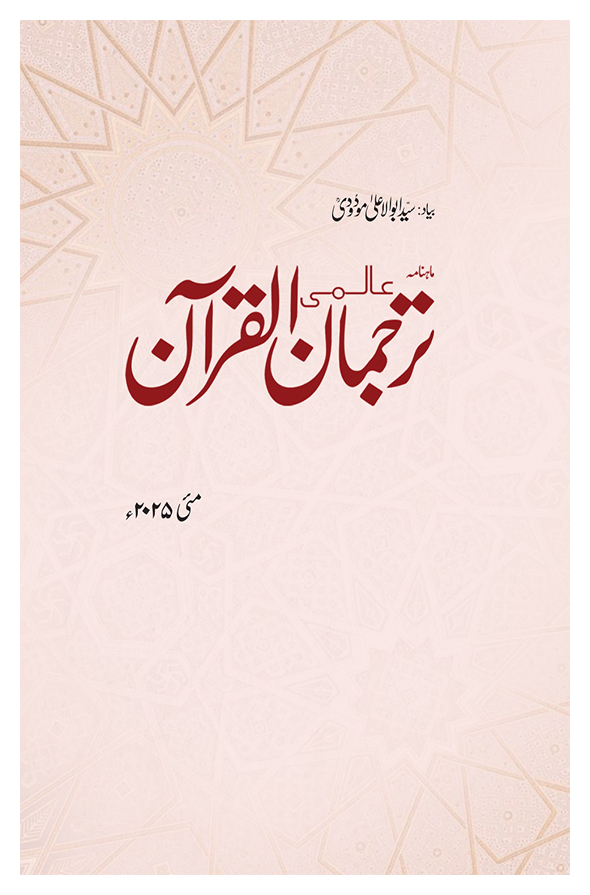
تاریخ کے آئینے میں ہر دور کی تصویر دیکھی جاسکتی ہے، اور یہ بھی امرواقعہ ہے کہ جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتیں، تاریخ انھیں سبق سکھا کر رہتی ہے۔ افسوس کہ تاریخ سے سبق کم ہی لیا جاتا ہے اور ہر دور میں متکبر حکمران وہی غلطیاں دہراتے چلے جاتے ہیں، جن کے سبب ان سے پہلے حکمران عبرت کا نشان بنے تھے۔ ہماری اپنی خودپسند قیادت کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔
مشرقی پاکستان میں جب آئینی اداروں کے کردار کو تسلیم کرنے سے انکار کے نتیجے میں بے چینی کا لاوا پک رہا تھا، تو اس وقت کے فوجی حکمران جنرل یحییٰ خان نے اعلان کیا تھا کہ ’’میں ہتھیاروں کی زبان استعمال کرکے سب کو سرنگوں کر لوں گا‘‘۔ جن اہلِ دانش نے اس کو مشورہ دیا کہ ہتھیاروں کی زبان نہیں، دلیل کا ہتھیار استعمال کرو تو اس نے اسے کمزوری اور بزدلی قرار دے کر مسترد کر دیا اور پھر اسی سال ۱۶ دسمبر کو قائداعظم ؒکے پاکستان کے دوٹکڑے ہوگئے۔
مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے سانحے سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ۱۹۷۳ء میں ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان کی منتخب حکومت برطرف کر کے فوجی حل کا تباہ کن راستہ اختیار کیا، اور ۱۹۷۳ء کے دستور کے مخلصانہ نفاذ سے جو برکتیں ملک و قوم کو حاصل ہوسکتی تھیں ان سے محروم کردیا۔ یہ آگ پیپلزپارٹی کے بعد وجود میں آنے والی ایک فوجی حکومت کے دور میں سرد پڑی اور تصادم کی وہ شکل ختم ہوئی جو قومی وجود کو تباہی کی طرف لے جارہی تھی۔
یہ افسوس کا مقام ہے کہ ۱۹۸۸ء کے بعد آنے والے نئے جمہوری اَدوار میں بھی نہ مرکزی قیادت نے اور نہ صوبے کی قیادت نے بلوچستان کے مسئلے کا صحیح حل تلاش کرنے کی کوئی منظم اور مؤثر کوشش کی، اور زیرزمین آگ پھر سُلگنے لگی، جسے جنرل پرویز مشرف کے فوجی حکمرانی کے دور نے ایک بار پھر بھڑکا کر دہکتا ہوا الائو بنادیا اور ۲۰۰۱ء کے بعد طاقت کی زبان استعمال کرنا شروع کی،جس کی شدت میں بہت اضافہ ہواہے۔ لاقانونیت کا دور دورہ ہے۔ لاپتا افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے اور مسخ شدہ لاشیں سامنے آرہی ہیں۔ نواب اکبر بگٹی جو بلوچستان کے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کرسکتے تھے، ان کو جس بے دردی اور رعونت کے ساتھ راستے سے ہٹایا گیا اور جس طرح انھیں سپردِ خاک کیا گیا، اس نے غم و غصے کا وہ سیلاب برپا کیا ہے، جس نے صوبے ہی نہیں ملک کے دروبست کو ہلا دیا ہے۔
سیاسی قیادت حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے مسئلے کا سیاسی حل نکالنا چاہتی تھی۔ پارلیمنٹ موجود رہی مگر اسے اس مسئلے پر بحث کرنے اور اس کا حل نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ماضی میں جائیں تو ایک پارلیمانی کمیٹی نے تین چار مہینے کی تگ و دو اور تمام متعلقہ عناصر سے کامیاب مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی کچھ واضح راہیں تلاش کیں، مگر اس کا کام بھی معرضِ خطر میںڈال دیا گیا اور اسے پرکاہ کی حیثیت نہ دی گئی___ مستقبل پر بات کرنے سے پہلے صحیح صورت حال، اصل مسائل اور ان کے حل کے نقشۂ راہ پر مختصر گفتگو ہوجائے تو پھر شاید سنگ ہائے راہ سے نجات کا راستہ بھی نکالا جا سکے۔
بلوچستان پاکستان کے رقبے کا ۴۵ فی صد اور آبادی کے تقریباً ۶ فی صد پر مشتمل ہے۔ تقریباً ۹۰۰ کلومیٹر کا ساحلی علاقہ اور ایران اور افغانستان سے سیکڑوں کلومیٹر کی مشترک سرحد ہے۔ تیل، گیس، کوئلے اور دوسری قیمتی معدنیات سے مالا مال ہونے کے باوجود اس وقت یہ ملک کا غریب ترین صوبہ ہے۔ بلوچ اور پشتون، آبادی کا تقریباً ۸۸ فی صد ہیں اور آپس میں برابر برابر ہیں، جب کہ باقی ۱۲ فی صد وہ آبادکار (settlers) ہیں، جو آہستہ آہستہ اس سرزمین کا حصہ بن چکے ہیں۔ ۲۰۲۳ء کی مردم شماری کے مطابق بلوچستان کی آبادی پاکستان کی کُل آبادی کا ۶ء۲ فی صد (ایک کروڑ ۴۸ لاکھ ۹۴ ہزار ۴سو) تھی۔ قبائلی نظام اب بھی مضبوط ہے اور اس کی روایات معاشرے میں راسخ ہیں۔
معاشی ڈھانچا نہ ہونے کے برابر ہے اور آبادی کے دُور دراز علاقوں تک پھیلے ہونے کی وجہ سے مواصلات اور سہولتوں کی فراہمی کا کام مشکل اور نسبتاً مہنگا ہے۔ جو سہولت دوسرے صوبوں میں مثال کے طور پر ایک کروڑ روپے کے خرچ سے میسر آسکتی ہے، صوبہ بلوچستان میں تین سے چار گنا زیادہ اخراجات درکار ہوتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وسائل کی فراہمی کا کام کبھی اس صوبے کے لیے انصاف اور ضروریات کی بنیاد پر نہ ہوسکا۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے دیہی علاقے میں غربت، پاکستان کی اوسط غربت سے تقریباً دگنی ہے۔
مرکزی اور صوبائی حکومتیں مسلسل دعویٰ کرتی آرہی ہیں کہ بلوچستان کے لیے کئی بڑے منصوبے (Mega Projects) اور تین ہزار سے زیادہ دوسرے ترقیاتی منصوبے زیرِتکمیل ہیں۔ اس مقصد کے لیے اربوں روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نہریں، سڑکیں اور ڈیم تعمیر کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں نفرت اور بے چینی کی لہریں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ گیس اور مواصلات کا نظام متاثر ہونے سے روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہورہا ہے اور اس میں انسانی جانوں کا ضیاع سب سے بڑا المیہ ہے جس کی کسی قیمت پر تلافی نہیں ہوسکتی۔
یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ محض چند سرداروں کی سرکشی اور شرارت ہے، جو اپنے ذاتی فائدے کی خاطر صوبے کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں؟ کیا اس میں بیرونی ہاتھ ہے اور بھارت کے اپنے عزائم ہیں کہ وہ گوادر بندرگاہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے؟ امریکا کی اپنی سوچ ہے اور بلوچستان میں چین کے عمل دخل پر وہ مضطرب ہے۔ گوادر ہو یا سینڈک، ہر جگہ امریکا، انڈیا اور بعض عرب ملکوں کو چینیوں کا کردار نظرآتا ہے۔ ان سب تصورات میں کچھ نہ کچھ صداقت بھی ہوسکتی ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ مخالف قوتیں حالات کو اسی وقت استعمال کر سکتی ہیں جب ان کے لیے حالات سازگار ہوں اور بگاڑ موجود ہو اور مسائل کو بروقت اور صحیح طریقے پر حل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ بس قوت کے ذریعے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔
یہ ۲۰۰۴ء کی بات ہے کہ مجھے بطور پارلیمنٹیرین، بلوچستان کے حالات کا زیادہ گہرائی سے مطالعہ کرنے اور صوبے کے چند مرکزی مقامات کا تفصیلی دورہ کرنے، اپنی آنکھوں سے حالات کا مشاہدہ کرنے اور بہت سے ذمہ دار افراد سے حقائق کو جاننے اور مسائل کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد جہاں مجھے یقین ہے کہ آج بھی تمام معاملات سیاسی عمل اور افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہوسکتے ہیں، وہیں میرا یہ احساس اور بھی پختہ ہوگیا ہے کہ کچھ برسرِاقتدار قوتیں مسائل کو حل کرنے میں واقعی کوئی دل چسپی نہیں رکھتیں بلکہ انھیں مزید الجھانے اور بگاڑنے کے درپے ہیں۔ اس کی نمایاں ترین مثال وہ پارلیمانی کمیٹی ہے جس کا اعلان اپنے مختصر دورِ وزارتِ عظمیٰ میں چودھری شجاعت حسین نے کیا تھا۔ یہ اس حیثیت سے ایک منفرد کمیٹی تھی کہ اس میں پارلیمنٹ کی تمام سیاسی جماعتیں شریک تھیں بشمول قوم پرست جماعتوں کے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس میں برسرِاقتدار جماعتیں اور اس کے حلیفوں کے نمائندے شامل تھے۔
اِس پارلیمانی کمیٹی نے مزید دو کمیٹیاں قائم کیں: ایک کمیٹی سینیٹر وسیم سجاد کی سربراہی میں، جس کا کام دستوری معاملات پر سفارشیں پیش کرنا تھا، اور دوسری کمیٹی سینیٹر مشاہد حسین سیّد کی سربراہی میں، جسے سیاسی اور معاشی معاملات پر سفارشات مرتب کرنا تھا۔ مجھے دوسری کمیٹی میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کمیٹی نے کھلے دل سے اور ملک کے مفاد میں اپنی پوری کارروائی آگے بڑھائی اور پارٹی وابستگیوں سے بالاتر ہوکر، ملک کے مفاد اور انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنی متفقہ سفارشات مرتب کیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ سفارشات پارلیمنٹ کے سامنے باضابطہ طور پر پیش کرنے میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں، ان پر عمل درآمد کی بات تو دُور کی چیز ہے۔ اس کے بعد سنگین واقعات رُونما ہوئے اور حالات مزید بگڑتے چلے گئے۔
ہماری نگاہ میں مسئلے کے حل کے لیے سب سے پہلے چند بنیادوں کا تعین اور چند حقائق کا فہم ضروری ہے:
۱- مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ مسئلہ سیاسی ہے اور اس کا حل بھی سیاسی ہی ہوسکتا ہے۔
۲- مسئلے کے حل کے لیے تمام متعلقہ عناصر کو افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اور کوشش کرنا ہوگی کہ مکمل اتفاق رائے اور بصورت دیگر اکثریت کے مشورے سے معاملات کو طے کیا جائے۔
۳- یہ اصول تسلیم کیا جانا چاہیے کہ محض ’مضبوط مرکز‘ کا فلسفہ غلط اور انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ ’مضبوط مرکز‘ اسی وقت ممکن ہے جب صوبے مکمل ہم آہنگی سے ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں۔ مرکز اور صوبوں میں تضاد و اختلاف کی جگہ مفاہمت اور ہم آہنگی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ قومی دستور کا بھی یہی تقاضا ہے، جسے پورا نہیں کیا گیا۔
۴- چوتھا بنیادی اصول یہ ہے کہ جس طرح زنجیر کی مضبوطی کا انحصار اس کی کمزور ترین کڑی پر ہوتا ہے، اسی طرح ملک کی مضبوطی کے لیے بھی ضروری ہے کہ کمزور اور غریب طبقے کو اتنا مضبوط کیا جائے اور اس سطح پر لایا جائے کہ سب برابری اور خوش حالی کے مقام پر آجائیں۔ دوسرے الفاظ میں سب انصاف کے حصول اور کمزور کو مضبوط بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں۔ انصاف نام ہی توازن اور برابری کا ہے اور یہی چیز آج تک ہماری معاشی منصوبہ بندی اور سیاسی پالیسی میں مفقود رہی ہے۔
۵- اس پورے عمل میں اصل اہمیت افراد، علاقے، صوبے اور پوری قوم کے حقوق کا تحفظ اور سیاسی اور معاشی عمل میں تمام عاملین کی بھرپور شرکت اور کارفرمائی کو حاصل ہے۔ فردِواحد کی حکومت یا محض کسی خاص گروہ اور مقتدر گروہ کے ہاتھوں میں قوت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا ارتکاز خرابی کی جڑ ہے۔ مسئلہ معاشی ہے مگر اس سے بھی زیادہ صوبوں کے اپنے وسائل پر اختیار اور سیاسی اور معاشی فیصلوں میں شرکت اور ترجیحات کے تعین کا ہے۔ منہ بند کرنے کے لیے کچھ گرانٹس یا مراعات کے دے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ملکیت، اختیار اور اقتدار اور فیصلوں میں شرکت کے انتظام کو ازسرِنو مرتب کرنا اصل ضرورت ہے۔ ترقی بلاشبہہ مطلوب ہے مگر اس انداز میںکہ رشتہ حاکم اور محکوم کا نہ ہو بلکہ سب کے فیصلے سے اور سب کی شراکت سے معاملات طے ہوں۔ وسائل پر اختیار بھی آزادی کا لازمی حصہ ہے۔
۶- اس سلسلے میں پاکستانی فوج کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف دفاعِ وطن کی ذمہ داری سول حکمرانی کے تحت انجام دے۔ ساری خرابیوں کی جڑ سیاسی اور اجتماعی معاملات میں فوج کی مداخلت اور اس کا ایک مقتدر سیاسی قوت بن جانا ہے۔ فوج کے سوچنے کا انداز (mind-set) سول نظام سے بہت مختلف ہے اور دونوں کا اپنے اپنے حدود میں رہ کر تعاون ہی ملک کے نظام کی صحت کی ضمانت ہوسکتا ہے۔ تحکمانہ انداز بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس سے خیر رُونما نہیں ہوسکتا۔
ان اصولوں کی روشنی میں یہ چند تجاویز پیش نظر رہنی چاہئیں:
بلوچستان ہی نہیں، تمام صوبوں اور ملک کے سب علاقوں اور متاثرہ افراد کے مسائل افہام و تفہیم سے حل ہوسکتے ہیں۔ یہ سب صرف اسی وقت ممکن ہے، جب اصل فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں، عوام کے مشورے سے ہوں۔ مکالمے کے ذریعے سیاسی معاملات کو طے کیا جائے۔ فوجی اور سول مقتدرہ کی گرفت کو مفادات کی سطح سے بلند ہوکر ختم کیا جائے، اور عوام اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جمہوری اداروں کے ذریعے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں۔
صوبائی قیادت کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ بلوچستان کی صوبائی قیادتیں بھی حالات کے بگاڑ کے سلسلے میں ایک حد تک ذمہ دار رہی ہیں لیکن زیادہ ذمہ داری مرکزی قیادت اور خصوصیت سے حکمران طبقے پر عائد ہوتی ہے۔
اسی طرح ہم یہ انتباہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ظلم و زیادتی کا معاملہ یک طرفہ نہیں ہے۔ نسل پرستی کا پرچم اُٹھانے والوں نے جس طرح ملک عزیز کے دوسرے حصوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں پر زندگی تنگ کی ہے اور شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کر ان کو قتل کیا ہے۔ ان کا یہ فعل اخلاقی، تہذیبی اور انسانی حوالوں سے ایک قبیح اور شرمناک حرکت ہے، اور اس ضمن میں جعفرایکسپریس کا واقعہ اندوہ ناک ہے۔
بالکل اسی طرح ریاست کے ذمہ دار مسلح اداروں کی جانب سے بلاجواز کسی سول آبادی کو نشانہ بنانا بھی قانونی اور اخلاقی درجے میں بدترین فعل ہے، جس کی قیمت پورے ملک کو ادا کرنے کے لیے نقصان اُٹھانا پڑتا ہے۔ پورے پاکستان کا دامن بلوچ ہم وطنوں کے لیے کھلی بانہوں کے ساتھ کشادہ رو ہے، مگر گذشتہ برسوں کے دوران علاقائی و نسلی بنیاد پر قتل کرنے کا یہ کلچر بدترین فسطائیت بن گیا ہے اور جو اس انڈین ڈیزائن کا حصہ ہے، جس کے تحت ۱۹۷۱ء میں مشرقی پاکستان میں غیربنگالی سول آبادی کا قتل عام کیا گیا تھا اور پھر ۱۹۸۵ء کے بعد کراچی و حیدرآباد میں مخصوص نسل پرستی کی آگ بھڑکائی گئی تھی۔
بلوچستان کی سیاسی و معاشی ناہمواری اپنی جگہ بڑی تلخ حقیقت ہے ، جس کی ذمہ داری ایک طرف مرکزی و صوبائی حکومت پر آتی ہے تو دوسری جانب خود بلوچستان کے مقتدرطبقوں اور نوابوں کی ایک نسل کو اس ظلم سے بری الذمہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مگر اس میں اہم بات یہ ہے کہ مبالغہ آمیز پروپیگنڈے کے ساتھ نفرت کی آگ بھڑکانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوسکتا۔ جھوٹ کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہوتی۔
مشرقی پاکستان میں جھوٹے اعداد و شمار کی آگ بھڑکا کر نہ صرف ملک توڑا گیا، بلکہ انڈیا کی غلامی کا طوق بھی پہن لیا گیا جس سے نکلنے کی آج تک کوششیں جاری ہیں۔ آج خود بنگلہ دیش میں تسلیم کیا جارہا ہے کہ ’’اگر تلہ سازش کیس سچا تھا اور مغربی پاکستان کے خلاف معاشی ہمواری کا پروپیگنڈا جھوٹا تھا‘‘۔ ہم سوشل میڈیا پر متحرک دشمن ملک اور دشمن کے ہاتھوں آلہ کار بننے والوں کے صریح جھوٹ پھیلانے کے عمل کو ایک گھنائونا کھیل تصور کرتے ہیں۔ افسوس کہ لوگ نادانی میں ایسی جھوٹی اور مبالغہ آمیز پوسٹیں آگے پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں خاص طور پر نسلِ نو کو احتیاط برتنی چاہیے کہ آخرکار اس کا نقصان اسی درخت کو پہنچے گا، جس پر ان کا آشیانہ ہے۔
۸فروری ۲۰۱۲ء کو امریکی کانگریس کیSurveillance and Oversight کمیٹی نے بلوچستان کے مسئلے پر باقاعدہ ایک نشست منعقد کی ہے، اور ۱۷فروری ۲۰۱۲ء کو اس کمیٹی کی سربراہ ڈینا روہربافر نے کانگریس میں ایک مسودۂ قانون اپنے دو مزید ساتھیوں کے ساتھ جمع کرا دیا جس میں بلوچستان کے پاکستان سے الگ ملک بنائے جانے اور علیحدگی پسند بلوچوں کی جدوجہد کی تائید اور سرپرستی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ یہ شرانگیز اقدام امریکی سیاسی قوتوں کی طرف سے اس نوعیت کی کوئی پہلی کوشش نہیں ہے۔ امریکا ایک طرف تو پاکستان سے تعاون کے مطالبے کرتا ہے اور دوسری طرف پاکستان کی آزادی، حاکمیت، خودمختاری اور استحکام پر بے دریغ حملے کرتا ہے۔ اس کی زمین اور فضائی حدود کو پامال کرتا ہے اور ملک میں تخریب کاری کی نہ صرف سرپرستی کرتا ہے، بلکہ سی آئی اے کے امریکی کارندوں اور پاکستان سے بھرتی کیے گئے کرائے کے گماشتوں (Mercenaries)کو بے دریغ استعمال کرتا ہے۔ بھارت بہت پہلے سے اس قسم کی مذموم حرکتوں کی پشتی بانی کرتا رہا ہے اور اب امریکی بھارتی اسٹرے ٹیجک پارٹنرشپ کا یہ مشترک ہدف ہے۔
امریکا اس وقت پاکستان کے خلاف تین B کی حکمت عملی پر گامزن ہے: Bribe (رشوت)، Blackmail (کمزوری سے فائدہ اُٹھانا) اور Bullet (گولی) کا استعمال ۔ وقتاً فوقتاً امریکی تھنک ٹینکوں کی رپورٹوں اور امریکی کانگریس کی کارروائیوں کی شکل میں معاملہ زیادہ ہی گمبھیر ہوتا جارہا ہے۔ افسوس ہے کہ ہماری سیاسی اور فوجی قیادت اب بھی امریکا کے اصل کھیل کو سمجھنے اور اس کے مقابلے کے لیے جان دار حکمت عملی بنانے سے قاصر ہے۔ان حالات میں قوم کے لیے اس کے سوا کوئی اور عزّت اور آزادی کا راستہ باقی نہیں رہا ہے کہ ایسی قیادت سے نجات پائے اور ایسی قیادت کو برسرِاقتدار لائے جو پاکستان کی آزادی، حاکمیت، استحکام اور مفادات کی بھرپور انداز میں حفاظت کرسکے۔
بلوچستان کے مسئلے کے دو اہم پہلو ہیں اور دونوں ہی بے حد اہم اور فوری اقدام کا مطالبہ کرتے ہیں:
امریکا جو کھیل کھیل رہا ہے وہ نیا نہیں۔ اس کا ہدف پاکستان کی آزادی، اس کا نظریاتی تشخص اور اس کی ایٹمی صلاحیت پر ضرب لگانا ہے اور اب ایک عرصے سے اس ہمہ گیر حکمت عملی کے ایک پہلو کی حیثیت سے بلوچستان کارڈ استعمال کیا جارہا ہے۔ ہنری کسنجر سے لے کر حالیہ قیادت تک سب کے سامنے ایک مرکزی ہدف مقامی چہروں کے ذریعے اُمت مسلمہ کی تقسیم در تقسیم اور اس کے وسائل پر بلاواسطہ یا بالواسطہ قبضہ ہے۔ اس پالیسی کا پہلا ہدف مقامی قومیتوں کے ہتھیار کے ذریعے دولت عثمانیہ کا شیرازہ منتشر کرنا تھا۔ پھر افریقہ کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ کر غیرمؤثر کردیا گیا۔ ’بالفور ڈیکلریشن‘ کے سہارے عالمِ عرب بلکہ عالم اسلام کے قلب میں اسرائیل کا خنجر گھونپنا بھی کچھ دوسرے مقاصد کے ساتھ ساتھ اسی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ پاکستان کو ۱۹۷۱ء میں دولخت کرنا، سوڈان اور انڈونیشیا کے اعضا کو کاٹ کر اپنی باج گزار ریاستیں وجود میں لانا، عراق اور افغانستان میں زبان، نسل اور مسلک کی بنیاد پر ان ممالک کی سرحدوں کو بدلنے کی کوشش کرنا، کرد قومیت کو عراق، شام اور ترکیہ کے علاقوں میں ہوا دینا ۔ پھر عراق، ایران، شام، لیبیا ، یمن اور ترکیہ میں دہشت گردی اور خون خرابے کی آگ بھڑکانا، یہ سب اسی حکمت عملی کے مختلف پہلو ہیں۔
پاکستان کی مغربی سرحد پہ خونیں کارروائیاں ہوں، یا مقبوضہ جموں و کشمیر میں برہمنی سامراجیت کی یلغار، یہ وارداتیں بھی اسی صہیونی اور صلیبی جنگ کے شاخسانے ہیں۔ ذرا پیچھے جائیں تو یہ ۲۰۰۶ء کی بات ہے رالف پیٹرز نے Armed Forces Journal US میں Blood Borders (خونیں سرحدیں) کے عنوان سے ایک شرانگیزمضمون لکھا تھا، جس میں پاکستان کی تقسیم اور تبدیل کی جانے والی سرحدوں کا نقشہ چھاپا تھا۔ اس میں آزاد بلوچستان کو ایک الگ ملک کی حیثیت سے دکھایا گیا تھا۔ بھارت اور امریکا دونوں اپنے اپنے انداز میں پاکستان میں تخریب کاری کے ساتھ علیحدگی کی تحریکوں کی سرپرستی کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندرونی حالات کو خراب کرنے کی کوششیں تیز تر ہوگئی ہیں۔ نیز امریکا اور انڈیا دونوں کی نگاہ میں پاکستان اور چین کا قریبی تعلق اور خصوصیت سے بلوچستان میں ’سی پیک‘ کا راستہ روکنے اور پاکستان ایران گیس پائپ لائن اور بجلی کی فراہمی میں تعاون کو مؤخر و ملتوی اور معاملے کو خراب کرنا ہے۔
امریکا کے ان جارحانہ عزائم کو سمجھنا اور ان کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنا دفاعِ پاکستان کا اہم ترین پہلو ہے۔ اس کے لیے ’امریکا کی دہشت گردی کے خلاف جنگ‘ سے نکلنا اور علاقے کے ممالک کے تعاون سے فیصلہ کن جدوجہد کرنا وقت کی اصل ضرورت ہے۔ اس کے لیے قوم کو بیدار اور متحرک کرنا ازبس ضروری ہے۔
مسئلے کا دوسرا پہلو بلوچستان کے حالات اور ان کی اصلاح ہے۔ بیرونی ہاتھ اپنا کام کر رہا ہے مگر اسے یہ کھیل کھیلنے کا موقع ہماری اپنی سنگین غلطیاں اور حالات کو بروقت قابو میں نہ لانے بلکہ مزید بگاڑنے والی پالیسیاں ہیں۔
ہمیں بڑے دُکھ سے یہ حقیقت بیان کرنا پڑ رہی ہے کہ بلوچستان اپنی تمام اسٹرے ٹیجک اہمیت اور معدنی اور مادی وسائل سے مالامال ہونے کے باوجود ملک کا پس ماندہ ترین صوبہ ہے اور معاشی اور سیاسی اعتبار سے بنیادی ڈھانچے سے محروم ہے۔
جب تک یہ مسئلہ اپنے تمام سیاسی، سماجی اور معاشی پہلوئوں کے ساتھ حل نہیں ہوتا، بیرونی قوتوں کے کردار پر بھی قابو نہیں پایا جاسکتا۔ اصل مسئلہ سیاسی، معاشی اور اخلاقی ہے۔ حقیقی شکایات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ فوجی آپریشن کسی بھی نام یا کسی بھی عنوان سے ہو، وہ مسائل کا حل نہیں۔ حل کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اس مسئلے سے متاثر تمام طبقات کو افہام و تفہیم اور حق و انصاف کی بنیاد پر مل جل کر حالات کی اصلاح کے لیے مجتمع اور متحرک کرنا ہے۔
مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اعتماد کا فقدان بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے اعتماد کی بحالی ہی پہلا قدم ہوسکتا ہے جس کے لیے فوجی آپریشن کا خاتمہ، عام معافی، تمام گرفتار شدہ اور لاپتا افراد کی بازیابی، اور بہتر فضا میں تمام سیاسی اور دینی قوتوں کی شرکت سے معاملات کو سنبھالنا ہے۔بیرونی قوتوں کا کھیل بھی اسی وقت ناکام بنایا جاسکتا ہے، جب ہم اپنے معاملات کی اصلاح کریں اور جو حقیقی شکایات اور محرومیاں ہیں ان کی تلافی کا سامان کریں۔اصل چیز اعتماد کی بحالی، سیاسی عمل کو شروع کرنا اور تمام قوتوں کو اس عمل کا حصہ بنانا ہے۔ عوام ہی کو حقیقی طور پر بااختیار بنانے سے نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ بہت وقت ضائع ہوچکا ہے۔ ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم ہی کو اسے بچانا اور اس کی تعمیرنو کی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہے۔ بلوچستان کا پاکستان سے باہر کوئی مستقبل نہیں ہے اور نہ پاکستان کا بلوچستان کے بغیر وجود ممکن ہے۔ سیاسی اور عسکری دونوں قیادتوں کا امتحان ہے۔ اس لیے کہ ؎
یہ گھڑی محشر کی ہے ، تو عرصۂ محشر میں ہے
پیش کر غافل ، عمل کوئی اگر دفتر میں ہے
انفرادی مزاج، ذاتی ضروریات، نظریاتی اختلافات، گروہی وابستگیوں اور قومی عصبیتوں کے باعث سماجی تعلقات اتنے تہہ در تہہ اور پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک فرد دوسرے فرد سے اور ایک گروہ دوسرے گروہ سے کسی سطح پر کٹا ہوا ہوتا ہے، تو اسی لمحے کسی سطح پر دوسرے افراد اور اقوام سے جڑے ہونا اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ ایک داعی ہو یا سیاسی کارکن، اگر وہ سماجی تعلقات کی ان پیچیدگیوں کا فہم نہیں رکھتا تو وہ اجتماعیت سے کٹ کر رہ جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنے پیغام اور کام کے لیے معاشرے میں خود ہی گنجائش (space) کم کرتا چلا جاتاہے۔ ایک داعی کے لیے تہہ در تہہ تعلقات سے دعوت کے لیے حمایت اور فوائد اخذ کرنے کی صلاحیت اَزحد ضروری ہے۔
سیرتِ نبویؐ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپؐ نے بدتر سے بدتر حالات اور دشمنوں کے نرغے میں بھی اپنے مقاصد کے لیے حمایت و تائید حاصل کی۔ کسی بھی اصولی و نظریاتی گروہ کے لیے یہ اُمید کا پہلو ہے کہ مخالفین میں بھی ہر آدمی ایک ہی طرح کا مخالف نہیں ہوتا۔ ان میں بھی دُور اندیش، معتدل طبیعت اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جو محض جذباتیت اور اندھی عصبیت کا شکار نہیں ہوتے۔ اس ضمن میں سیرتِ رسولؐ سے کچھ واقعات پیش ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پھوپھیوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھ پر یہ حکم نازل فرمایا ہے: وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ۲۱۴ (الشعراء ۲۶:۲۱۴)’’اور آپؐ اپنے قریبی عزیزوں کو ڈرایئے‘‘، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے ربّ کے اس حکم کی تعمیل کیسے کروں؟ آپؐ کی پھوپھی حضرت صفیہؓ نے کہا: ’’تو اس میں دیر کس بات کی۔ عبدالمطلب کی ساری اولاد کو بلائیں اور ان کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ البتہ اپنے چچا ابولہب کو نہ بلائیں، وہ تمھاری کوئی بات نہ مانے گا‘‘۔
اگلے دن آپؐ نے بنوہاشم کو کھانے پر بلایا اور اپنی پھوپھی کی رائے کے برخلاف ابولہب کو بھی بلایا۔ خاندان بنوہاشم کے چالیس افراد آئے اور ابولہب نے اس محفل کا ماحول خراب کرنے اور آپؐ کی دعوت سے بنوہاشم کو بدظن کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور بعد کی زندگی میں بھی بنوہاشم کا یہ واحد شخص تھا جس نے آپؐ کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔(الکامل ابن اثیر بحوالہ الرحیق المحتوم، ص ۱۱۲-۱۱۳)
حضرت صفیہؓ کی رائے درست ہونے کے باوجود اسے کھانے پر بلانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ نہ صرف آپؐ کا حقیقی چچا تھا بلکہ آپؐ کا قریب ترین ہمسایہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپؐ کا سمدھی بھی تھا۔ آپؐ کی دو بیٹیاں حضرت رقیہؓ اور حضرت اُمِ کلثومؓ ابولہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں، اگرچہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب آپؐ خاندان کے دیگر افراد کو دعوت دے رہے تھے تو اسے کیسے نظرانداز کرسکتے تھے؟ اس طرح تو اسے بھتیجے کی مخالفت کا ایک اخلاقی جواز مل جاتا کہ جب محمدؐ بن عبداللہ نے مجھے سارے خاندان میں حقیر سمجھا ہے تو میں بھی اس کی تحقیر کروں گا۔
اب اسی شخص کی خاندانی عصبیت ایک موقع پر مسلمانوں کے کام آگئی۔ واقعہ یہ ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ کے بعد جب ایک غلط فہمی کے باعث بعض مسلمان حبشہ سے واپس آگئے تو وہ مکہ میں کسی نہ کسی کی ’امان‘ حاصل کرکے رہنے لگے۔ ان میں قریش کے خاندانِ بنی مخزوم کے ابوسلمہؓ اور ان کی بیوی بھی تھے۔ ان کو ان کے ماموں حضرت ابوطالب نے پناہ دے دی۔بنومخزوم کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے باغی نوجوان کو کوئی اور پناہ دے۔ وہ اپنے سردار ابوجہل کے ہمراہ حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور انھوں نے کہا: ’’تم نے ہمارے خاندان کے آدمی کو کیوں پناہ دی ہے؟‘‘
حضرت ابوطالب نے کہا: ’’ابوسلمہ میرا بھانجا ہے ۔ اگر میں اپنے بھتیجے محمدؐ کو پناہ دے سکتا ہوں تو بھانجے کو کیوں نہیں دے سکتا؟‘‘
اس پر ابوجہل اور حضرت ابوطالب کے درمیان تکرار بڑھ گئی۔ ابولہب نے جب دیکھا کہ بنومخزوم اس کے بھائی ابوطالب سے لڑنا چاہتے ہیں تو اس کی خاندانی عصبیت نے جوش مارا۔اس نے کہا:
’’اے بنومخزوم! تم ابوطالب پر دبائو ڈالتے جارہے ہو۔ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو خدا کی قسم! میں ان کی حمایت میں سینہ سپر ہوجائوں گا‘‘۔
ابولہب کے یہ تیور دیکھ کر بنومخزوم اسے کہنے لگے:’’اے ابوعتبہ! ہم تمھیں ناراض نہیں کرنا چاہتے‘‘، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ (ضیاء النبی، ۲ /۲۵۸)
خاندان بنوہاشم کی پہلی دعوت میں جب ابولہب نے بنوہاشم کو حضوؐر کی دعوت کے خطرات سے ڈرایا کہ ہم تمام قریش اور عرب کا مقابلہ نہیں کرسکتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ خاندان ابھی سے محمدؐبن عبداللہ کو اس کام سے روک دے تو حضرت ابوطالب نے معاملے کو سنبھالتے ہوئے کہا:
’’اے بھتیجے! تمھیں شاید اندازہ نہیں کہ ہمیں تمھاری نصیحت کس قدر پسند ہے اور ہم تمھاری بات کو کس قدر سچی جانتے ہیں۔ یہ تمھارا گھرانہ جمع ہے اور میں بھی اسی خاندان کا ایک فرد ہوں۔ اگرچہ میری طبیعت عبدالمطلب کا آبائی دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے لیکن تمھیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے، اسے تم انجام دیتے رہو۔ اللہ کی قسم! جب تک میرے جسم میں جان ہے، تمھاری حفاظت سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا‘‘۔ (ابن اثیر: الکامل، بحوالہ الرحیق المختوم، ص ۱۱۳، ضیاء النبی، ۲/ ۲۷۰)
جب قریش کے لیے دعوت کا پھیلائو ناقابلِ برداشت ہوگیا تو بنوہاشم کے سردار حضرت ابوطالب کو پیغمبرؐ اسلام کی حمایت سے روکنے کے لیے معززین قریش کا ایک وفد لے کر ان کے گھر پہنچ گئے اور مطالبہ کیا کہ یا تو اپنے بھتیجے کو قوم کے معبودوں میں عیب چھانٹنے اور ہمارے آبائواجداد کو گمراہ کہنے سے روک دیں یا درمیان سے ہٹ جائیں، تاکہ ہم اس سے خود نمٹ لیں۔ سردارانِ قریش باہمی خانہ جنگی سے بچنے کے لیے حضرت ابوطالب پر دبائو ڈال رہے تھے۔ انھوں نے بڑا نرم اور رازدارانہ لہجہ اختیار کرکے انھیں خوب صورتی سے ٹال دیا۔(سیرۃ ابن ہشام بحوالہ ضیاء النبی، ۲/ ۲۷۰، الرحیق المختوم، ص ۱۱۶)
کچھ عرصے بعد ان کا دوسرا وفد آگیا اور یہ دھمکی دے کر چلا گیا کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روکیں گے تو ہماری آپ سے لڑائی ہوگی۔ بنوہاشم کی تعداد اتنی نہ تھی کہ پورے قبیلہ قریش سے ٹکر لے سکے۔ اس لیے حضرت ابوطالب نے چاہا کہ بھتیجے کو اس بات سے آگاہ کریں۔ انھوں نے پیغمبرؐ اسلام سے کہا:
’’بھتیجے! مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کا سہارنا میرے بس میں نہ ہو‘‘۔ لیکن جب بھتیجے نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لاکر رکھ دیں تو بھی میں اس دعوت سے باز نہ آئوں گا تو حضرت ابوطالب نے کہا:
’’بھتیجے جائو اور وہ بات کہتے رہو جو تمھیں پسند ہے۔ میں تمھیں کبھی دشمن کے رحم و کرم پر نہ چھوڑوں گا‘‘۔ (سیرۃ ابن ہشام ۱/ ۳۷۸، سیرۃ ابن کثیر۱/ ۲۷۴ بحوالہ ضیاء النبیؐ، ۲/ ۲۷۶)
تیسری مرتبہ قریشی وفد نے حضرت ابوطالب سے یہ سودے بازی کرنا چاہی۔ انھوں نے حضرت ابوطالب سے کہا:
’’ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو اپنا فرزند بنا کر رکھ لیں تاکہ وہ تمھارا دست و بازو بنے اور محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے حوالے کر دیں‘‘۔ اس پر حضرت ابوطالب نے کہا: ’’واللہ! تم میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر رہے۔ مجھے اپنا بیٹا دے رہے ہو کہ میں اسے پالوں، پوسوں اور موٹا تازہ کروں اور تم میرے بیٹے کو لے جا کر تلوار کے نیچے سے گزار دو۔ اللہ کی قسم! ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا‘‘۔(الرحیق المختوم، ص ۱۴۰)
بھتیجے کی حفاظت کے لیے حضرت ابوطالب اس قدر فکر مند رہتے کہ رات کو بھتیجے کے لیے ایک جگہ بستر لگواتے اور جب سب سو جاتے تو بھتیجے کو کسی اور بستر پر لٹا دیتے اور ان کے بستر پر اپنے بیٹوں میں سے کسی کو سلا دیتے۔وہ بھتیجے کی جان کے لیے اپنے بیٹوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار تھے۔ ( سیرۃ ابن کثیر۲/ ۴۴ بحوالہ ضیاء النبیؐ، ۲/ ۳۸۳)
جب قریش حضرت ابوطالب سے مایوس ہوگئے تو انھوں نے نہ صرف قریش بلکہ اپنے حلیف بنوکنانہ کے ساتھ مل کر بنوہاشم کے معاشرتی و معاشی مقاطعے (بائیکاٹ) کا فیصلہ کیا تو اس میں بھی حضرت ابوطالب اور بنوہاشم کی آپ کو پشت پناہی حاصل رہی حالانکہ اس وقت تک حضرت ابوطالب اور بنوہاشم کی ۱۰فی صد تعداد بھی مسلمان نہ ہوئی تھی۔
ابولہب کے بنوہاشم کا سردار بننے کے باعث خاندان کی وہ سرگرم حمایت تو حضوؐر کو حاصل نہ رہی لیکن آپؐ کے ایک چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب جو کہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے لیکن درپردہ آپؐ کے حمایتی رہے۔ جب ۱۳نبوی میں آپؐ نے رات کی تاریکی میں اہل مدینہ سے بیعت عقبہ ثانیہ لی تو اس وقت حضرت عباسؓ آپؐ کے ساتھ تھے۔ انھوں نے اہل مدینہ کو مخاطب کر کے کہا:
’’خزرج کے لوگو! ہمارے اندر محمدؐ کی جو حیثیت ہے تمھیں معلوم ہے۔ اپنے قبیلہ قریش کے ساتھ ہم عقیدہ ہونے کے باوجود ہم نے قریش کے مقابلے میں ان کا دفاع کیا ہے۔ اب وہ تمھارے ہاں منتقل ہونے کے بارے میں یکسو ہیں۔ اگر تم ان کے دشمنوں سے ان کا دفاع کرلو گے، تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم بعد میں ان کو بے یارومددگار چھوڑ دو تو بہتر ہے کہ اس پیش کش سے آج ہی دستبردار ہوجائو، کیونکہ وہ اپنے شہر میں اپنے خاندان کے تحفظ میں تو ہیں‘‘۔(سیرۃ ابن ہشام ۱/ ۴۴۱-۴۴۲، بحوالہ الرحیق المختوم ، ص۲۱۱-۲۱۲)
مطعم بن عدی جو کہ حضورؐ کے دادا ہاشم کے ایک بھائی نوفل کا پوتا تھا، آخر دم تک کفر پر قائم رہا اور جنگ ِ بدر میں قتل ہوا۔ بعثت ِ نبویؐ کے پانچویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنوہاشم کے معاشرتی مقاطعہ (بائیکاٹ) کا باہمی طور پر معاہدہ کیا جس کی رُو سے قریش کی دوسری شاخوں کا بنوہاشم سے میل جول اور لین دین ممنوع ہوگیا۔ حضوؐر کی حفاظت اور دفاع کے لیے بنوہاشم شعب ابی طالب میں محصور ہوگئے۔ قریش کے سخت پہرے کے باعث باہر سے کوئی چیز بھی وہاں نہیں پہنچ پاتی تھی۔ قریش کی سنگدلی کے اس زمانہ میں چند نرم دل کافر چوری چھپے غلّہ و اناج پہنچاتے رہے۔ بالآخر تین سال بعد قریش ہی کے بعض منصف مزاج لوگوں نے ابوجہل کے اس فیصلہ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور اس ظالمانہ معاہدے کو چاک کیا۔ ان پانچ چھ افراد میں مطعم بن عدی بھی شامل تھا۔ (سیرۃ ابن ہشام، ص۳۲۵ ، الرحیق المختوم،ص ۱۶۰)
حضرت ابوطالب کی وفات کے بعد ابولہب بنوہاشم کا سردار بنا تو اس نے آپؐ کو خاندانِ بنوہاشم سے ’طرد‘ (کنبہ بدر) کردیا۔ قریش کے تمام خاندان تو آپؐ کے مخالف تھے ہی اب خاندان بنوہاشم بھی آپ ؐ کی حمایت سے دست کش ہوگیا تو اب کوئی بھی آپؐ پر ہاتھ اُٹھاتا یا قتل کردیتا تو کسی کو آپؐ کے خاندان سے لڑائی کا کوئی خطرہ نہ رہا۔ ان خونخوار حالات میں آپ دیگر قبائل کی حمایت کے لیے سفرطائف پر روانہ ہوئے۔ راستے کے قبائل نے بھی آپؐ کی بات قبول نہ کی اور طائف کے سرداروں نے تو اُلٹا آپؐ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا جنھوں نے سنگ باری کر کے آپؐ کو لہولہان کردیا۔ حالات کی خونخواری اتنی بڑھ گئی تھی کہ جب آپؐ مکہ کے قریب پہنچے تو آپؐ کے رفیقِ سفر حضرت زیدؓبن حارثہ نے کہا:
’’یارسولؐ اللہ! آپؐ کس طرح مکہ میں داخل ہوں گے، جب کہ وہاں کے لوگ تو آپؐ کے خون کے پیاسے ہوچکے ہیں؟ حضرت زیدؓ کو خدشہ تھا کہ اہل طائف کی بدسلوکی کے بعد تو اہل مکہ کی جسارتیں اور بڑھ جائیں گی۔جب آپؐ حرا کے مقام پر پہنچے تو آپؐ نے بنوخزاعہ کے ایک صحرائی گائیڈ عبداللہ بن اریقط کو کہا:
’’اخنس بن شریق ثقفی کے پاس جائو اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ مجھے اپنی جوار (پناہ) میں لے سکتاہے تاکہ میں لوگوں تک ان کے ربّ کا پیغام پہنچا سکوں؟ حقِ جوار یا امان لینا عرب کی روایت تھی۔ جوار دینے والا قبیلہ اسے اپنی عزّت سمجھتا تھا اور پناہ میں آنے والے کی حفاظت کو اپنی عزّت کی حفاظت تصوّر کرتا تھا۔
جب اخنس کی معذرت آگئی تو آپؐ نے عبداللہ کو اسی پیغام کے ساتھ سہیل بن عمر کی طرف بھیجا۔ اس کی معذرت آئی تو آپؐ نے عبداللہ کو مطعم بن عدی کی طرف بھیجا۔ مطعم نے پیغام سن کر کہا: ’’اگر محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) مجھ سے حقِ جوار چاہتے ہیں تو میں انھیں اپنے جوار (پناہ) میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ تم انھیں کہو کہ وہ حرم میں آجائیں‘‘۔ اب اس نے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو حکم دیا: ’’تم سب مسلح ہوکر حرم کے گوشوں پر کھڑے ہو جائو کیونکہ میں نے محمدؐ بن عبداللہ کو حقِ جوار دے دیا ہے‘‘۔
پیغام ملنے کے بعد حضوؐر حضرت زیدؓ بن حارثہ کے ہمراہ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حرم کے چاروں کونوں پر مطعم کے بیٹے گلے میں تلواریں حمائل کیے اور خود مطعم اپنے باقی افراد کے ساتھ مطاف میں اُونٹنی پر سوار کھڑا تھا۔ اس نے بآوازِ بلند اعلان کیا:
’’یامعشرالقریش! میں نے محمدؐ کو پناہ دی ہے، لہٰذا کوئی ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے‘‘۔
حضورؐ نے طو افِ کعبہ کیا اور گھر چلے گئے۔ ابوجہل اس ساری صورتِ حال پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ تو خیال کیے بیٹھا تھا کہ اب تو محمدؐ بن عبداللہ کے خاتمے کی راہ صاف ہوگئی ہے لیکن مطعم بن عدی کی پناہ نے اس کا سارا منصوبہ تہس نہس کردیا۔عرب روایت کے مطابق کسی کی جوار ملنے کے بعد اس سے لڑائی گویا جوار دینے والے سے لڑائی بن جاتی تھی۔ ابوجہل مطعم کے پاس آیا اور اُس سے پوچھا: ’’اے مطعم! اسے پناہ دی ہے یا اس کی اطاعت قبول کرلی ہے؟‘‘
’’میں نے اسے پناہ دی ہے‘‘۔ یہ جواب سن کر ابوجہل نے کہا: ’’تو پھر کوئی ڈر والی بات نہیں، جسے تُو نے پناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی‘‘۔ ( سیرۃ ابن ہشام۱/ ۴۱۹ بحوالہ الرحیق المختوم ، ص ۱۸۵-۱۸۷)
اب یہی مطعم بن عدی ہے کہ جب حضوؐر نے حرم میں بیٹھے لوگوں کو بتایا کہ میں آج رات بیت المقدس گیا اور واپس بھی آگیا ہوں تو مطعم بن عدی بول اُٹھا: ’’اے محمدؐ! آج جو بات آپؐ نے کہی ہے اس نے تو ہمیں ہلا کر ہی رکھ دیا ہے۔ ہم یہ کیسے مان لیں کہ جس مسافت کے طے کرنے میں ہمیں جاتے ہوئے ایک مہینہ، واپس آتے ہوئے ایک مہینہ لگتاہے، تم نے اسے رات کے قلیل حصے میں طے کرلیا۔لات و عزیٰ کی قسم! ہم آپؐ کی یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں‘‘۔
مطعم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے کہا: ’’اے مطعم!تم نے اپنے بھتیجے کے ساتھ جو گفتگو کی، وہ اَزخود ناپسندیدہ ہے۔ تو نے اُس شخص کو جھٹلایا، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا‘‘۔ (شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب، مختصر سیرۃ الرسولؐ، ص ۲۵۹، ضیاء النبیؐ، ۲/ ۴۸۴)
قریش کا ایک سردار عتبہ بن ربیعہ اسلام کے اتنا مخالف تھا کہ ایک بار جب حضرت ابوبکرؓ صحنِ حرم میں دعوتِ توحید دینے لگے تو قریش نے ان پر حملہ کردیا، حتیٰ کہ ابوبکر گرپڑے۔ اس دوران عتبہ بن ربیعہ نے اپنا جوتا نکال کر حضرت ابوبکرؓ کے چہرے پر جوتے سے پے درپے ضربیں لگائیں۔ ان کے پیٹ پر چڑھ کر کر کُودتا رہا۔ بعد میں جب رسولؐ اللہ نے ان کا حال پوچھا تو حضرت ابوبکر ؓ نے عرض کیا: یارسولؐ اللہ! مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے جوتوں کی ان ضربوں کے جو عتبہ بن ربیعہ نے میرے چہرے پر لگائی تھیں۔( سیرۃ ابن کثیر۱/ ۴۴۱ بحوالہ ضیاء النبیؐ، ۲/ ۲۴۰)
اسلام کی مخالفت میں جنگ بدر میں آیا تو سب سے پہلے یہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ آگے آیا اور مسلمانوں سے مبارز طلبی کی اور ابتدائے جنگ میں حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ( سیرۃ ابن کثیر۲/ ۴۱۳ ، الرحیق المختوم ،ص ۲۹۵)
البتہ وادیٔ طائف میں جب ہجوم نے پیغمبر ؐ اسلام کو لہولہان کردیا تو ان کی سنگ باری سے بچنے کے لیے آپؐ عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں داخل ہوئے اور دیوار سے ٹیک لگا کر سستانے لگے تو قریش کی روایتی وضع داری کے مطابق عتبہ نے اپنے غلام عداس کے ذریعے حضورؐ کی انگوروں سے تواضع کرائی۔ ( سیرۃ ابن کثیر۲/ ۱۵۳ ، الرحیق المختوم ،ص ۱۸۳)
جنگ ِ بدر کی صبح حکیم بن حزام اور عتبہ بن ربیعہ نے ابوجہل کو اس جنگ سے روکنے کی آخری حد تک کوشش کی۔ جنگ سے کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر سردار عمرو بن حضرمی قتل ہوا تھا۔ ابوجہل اس کے بھائیوں کو انتقام کے لیے بھڑکا رہا تھا۔ عتبہ نے انھیں ٹھنڈا کرنے کے لیے عمرو کے قتل کی دیت اور دیگر نقصان کی تلافی بھی اپنے ذمے لے لی۔
اس نے اپنی قوم سے کہا: ’’قریش کے لوگو! تم محمدؐ اور اُن کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہیں دے لو گے۔ خدا کی قسم! تم نے انھیں اگر مار لیا تو اپنے چچازاد یا خالہ زاد یا کنبے کے کسی آدمی کو ہی قتل کیا ہوگا‘‘۔ لیکن ابوجہل نے عمرو بن حضرمی کے بھائیوں کو مشتعل کرکے اتنی زیادہ انتقامی فضابنادی کہ عتبہ بن ربیعہ کی جنگ ٹالنے کی تدبیر ناکام ہوگئی ، حتیٰ کہ وہ اپنی قوم پرستی کے ثبوت کے لیے میدانِ جنگ میں سب سے آگے مبارز طلب ہوا۔ ( الرحیق المختوم ،ص ۲۹۱)
حضرت ابوبکرؓ پر حرم میں تشدد کی خبر جب ان کے خاندانِ بنوتیم کو معلوم ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور مارنے والوں کو دھکے دے کر حضرت ابوبکرؓ سے ہٹایا۔ انھیں ایک کپڑے میں ڈال کے ان کے گھر لے گئے۔ خاندان بنوتیم کو ان کی زندگی کی کوئی اُمید نہ تھی۔ انھیں گھر چھوڑ کر وہ سب پلٹ کر صحن حرم میں آئے اور للکار کر کہا: ’’اللہ کی قسم! اگر ابوبکر کو کچھ ہوگیا تو عتبہ بن ربیعہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے‘‘۔
وہ واپس حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے۔ سارے دن کی بے ہوشی کے بعد مغرب کے وقت انھیں ہوش آیا تو سب سے پہلے انھوں نے اللہ کے رسولؐ کا حال پوچھا تو خاندان کے لوگ ناگواری کے ساتھ ان کے ہاں سے چلے گئے۔ ( سیرۃ ابن کثیر۱/ ۴۴۱ بحوالہ ضیاء النبیؐ، ۲/ ۲۳۹)
قریش کا ایک سردار ابوالبختری بھی اسلام مخالف تھا۔ وہ جنگ ِ بدر میں قتل ہوا، جب کہ حکیمؓ بن حزام فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔شعب ابی طالب کے دنوں میں جب بنوہاشم قریش کے معاشرتی و معاشی بائیکاٹ کے باعث اناج کی قلت کے شکار تھے۔ حکیم بن حزام چوری چھپے بنوہاشم کو غلّہ پہنچانے کے لیے اپنے غلام کے ہمراہ نکلے تو ابوجہل مزاحم ہوگیا کہ معاہدے کے مطابق بنوہاشم کو قریش کچھ نہ دیں گے۔ حکیمؓ بن حزام نے کہا کہ وہ یہ گندم بنوہاشم کے لیے نہیں اپنی پھوپھی خدیجہؓ کے لیے لے جارہے ہیں جو کہ بنواسد کی بیٹی ہے۔ ابوجہل نے کہا کہ خدیجہؓ تو قوم کی مخالفت میں بنوہاشم کے ساتھ ہے۔ حکیم بن حزام نے ابوجہل کی بات ماننے سے انکار کیا۔ اسی توتکار میں ابوالبختری بھی آگیا اور اس نے ابوجہل کو کہا کہ اس کی پھوپھی نے اس کے پاس رکھی ہوئی اپنی گندم منگوائی ہے تو تمھیں اسے روکنے کا کیا حق ہے؟ اس بات پر ابوجہل اور ابوالبختری آپس میں دست و گریبان ہوگئے۔ ابوالبختری نے قریب پڑی ہوئی اُونٹ کی ایک ہڈی پکڑ کر ابوجہل کے سر میں دے ماری جس سے ابوجہل کا خون بہنے لگا۔ پھر اس نے ابوجہل کو اُٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اس دوران حضرت حمزہؓ ان کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوگئے۔ ( البدایہ ۳/ ۱۰۹ بحوالہ ضیاء النبیؐ، ۲/ ۳۸۶)
ہشام بن عمرو عامری کافر تھا۔ اس نے رات کی تاریکی میں سامانِ خوراک سے لدے تین اُونٹ شعب ابی طالب میں بھجوائے۔ صبح جب ابوجہل کو مخبری ہوئی تو وہ سردارانِ قریش کے ایک وفد کو لے کر ہشام کے گھر پہنچ گیا اور اسے کہا کہ اس نے قریش کے ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہشام نے اسے کہا کہ بھوکوں کو کھلانا کب سے جرم بن گیا ہے؟ سردارانِ قریش نے اُس پر اتنا دبائو ڈالا کہ اُس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کر ے گا۔ اگلی رات ہشام پھر اناج کے دو اُونٹ لے کر شعب ابی طالب میں پہنچ گیا۔ قریش کو پھر معلوم ہوگیا۔ تکرار اتنی بڑھی کہ تلواریں میانوں سے باہر آگئیں۔ آخر ابوسفیان نے مداخلت کرکے ہشام کی جان چھڑائی۔ لیکن ہشام اپنے حساس دل کے ہاتھوں مجبور اپنے محصور رشتہ داروں کو بھوک سے نڈھال نہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ گاہے بگاہے رات کے اندھیرے میں سامان سے لدے اُونٹ شعب ابی طالب کے دھانے پر لے آتا اور پھر اُونٹ کو اپنی لاٹھی سے اندر ہانک دیتا۔ گھاٹی میں مقیم لوگ سامان اُتار کر اُونٹ کو واپس ہانک دیتے۔(دلائل النبوۃ لابی نعیم بحوالہ ضیاء النبیؐ، ۲/ ۳۸۶)
بنوہاشم کی شعب ابی طالب میں محصوری کو جب تین سال ہوگئے تو ہشام بن عمرو عامری نے پہلے زہیر بن ابی اُمیہ مخزومی کو قریش کے اس ظلم کے خلاف احتجاج کے لیے تیار کیا۔ زہیر کی ماں عاتکہ حضرت ابوطالب کی بہن تھیں اور دوسری طرف زہیر ابوجہل کا چچازاد تھا۔ اس کے بعد اس نے بنی نوفل کے سردار مطعم بن عدی کو ابوجہل کے فیصلے کے خلاف اپنا ہم خیال بنایا۔ اسی طرح ابوالبختری، زمعہ بن الاسود اور عدی بن قیس کو تیار کیا اور پھر قریش کی ایک مجلس میں باری باری ہر ایک نے معاشرتی مقاطعے کی اس دستاویز سے اپنی برأت کا اظہار کیا۔ ابوجہل بہت سٹپٹایا لیکن قریش میں سے کوئی بھی اس کی حمایت میں نہ بولا۔خانہ کعبہ میں آویزاں اس معاہدے کو یہ پھاڑنے کے لیے گئے تو اسے دیمک چاٹ چکی تھی۔ پھر زہیر اور ہشام عامری اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہتھیار بند ہوکر شعب ابی طالب میں پہنچے اور بنوہاشم کو اپنے ہمراہ مکہ میں لے آئے۔ ( سیرۃ ابن کثیر، ابن ہشام، زاد المعاد بحوالہ الرحیق المختوم، ص ۱۵۹-۱۶۱)
حضرت عثمان بن مظعون حبشہ سے واپس آئے تو بنومخزوم کے سردار اور ابوجہل کے چچا ولیدبن مغیرہ کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ کفّار اصحابِ رسولؐ پر تشدد کر رہے ہیں اور وہ ایک کافر کی پناہ میں آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کی ایمانی غیرت یہ گوارا نہ کرسکی۔ انھوں نے ولید بن مغیرہ کو اس کی امان اسے لوٹا دی تو ولید نے کہا: ’’کیوں بھتیجے! کیا میری قوم کے کسی آدمی نے تجھ سے کوئی زیادتی کی ہے؟‘‘۔ عثمان بن مظعون نے کہا کہ میں صرف اللہ کی امان میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب کافروں کے تشدد کے نتیجے میں ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تو ولید نے عثمان بن مظعون کو اپنی امان کی دوبارہ پیش کش کی۔(طبرانی، البدایہ، ۳/ ۹۳، بحوالہ حیاۃ الصحابہ، ۱/ ۳۸۹-۳۹۰)
زینب بنت ِ رسولؐ کے خاوند ابوالعاص بن ربیع جنگ ِ بدر کے قیدی تھے۔ ان کی رہائی کے وقت حضورؐ نے اُن سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ ابوالعاص کے مکہ پہنچنے پر زینب مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگیں۔ ایک دن قریش کے سردار ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی: ’’اے میرے چچا کی بیٹی! اگر تجھے زادِ سفر کے طور پر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلاتکلف مجھے کہو‘‘۔ ہند اپنی پیش کش میں مخلص تھی۔ جب زینب کا دیور کنانہ بن ربیع مسلح ہوکر انھیں لے کر نکلا تو قریش کے چند نوجوانوں نے تعاقب کرکے مقامِ ذی طویٰ پر انھیں گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر کنانہ نے انھیں للکار کر کہا: واللہ! تم میں سے جو شخص بھی ہمارے قریب آنے کی جسارت کرے گا تو میں اپنے تیروں سے اس کے سینے کو چھلنی کردوں گا‘‘۔
اسی دوران ابوسفیان دیگر سردارانِ قریش کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کنانہ کو کہا: ’’جب تک ہم تم سے بات نہ کرلیں، تیر نہ چلانا‘‘۔کنانہ کے رُکنے پر وہ اس کے قریب آیا اور رازداری سے کہنے لگا: ’’تم نے یہ سمجھ داری نہیں کی کہ دن کے اُجالے میں لوگوں کے سامنے اس خاتون کو لے کر نکل پڑے جس کے باپ کی وجہ سے ہم مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ان حالات میں اگر تم محمدؐ کی بیٹی کو علانیہ لے کر جائو گے تو جو لوگ یہ بات سنیں گے وہ یہی تو کہیں گے کہ اب قریش بالکل عاجز و ناکارہ ہوگئے ہیں اور یہ بات ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا باعث بنے گی۔ واللہ! مجھے زینب بنت محمدؐ کو یہاں روکنے سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ اسے روکنے سے ہماری آتشِ انتقام ٹھنڈی ہوسکتی ہے۔ سردست تم انھیں لے کر واپس اپنے گھر چلے جائو۔ چند روز تک یہ ہنگامہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ لوگ اس واقعہ کو بھول جائیں گے۔ اس وقت کسی رات کو اندھیرے میں انھیں لے کر چلے جانا۔ لوگ یہ دیکھ کر مطمئن ہوجائیں گے کہ ہم نے اُنھیں لوٹا دیا ہے‘‘۔
مخالفت کے باوجود ابوسفیان نے قریش کی اس وضع داری کا مظاہرہ کیا جو قبیلے کی بیٹیوں کے حق میں ان کی روایت تھی۔ چنانچہ کنانہ کو اس کی بات معقول لگی اور وہ زینبؓ کو لے کر گھر واپس آگیا۔ چند روز گزرنے کے بعد جب ماحول پُرسکون ہوگیا تو کنانہ رات کی تاریکی میں حضرت زینب کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوگیا۔( سیرۃ ابن ہشام ، ص ۵۸۷-۵۸۸)
فتح مکہ کے موقع پر مشہور دشمنِ اسلام اُمیہ بن خلف کے بیٹے صفوان کو اس کے چچازاد عمیر بن وہب کی سفارش پر حضورؐ نے امان دے دی۔ اس نے قبولِ اسلام کے بارے میں غوروفکر کے لیے دو ماہ کی مہلت مانگی۔ آپؐ نے اسے چار ماہ کی مہلت دے دی۔ فتح مکہ کے بعد جب قریش کی اکثریت مسلمان ہوگئی تو قریش کا پرانا حریف قبیلہ بنو ہوازن آبائی مذہب کا علَم بردار بن کر کھڑا ہوگیا کیونکہ وہ مسلمانوں کی کامیابی کو قریش ہی کی بالادستی تصور کر رہے تھے۔ انھوں نے وادیٔ حنین میں ۲۰ ہزار کا لشکر جمع کرلیا۔
حضورؐ ۱۲ ہزار کے لشکر کے ساتھ جب وادیٔ حُنین میں داخل ہوئے تو گھات میں بیٹھے بنوہوازن نے اچانک اُن پر تیروں کی بارش کردی۔ اس خلافِ توقع حملے سے مسلمانوں میں شدید بھگدڑ مچ گئی۔ قرآن کے مطابق زمین اپنی کشادگی کے باوجود مسلمانوں پر تنگ پڑگئی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ (التوبہ ۹:۵۲)
ابوسفیان جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی موقع پر موجود تھے۔ انھوں نے کہا: ’’اب ان کی بھگدڑ بحیرئہ احمر سے پہلے رُکنے والی نہیں‘‘۔ یہ بات سن کر صفوان بن اُمیہ کا سوتیلا بھائی جبلہ بن حنبل خوشی سے چلّا اُٹھا:’’آج محمدؐ کا جادو ٹوٹ گیا‘‘۔
اپنے ماں جائے کے اس جملے پر صفوان بن اُمیہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا: ’’اللہ تیرے دانت توڑے، چپ رہ۔ خدا کی قسم! مجھے قریش کے آدمی کی حکومت بنوہوازن کے آدمی کی حکومت سے زیادہ محبوب ہے‘‘۔
صفوان بن اُمیہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن قریشی عصبیت کے باعث وہ کسی اور قبیلے کی بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اللہ کے رسولؐ جانتے تھے کہ قریش کے ساتھ ان کی صلہ رحمی بالآخر قریشی عصبیت کو اسلامی عصبیت میں ڈھال دے گی۔ ( سیرۃ ابن ہشام ، ص ۸۳۷، الرحیق المختوم ، ص ۵۶۴)
عاص بن وایل سہمی بھی اسلام دشمن قریشی سردار تھا اور حضرت عمرؓ کے خاندان بنی عدی کا حلیف تھا۔ جب عمرفاروقؓ نے اسلام قبول کیا اور اس کا کھل کر اظہار کیا تو قریش نے حضرت عمرؓ کے گھر کا گھیرائو کرلیا۔ عمرفاروقؓ اہل خانہ کے ساتھ گھر میں بیٹھے تھے اور باہر لوگوں کا شوروغوغا برپا تھا۔ عبداللہ بن عمرؓ جو اُس وقت ۱۰، ۱۲ برس کے لڑکے تھے، بیان کرتے ہیں کہ ایک باوجاہت آدمی ریشمی گوٹے سے آراستہ کُرتہ زیب تن کیے اور دھاری دار یمنی چادر کا حُلّہ پہنے ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ یہ خاندان بنوسہم کا سردار عاص بن وایل تھا۔
اس نے حضرت عمرؓ سے پوچھا:’’خطاب کے بیٹے! یہ کیا معاملہ ہے؟‘‘
’’میں مسلمان ہوگیا ہوں، اس لیے تمھاری قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے‘‘۔
’’یہ نہیں ہوسکتا‘‘۔ یہ کہتے ہوئے عاص باہر گیا۔ لوگوں کی بھیڑ سے گلی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ عاص نے لوگوں میں پہنچ کر ان سے پوچھا:’’تم کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟‘‘
’’خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہوگیا ہے ‘‘۔لوگوں کے اس جواب پر عاص نے کہا: ’’اگر ایسا ہے تو کیا ہوا؟ ایک شخص نے اپنی ذات کے لیے ایک راستہ اختیار کیا تو تمھیں کیا اعتراض ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بنی عدی اپنے آدمی کو یونہی تمھارے حوالے کردیں گے۔ اس شخص کا خیال چھوڑ دو‘‘۔
عاص بن وایل کی یہ بات ایسی تھی کہ اس کو سنتے ہی لوگ ایسے چھٹ گئے جیسے کپڑا پہن کر پھینک دیا گیا ہو۔ ( سیرۃ ابن ہشام ، ص ۳۰۵، فتح الباری، ۷/۱۷۶)
ربِّ کریم کا فرما ن ہے: كُلُّ مَنْ عَلَيْہَا فَانٍ۲۶ۚۖ وَّيَبْقٰى وَجْہُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ۲۷ (الرحمٰن ۵۵:۲۶-۲۷) ’’ہرچیز جو اس زمین پر ہے فنا ہوجانے والی ہے اور صرف تیرے ربّ کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے‘‘۔ ہرمتنفس کو دُنیاوی زندگی سے ایک دوسری زندگی کی طرف سفر کرنا ہے۔ اس لیے یہ ربِّ کریم کا خصوصی فضل ہے کہ وہ اپنے کسی بندے سے اس دُنیاوی زندگی میں وہ کام لے لے، جو اس کی نجات اور کامیابی کے لیے بنیاد فراہم کرسکے۔ پروفیسر خورشیداحمد صاحب نے جب سے شعوری طور پر اسلام کو بطور ایک تحریک اور انقلابی قوت کے سمجھا، اس وقت سے ان کی زندگی کا مشن رضائے الٰہی کا حصول اور اپنی تمام ترجیحات کو تحریکی ترجیحات کے تابع کر دینا قرار پایا۔ دورانِ تعلیم اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستگی اور اس کی دعوت کے فروغ کے لیے جدوجہد اور اسلامی جمعیت طلبہ کی نظامت اعلیٰ سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی جماعت اسلامی میں شمولیت ان کی تحریکی وابستگی کی ایک دلیل تھی۔
ترجمان القرآن سے ان کی وابستگی ایک تحریکی فریضے کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں نے اُنھیں ہمیشہ یہی کہتے ہوئے سنا کہ:’’آخر دم تک ترجمان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں‘‘۔ کچھ عرصہ سے جب وہ علالت کی بناپر یکسوئی کے ساتھ ’اشارات‘ تحریر نہیں کر پاتے تھے تو اپنے احساسِ فرض کی بناپر مجھے ہدایت کرتے کہ ’’میں یہ بات ’اشارات‘ میں لانا چاہتا ہوں‘‘، اور ان کی تعمیلِ ارشاد میں مجھے نااہلی کے احساس کے باوجود حکم کی تعمیل کرنا ہوتی تھی۔
قارئین پر پروفیسر خورشید صاحب کا حق، اقامت دین کی جدوجہد میں اپنا تمام سرمایۂ حیات لگانے سے ہی ادا ہوسکتا ہے ؎
جان دی ، دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
ترجمان القرآن کے اعلیٰ معیار کو مزید بلند کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس خلا کو پُر کیا جاسکے جو تحریک اسلامی پاکستان کو ایک علمی قائد سے محروم ہونے کی شکل میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مودودیؒ کے لگائے ہوئے اس علمی شجر طیبہ کے ذریعے دعوت الی اللہ اور دعوتِ اطاعت ِ رسولؐ کو لوگوں کے دل و دماغ میں پیوستہ کرنے میں کامیابی عطا فرمائے، آمین!
پروفیسر خورشید احمد صاحب نے محترم مولانا مودودی کی فکر کو آگے بڑھانے میں تین اہم محاذوں پر کام کیا:
ان تین بنیادی کاموں کے ساتھ پروفیسر صاحب نے خود مغربی فکر کے تحلیلی جائزے کے ساتھ اسلامی تصورِ حیات کو عصری زبان میں پیش کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔
اس بات کی ضرورت ہے کہ تحریک، علمی قیادت کو اوّلین اہمیت دے اور ایسے نوجوان ذہن تیار کرے جو ولولہ اور جوش کے ساتھ تفقہ فی الدین کے ساتھ آنے والے دور کے پیش نظر اسلام کی پوری تعلیمات کو مختلف زبانوں میں پیش کرسکیں۔ یہ کام منصوبہ بندی، مسلسل کوشش اور رہنمائی کا طالب ہے۔
نوّے کی دہائی کے اوائل میں، جب میں دہلی میں صحافت کے ابتدائی مراحل سے گزر رہا تھا، مجھے دو ایسی شخصیات سے فیض حاصل ہوا جنھوں نے میرے فکری سفر کی بنیاد رکھی۔ ایک سے براہِ راست ملاقاتیں ہوئیں، جب کہ دوسرے سے محض فون پر رابطہ رہا اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ ان سے شرفِ ملاقات نصیب ہوا۔
یہ غالباً ۱۹۹۲ء کا سال تھا۔ کشمیری قائدین جب ایک طویل اسیری کے بعد دہلی آتے، تو وہاں مقیم چند کشمیری طلبہ اور ملازمت پیشہ افراد باری باری ان کی میزبانی کا فریضہ انجام دیتے۔ ایک سینئر ساتھی باقاعدہ شیڈول بناتے، اور جس دن کسی کی خدمتی ذمہ داری ہوتی، وہ دفتر یا کلاس سے چھٹی لے کر ان قائدین کی خدمت پر مامور ہوتا۔ وہ ان کے لیے ٹیکسی کی فراہمی یا کسی مقام پر پہنچنے میں مدد کرتا۔ میرواعظ عمر فاروق اور شبیراحمد شاہ تو ایک ٹیم کے ساتھ سری نگر سے دہلی آتے، مگر دیگر قائدین جیسے عبدالغنی لون، پروفیسر عبدالغنی بٹ، اور عباس انصاری وغیرہ کو مقامی معاونت درکار ہوتی۔ محمد یاسین ملک اُن دنوں انڈرگرائونڈ (روپوش) تھے، مگر ۱۹۹۴ء کے بعد جب انھوں نے دہلی آنا شروع کیا تو اُن کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام کیا جاتا تھا۔
ایک بار سیّد علی گیلانی صاحب دہلی آ کر چانکیہ پوری کے جموں و کشمیر ہاؤس میں قیام پذیر ہوئے، تو میری اور ایک اور ساتھی کی ’ڈیوٹی‘ ان کے ساتھ لگائی گئی۔ تب تک ان سے محض اتنا تعلق تھا کہ وہ سوپور سے ایم ایل اے اور معروف رہنما تھے، اور ہمارا خاندان بھی سوپور کا رہائشی تھا۔
اسی دوران ان کے نجی سیکریٹری، غالباً ڈاکٹر محمد سلطان نے، گیلانی صاحب کو یاد دلایا کہ معروف کالم نگار اور ماہر قانون اے جی نورانی ان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ جب نورانی صاحب کمرے میں داخل ہوئے، تو رسمی سلام دعا کے بعد انھوں نے سبھی، حتیٰ کہ ڈاکٹر سلطان کو بھی، باہر جانے کے لیے کہا۔ چونکہ میں اور میرا ساتھی چائے وغیرہ پیش کر رہے تھے، اس لیے ہمیں جانے کو نہیں کہا۔ چائے دینے کے بعد ہم ایک کونے میں بیٹھ گئے۔
تقریباً ایک گھنٹے بعد، رخصت ہوتے ہوئے نورانی صاحب نے گیلانی صاحب سے کہا کہ : ’’مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو کشمیر پر کالم لکھنے میں میری معاونت کرے اور مواد فراہم کرے‘‘۔ گیلانی صاحب نے فوراً مجھے آواز دی اور میرا تعارف کرایا۔ بطور کالم نگار میں پہلے ہی ان کا مداح تھا۔ ان دنوں ان کا کالم مشہور اخبار Stateman میں چھپتا تھا اور میں صرف ان کے کالم کی خاطر وہ اخبار خریدا کرتا تھا۔
نورانی صاحب نے مجھ سے فون نمبر مانگا، میرے پاس فون نہ تھا۔ انھوں نے اپنا نمبر دیا اور کہا کہ ہر اتوار کو صبح گیارہ بجے سے سوا گیارہ بجے تک وہ میری کال کا انتظار کریں گے۔ بعد ازاں ہمارا ایسا تعلق بن گیا کہ میں نے ان کی پانچ کتابوں کے لیے بطور ریسرچر کام کیا۔ جب انڈین وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف کے کشمیر فارمولے پر ان کی گیلانی صاحب سے ناراضی ہوئی، تو وہ کہتے تھے کہ ’’میں گیلانی صاحب سے خفا ہوں، مگر یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا کہ انھوں نے افتخار سے میرا تعارف کرایا‘‘۔
اسی دورے کے دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ میں گیلانی صاحب کے کمرے کے باہر ان کے سیکریٹری کا کوئی کام کر رہا تھا کہ اچانک اندر سے بلایا گیا۔ گیلانی صاحب کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ پاکستان سے پروفیسر خورشید احمد کال پر ہیں۔ انھوں نے کہا کہ وہ ریسیور ایک برخوردار، افتخار گیلانی، کو دے رہے ہیں جو صحافت کے طالب علم ہیں اور ان کا مسئلہ حل کرسکتے ہیں۔ جب میں نے کال سنبھالی، تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پروفیسر صاحب کی کئی کتابیں اور مقالات پہلے ہی میرے مطالعے میں آ چکے تھے۔ انھوں نے بھی یہی کہا کہ انھیں کشمیر پر مسلسل مواد درکار ہے۔
پھر پرو فیسر صاحب نے رہنمائی کی کہ ’’ہر ہفتے کشمیر پر اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹس اور مضامین کی تلخیص تیار کر کے مجھے بھیجی جائے‘‘۔ دہلی میں کشمیر ٹائمز کا دفتر شاہجہان روڈ پر واقع تھا اور کشمیر پر اطلاعات کا واحد ذریعہ تھا۔ ایس کے ڈھنگرہ صاحب، جن کے تحت مَیں نے بعد میں کام کیا، اس کے انچارج تھے۔ وہ اسی دفتر میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ ان کا گھر گراؤنڈ فلور پر تھا، وہ اخبار کی کاپیاں کھڑکی کی سلاخوں کے پاس رکھ دیتے تھے۔ میں وہیں کھڑے کھڑے اخبارات پڑھ کر اہم نکات ڈائری میں نوٹ کرتا، کیونکہ دفتر کے اندر وہ داخل ہونے نہیں دیتے تھے۔
چند ہفتوں بعد، پروفیسر صاحب نے مشورہ دیا کہ ’تلخیص ٹائپ کر کے بھیجی جائے‘۔ مجھے یاد ہے کہ انھوں نے دہلی میں اپنے ایک رفیق کو میرے لیے چھوٹا سا ٹائپ رائٹر لانے کا کہا۔ کافی عرصے تک یہ ٹائپ رائٹر میرا ساتھی رہا۔ کمپیوٹر آنے کے بعد بھی میں نے اسے بطور تبرک سنبھالے رکھا۔
اس تمام سلسلے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اے جی نورانی صاحب اور پروفیسر خورشید صاحب کے مضامین پڑھ کر مجھے اندازہ ہونے لگا کہ معلومات کا کس طرح استعمال اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ میں تو محض ابتدائی معلومات فراہم کرتا تھا۔
پروفیسر خورشید احمد صاحب سے یہ تعلق اُس وقت تک برقرار رہا جب تک ۱۹۹۵ء میں دہلی میں حریت کا دفتر قائم نہ ہوا۔ پھر میں خود بھی مصروف ہو گیا اور یہ کمٹمنٹ نبھانا ممکن نہ رہا۔
فروری ۲۰۰۱ء کے دوران، اسلام آباد میں میرے ایک کزن ذوالقرنین کی شادی تھی۔ میں کچھ دنوں کی تاخیر سے پہنچا۔ ارشاد محمود صاحب نے پروفیسر صاحب سے ملاقات کا بندوبست کرایا۔ اپنے دفتر میں مجھ جیسے نو آموز صحافی کا انھوں نے جس محبت سے استقبال کیا، وہ انھی کا خاصہ تھا۔
میں ان دنوں پاکستانی اخبارات دی نیشن اور نوائے وقت کے لیے دہلی سے رپورٹنگ کرتا تھا۔ انھوں نے میری رپورٹس کی ایک باقاعدہ فائل بنا رکھی تھی۔ ملاقات سے قبل میرا ارادہ تھا کہ ان کا انٹرویو لے کر کشمیر ٹائمز میں شائع کروں، جہاں میں بیورو میں کام کرتا تھا، مگر انھوں نے خود میرا انٹرویو لیا۔ دو گھنٹے تک وہ بھارت کی سیاست، صحافت، کشمیر اور میری رپورٹس پر سوالات کرتے رہے۔ دہلی شہر کو وہ بہت یاد کرتے تھے: قرول باغ، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامع مسجد، گلی قاسم جان، ترکمان گیٹ، —سب کا ذکر چھیڑا۔
اسی طرح ۱۹۹۳ء میں سیّد علی گیلانی صاحب کی جیل ڈائری رُودادِ قفس کے نام سے شائع ہونی تھی۔ مرحوم الطاف احمد شاہ اس کا مسودہ دہلی لائے اور اگلے روز اسے پریس میں دینا تھا۔ ایک ساتھی، جو اَب معروف ٹی وی پروڈیوسر ہیں، نے جب مسودہ دیکھا تو کہا کہ اس پر کسی بڑی شخصیت کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ طے پایا کہ پروفیسر خورشید احمد سے رابطہ کیا جائے۔ پروفیسر صاحب سے جب الطاف شاہ نے رابطہ کیا تو انھوں نے کہا کہ مکمل مسودہ پہنچنے میں وقت لگے گا، لہٰذا اس کی ایک تلخیص بھیج دی جائے۔ ہم نے پوری رات جاگ کر تلخیص تیار کی اور اگلے دن انھیں فیکس کر دی۔ انھوں نے مکمل کتاب بعد میں پڑھی، مگر مقدمہ انھوں نے پہلے ہی تلخیص کی بنیاد پر تحریر کیا تھا۔
اس مقدمے میں انھوں نے لکھا:’’جب میں سیّد علی گیلانی کی پُرآشوب اور ہنگاموں سے بھری زندگی پر نظر ڈالتا ہوں، اور ان کی شخصیت کے وہ نقوش ذہن میں لاتا ہوں، جو دل و دماغ پر نقش ہو چکے ہیں، تو میرے سامنے اقبال کا مردِ مومن اُبھر آتا ہے۔ وہ خود بھی اسی مرد مومن کی عملی تفسیر تھے‘‘۔
یہاں پر اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ انڈین وزیراعظم ڈاکٹر من موہن سنگھ اور پاکستانی فوجی حاکم صدر جنرل پرویز مشرف کے کشمیر فارمولے پر کشمیر میں سیّد علی گیلانی کے علاوہ دوسرے سیاسی طبقوں میں اتفاق رائے تھا۔ انڈین حکومت اس وقت کسی طرح گیلانی صاحب کو بھی اس کشتی میں سوار کرانا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے وہ ایسے افراد کی تلاش میں تھی، جو بزرگ حُریت لیڈر پر اثرورسوخ استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ قرعہ فال پروفیسر خورشیداحمد صاحب کے نام نکلا۔ وزیراعظم من موہن سنگھ کے ایما پر سینئر سفارت کار ایس کے لامبا (م:۲۰۲۲ء) اور اے جی نورانی نے ان سے ملاقات کرکے، انھیں علی گیلانی صاحب کو ’مشرف فارمولا‘ قبول کرنے پر آمادگی کے لیے گزارش کی۔ مگر پروفیسر صاحب نے حُریت کے اندرونی معاملات اور ان کی فیصلہ سازی میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا، اور ایسی معاونت سے معذرت کرلی۔ اسی طرح حکومت پاکستان کی طرف سے بھی پروفیسر صاحب کو اس سمت میں خاصے دبائو کا سامنا کرنا پڑا مگر وہ کشمیری قیادت پر اثرانداز نہیں ہوئے۔
پروفیسر خورشید احمد صاحب کو دیکھنے اور سننے سے پہلے اُن کے علم، فہم، تدبر اور کردار کا بہت چرچا سن رکھا تھا۔ ان کا نام علمی، فکری اور دینی حلقوں میں احترام سے لیاجاتا تھا۔ تاہم، ۱۹۹۲ء میں جب مجھے اُن کے قائم کردہ ادارے انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز (آئی پی ایس)سے وابستہ ہونے کا موقع ملا، تو اُنھیں قریب سے دیکھنے، سننے اور ان سے استفادہ کرنے کے کئی مواقع میسر آئے۔
پروفیسر صاحب عشروں سے برطانیہ میں مقیم تھے، لیکن جب بھی سینیٹ کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے پاکستان آتے، تو بڑی تیاری اور جامع منصوبہ بندی کے ساتھ آتے۔ پاکستان میں ان کے قیام کے دوران انسٹی ٹیوٹ میں متعدد علمی نشستیں، سیمینار اور کتابوں کی تعارفی تقاریب کا انعقاد ہوتا، جن کی ترتیب و تنظیم میں مجھے بھی شریک رہنے کا موقع ملتا۔ ان تقریبات کے انتظام و انصرام کے دوران نہ صرف ادارے کے سربراہ جناب خالد رحمٰن کی راہ نمائی میسر آتی،بلکہ پروفیسر خورشید احمد صاحب سے بھی براہِ راست تبادلہ خیال کا موقع ملتا، جس سے ان کی شخصیت کو سمجھنے اور استفادے کے کئی نئے دریچے کھلتے۔
پروفیسر خورشید صاحب کی دلچسپیاں بے حد وسیع اور متنوع تھیں: —اسلامی معیشت، تعلیم، اسلامی تحریکیں، پاکستان کی سیاست، عالمی امور اور مسلم امہ کے مسائل۔ —گویا ہر موضوع ان کے فکری کینوس پر نمایاں تھا۔ تاہم، کم لوگوں کو معلوم ہے کہ نوّے کے عشرے کے بعد سے انھوں نے اپنے قیمتی وقت کا ایک بڑا حصہ کشمیر کاز کے لیے وقف کر رکھا تھا۔
ان سے میری قربت اور ملاقاتوں کی بنیاد بھی کشمیر ہی بنا۔ وہ سال میں تین سے چار مرتبہ برطانیہ سے اسلام آباد آتے تو ان کے معتمدِ خاص، راؤ محمد اختر، اُن کی مصروفیات کا جائزہ لینے کے بعد مجھے اطلاع دیتے: ’’میاں، ملاقات کی تیاری کر لو‘‘۔ اس کا مطلب ہوتا کہ پروفیسر صاحب کو میں نے گذشتہ چند ماہ کے دوران کشمیر اور پاک انڈیا تعلقات کے پس منظر میں رُونما ہونے والے اہم واقعات کی جامع بریفنگ دینی ہے۔ —ایسی بریفنگ جو نہ صرف حالات کا خلاصہ ہو بلکہ اس کے تحریکِ آزادی پر اثرات کی جامع تصویر بھی پیش کرے۔
ابتداء میں یہ بریفنگ محض سات سے دس منٹ پر مشتمل ہوتی، مگر رفتہ رفتہ اس کا دورانیہ بڑھتا گیا۔ چونکہ اُن کے پاس وقت نہایت محدود ہوتا اور مصروفیات کا ایک انبار ہوتا، اس لیے مجھے ہمیشہ ’دریا کو کوزے میں بند‘ کرنے کا ہنر آزمانا پڑتا۔اس بریفنگ کے دوران وہ اکثر اہم سوالات کرتے، میری آراء لیتے اور کئی مرتبہ حکومتی اہلکاروں، سفارت کاروں یا سیاست دانوں سے ہونے والی گفتگو کے اہم نکات بھی میرے ساتھ شیئر کرتے۔ یوں کشمیر اور پاک-بھارت تعلقات کی پیچیدہ اور باریک بین جہتوں کو سمجھنے میں مجھے گراںقدر رہنمائی حاصل ہوتی۔
کشمیر کے ہر پہلو سے ان کی دلچسپی تھی۔ تحریکِ مزاحمت کی بدلتی صورتِ حال سے وہ ہمیشہ باخبر رہتے، لیکن ان کی توجہ صرف سیاسی سرگرمیوں تک محدود نہیں تھی۔ وہ کشمیر پر ہونے والے علمی کاموں کو بھی دل سے سراہتے اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے۔ نوّے کے عشرے میں ڈاکٹر طاہر امین نے Mass Resistance in Kashmir کے عنوان سے ایک اہم کتاب لکھی۔ اس کی تعارفی تقریب آئی پی ایس میں ہوئی۔ اس موقعے پر بین الاقوامی اسلامی یونی ورسٹی کے صدر، ڈاکٹر ممتاز احمد نے انکشاف کیا کہ انھوں نے ستّر کی دہائی میں کشمیر پر جو کتاب لکھی تھی، اس کے پسِ پردہ بھی پروفیسر خورشید صاحب ہی کی تحریک اور حوصلہ افزائی کارفرما تھی۔
پروفیسر صاحب کی سرپرستی میں آئی پی ایس نے کشمیر پر درجنوں کتابیں شائع کیں اور سیکڑوں علمی سیمینار اور فکری نشستوں کا انعقاد کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر صرف سیاسی نعروں یا سفارتی بیانات تک محدود نہ رہے بلکہ فکری اور علمی میدان میں بھی اس پر سنجیدہ بات ہو۔
یہ ان کی کشادہ ظرفی اور فکری وسعت تھی کہ آئی پی ایس کا پلیٹ فارم ہر مکتبِ فکر کے لوگوں کے لیے کھلا تھا۔ شاید ہی کوئی اہم کشمیری رہنما ایسا ہو جسے یہاں بات کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔ جو بھی کشمیری لیڈر پاکستان تشریف لاتا، آئی پی ایس میں اس کے ساتھ تبادلہ خیال کی ایک محفل ضرور برپاہوتی۔ جناب عبدالغنی لون، شیخ عبدالعزیز، سردار محمد ابراہیم خان، سردار عبدالقیوم خان، یاسین ملک، امان اللہ خان اور وید بھیسین جیسے کئی بڑے نام اس فورم پر آ کر پاکستانی دانش وروں کے ساتھ مکالمے میں شریک ہوئے۔
کشمیر کے حوالے سے پروفیسر خورشید صاحب کی سوچ محض عوامی یا غیر رسمی دائرے تک محدود نہ تھی۔ وہ حکومت اور سرکاری اداروں کے ساتھ رابطے کو بھی ضروری سمجھتے تھے، اور اس بات کے قائل تھے کہ ریاستی سطح پر بھی راہ نمائی کی جائے۔ جب تک وہ سینیٹر رہے، ہر دورِ حکومت میں انھوں نے مسئلہ کشمیر پر مدلل، متوازن اور مؤثر تجاویز پیش کیں۔ سینیٹ میں ان کی تقاریر قومی، فکری اور ملّی سوچ کی بھرپور عکاس ہیں۔
پروفیسر خورشید صاحب کا فکری خمیر تحریکِ پاکستان کے ماحول میں پروان چڑھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی تحریروں اور تقریروں میں قائداعظم محمد علی جناح ؒکے فرمودات اور تقاریر کے برمحل حوالے کثرت سے ملتے ہیں۔ وہ ان حوالوں کو صرف تاریخی تناظر میں نہیں بلکہ موجودہ حالات کی روشنی میں نئے مفاہیم کے ساتھ پیش کرتے، اور یوں تاریخ اور حال میں ایک فکری ربط قائم کرتے تھے۔
ایک بار میں نے انڈیا کے ممتاز قانون دان اے جی نورانی [۱۶ستمبر ۱۹۳۰ء- ۲۹؍اگست ۲۰۲۴ء] کو میریٹ ہوٹل، اسلام آباد سے لے جا کر پروفیسر خورشید صاحب سے ملاقات کرائی۔ نورانی صاحب بڑے محقق اور دانشور تھے، ان کا دل کشمیریوں کے لیے دھڑکتا تھا۔ اپنی کتابوں اور مضامین میں انھوں نے کشمیر کے مختلف پہلوؤں کو مدلل انداز میں اُجاگر کیا ہے۔ صدر جنرل پرویز مشرف [۱۹۴۳ء- ۲۰۲۳ء]کے دور میں وہ ’ٹریک ٹو‘ ڈپلومیسی میں بھی کافی سرگرم رہے۔ انھی دنوں انھوں نے جنرل مشرف کا ایک دھماکا خیز انٹرویو کیا تھا جو پندرہ روزہ Frontline میں شائع ہوا۔ نورانی صاحب، سیّد علی گیلانی [۲۹ستمبر ۱۹۲۹ء- یکم ستمبر ۲۰۲۱ء]کے بھی بہت قریب تھے، اور انھوں نے گیلانی صاحب کو مشرف کے چار نکاتی فارمولے کی حمایت پر آمادہ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔
نورانی صاحب جانتے تھے کہ سیّد علی گیلانی، پروفیسر خورشید صاحب کا بے حد احترام کرتے ہیں اور ان کی رائے کو نظرانداز نہیں کرتے۔ اس لیے انھوں نے پروفیسر خورشید صاحب سے کہا کہ آپ گیلانی صاحب کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی راہ نکالی جاسکے، خاص طور پر مشرف فارمولے کے تحت‘‘۔ مگر گیلانی صاحب کا موقف واضح اور غیر متزلزل تھا۔دونوں بزرگوں کے درمیان خاصی طویل ملاقات رہی، مگر بات بنی نہیں، کیونکہ پروفیسر خورشید صاحب، گیلانی صاحب پر دباؤ ڈالنے پر آمادہ نہ تھے۔وہ سیّد علی گیلانی کی شجاعت اور قربانی کے بہت بڑے مداح تھے۔
پروفیسر خورشید احمد محض ایک دانش ور ہی نہیں تھے بلکہ ایک سرگرم سیاسی اور سماجی رہنما بھی تھے۔ وہ صرف علمی میدان میں ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں بھرپور طریقے سے شریک رہتے تھے۔ کشمیر کے حوالے سے ان کی وابستگی محض جذباتی اور قومی بنیادوں پر نہیں تھی، بلکہ انھوں نے اخلاقی، اصولی، قانونی اور تنظیمی سطح پر بھی گراں قدر کردار ادا کیا۔ برطانیہ میں تحریکِ آزادیٔ کشمیر کو منظم کرنے میں ان کا کردار کلیدی تھا۔ اسلامک مشن کے پلیٹ فارم سے ابتدا کی، اور پھر اسی کے بطن سے ’تحریکِ کشمیر‘ کے نام سے ایک باقاعدہ فورم تشکیل دیا۔
برسوں تک تحریکِ کشمیر کی قیادت مردِ درویش منور حسین مشہدی مرحوم کے ہاتھ میں رہی، اور اس پلیٹ فارم نے برطانیہ میں کشمیر کاز کے لیے نمایاں خدمات سرانجام دیں۔ برطانیہ میں مقیم کشمیری، پاکستانی اور دیگر مسلمانوں کو منظم کرنا، ان کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو سیاسی اور فکری میدان میں اُجاگر کرنا ان کا ہدف تھا۔
اسّی کے عشرے میں جب مسئلہ کشمیر نئے پس منظر میں انگڑائی لے رہاتھا ۔پروفیسر خورشید صاحب نے پیر حسام الدین ایڈووکیٹ، جو مقبوضہ کشمیر کے ایک مایہ ناز قانون دان اور تحریکی رہنما تھے، انھیں برطانیہ مدعو کیا جہاں وہ کافی عرصے تک مقیم رہے، اور برطانیہ اور یورپ میں مسئلہ کشمیر کو اُجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں پیرحسام الدین واپس مقبوضہ کشمیر چلے گئے کیونکہ حج کے دوران بھارتی حکام نے ان کا پاسپوٹ ضبط کرلیا تھا، جہاں ۲۰۰۴ء میں ’نامعلوم افراد‘ کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔
ریاست جموں و کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے کشمیری حلقوں میں متعدد پہلوئوں پر اختلافِ رائے پایا گیا ہے۔ اگرچہ ایک بڑی اکثریت پاکستان سے محبت کرتی ہے، لیکن ایک نمایاں طبقہ ایسا بھی ہے جو کشمیر کو ایک ’خودمختار ریاست‘ کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی نیا خیال نہیں، بلکہ اس کی جڑیں بیسیویں صدی میں چالیس کے عشرے تک جاتی ہیں۔۱۹۹۰ء میں جب تحریکِ مزاحمت نے ایک ہمہ گیر عوامی تحریک کی شکل اختیار کی، تو اس مسئلے پر خاصی تلخیاں بھی پیدا ہوئیں۔ کشمیر کے مستقبل کے سوال پر کئی محاذ کھل گئے، اور افسوس کہ اس کش مکش میں دونوں طرف کا جانی اور سیاسی نقصان ہوا۔
مجھے پرویز مشرف کے دورِ حکومت میں مقبوضہ کشمیر اور دہلی جانے کا موقع ملا۔ ان دوروں نے نہ صرف کشمیر کی زمینی حقیقت کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیا بلکہ کئی اہم سیاسی رہنماؤں سے دوستانہ تعلقات بھی قائم ہوئے۔ جناب یاسین ملک بھی ان میں سے ایک تھے۔ ان سے پہلی ملاقات رسمی تھی ،لیکن جلد ہی یہ تعلق دوستی میں اور پھر گہری رفاقت میں بدل گیا۔
اسی تعلق کی بنیاد پر راقم نے یاسین ملک کی ملاقات پروفیسر خورشید صاحب سے کروائی، اور پھر ان دونوں کے درمیان بھی ذاتی سطح پر ایک احترام اور مشاورت کا رشتہ قائم ہوگیا۔ پروفیسر خورشید صاحب نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ سیّد علی گیلانی اور میر واعظ عمر فاروق کے ساتھ مل کر جدوجہد کو مربوط بنائیں۔ کشمیر کے مستقبل کے سوال پر انھوں نے یاسین ملک کو یہی مشورہ دیا کہ فیصلہ کشمیری عوام کی مرضی اور رائے پر چھوڑ دینا چاہیے۔
۲۰۱۱ء میں جب یاسین ملک اسلام آباد میں کچھ وقت گزار کر واپس سری نگر لوٹے، تو ان کی تمام تر توجہ حریت پسند جماعتوں کے درمیان اتحاد پر مرکوز رہی۔ انھوں نے جناب علی گیلانی اور میرواعظ عمر فاروق کو ایک میز پر بٹھایا، جو ایک بڑا قدم تھا۔ لیکن بھارت کی جانب سے اس کوشش کا شدید ردعمل آیا۔ بھارتی اسٹیبلشمنٹ غیر معمولی طور پر مشتعل ہوئی، اور یاسین ملک کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑی، —جو وہ آج تک تہاڑ جیل میں چکا رہے ہیں۔
۵؍ اگست ۲۰۱۹ء کو بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو دفعہ ۳۷۰ اور ۳۵-اے سے متعلق ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کرکے ریاست جموں و کشمیر کی آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کی راہ ہموار کردی۔ اس نازک مرحلے پر، پروفیسر خورشید صاحب نے ماہ نامہ ترجمان القرآن میں کشمیری قیادت کو مشورہ دیا کہ وہ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ریاست جموں و کشمیر کے مسلم تشخص کے تحفظ کے ایک نکاتی ایجنڈے پر وسیع البنیاد اتفاق رائے پیدا کریں۔حالانکہ وہ جانتے تھے کہ بھارت نواز اور آزادی پسند کشمیری سیاستدانوں میں اختلافات محض سیاسی نوعیت کےنہیںہیں، بلکہ یہ خلیج ناقابلِ عبور ہے۔ اس کے باوجود انھوں نے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو متحدہو کر مسلم تشخص کے تحفظ اور آبادی کا تناسب بگاڑنے کے بھارتی حربوں کا مقابلہ کرنےکی دعوت دی اور عملی اقدام کی اپیل کی۔
اسی طرح، حالیہ چند ماہ کے دوران آزاد جموں و کشمیر میں گورننس کی ناکامی اور سیاسی عدمِ استحکام کے باعث شدید عوامی بےچینی نے جنم لیا، جو بالآخر ایک ہمہ گیر تحریک کی صورت اختیار کرگئی۔ اس موقعے پر بھی، پروفیسر خورشید صاحب نے ترجمان القرآن [فروری ۲۰۲۵ء]کے ایک اداریے میں توجہ دلائی کہ اس تحریک کو ہرگز پاکستان مخالف رنگ نہ اختیار کرنے دیا جائے، بلکہ آزاد کشمیر کے عوام کو درپیش بنیادی مسائل کا سنجیدگی سے حل نکالا جائے۔ ساتھ ہی، کشمیری عوام کو مشورہ دیا کہ وہ قومی دھارے سے جڑے رہیں اور پاکستان مخالف جذبات کو آزاد کشمیر کی فضا میں جڑ نہ پکڑنے دیں۔ غالباً مسئلہ کشمیر پر پروفیسر خورشید احمد صاحب کی یہی آخری تحریر تھی — ایک فکر انگیز اور بصیرت افروز وصیت کی صورت میں۔
پروفیسر صاحب نہ صرف حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھتے تھے بلکہ اپنے نظریاتی مخالفوں اور اپنے ساتھیوں کی تحریروں کا بھی بڑی توجہ سے مطالعہ کرتے تھے۔ ۲۰۰۴ء میں جب جنرل پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے چار نکاتی فارمولا پیش کیا، تو میں نے عمومی طور پر اس خیال کی حمایت کی۔ میری نظر میں یہ ایک جمود توڑنے والا قدم تھا، جو مسئلہ کشمیر کو ایک نئی سمت دے سکتا تھا۔ میں نے اخبار دی نیوز میں اس پر ایک مضمون لکھا، جس میں مشرف کی سوچ کو پیش رفت کی ایک صورت کے طور پر بیان کیا۔ مضمون چھپنے کے چند گھنٹوں بعد پروفیسر صاحب کا فون آیا۔ کہنے لگے: ’’اگر آپ یہ لکھتے کہ یہ حل کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے، تو بات زیادہ مدلل اور مؤثر ہوتی‘‘۔ایک بار انھوں نے روزنامہ جنگ میں میرا ایک مضمون پڑھا تو بلا کر ستائش کی اور ساتھ مشورہ دیتے ہوئے کہا:’’برٹرینڈ رسل کی کتابیں پڑھو، دیکھو وہ کیسے دلیل قائم کرتے ہیں، ان کی تحریریں مختصر لیکن پر اثر ہوتی ہیں‘‘۔
لگ بھگ سولہ برس پہلے میں نے آئی پی ایس سے علیحدگی اختیار کر لی اور دیگر اداروں سے وابستہ ہو گیا، مگر اس کے باوجود پروفیسر خورشیداحمد صاحب کی شفقت اور توجہ قائم رہی۔ دو برس قبل پروفیسرصاحب کے معاون ترجمان القرآن نے بتایا کہ ’’پروفیسر صاحب چاہتے ہیں کہ خرم پرویز، جو انسانی حقوق کے نمایاں علَم بردار ہیں اور جنھیں بھارت میں جھوٹے مقدمات میں جیل میں ڈال دیا گیا ہے، ان پر آپ کے انگریزی مضمون کا اردو ترجمہ ترجمان القرآن میں شائع ہو‘‘۔ میرے لیے یہ بات باعثِ مسرت تو تھی لیکن حیرت کا باعث بھی کہ اس قدر علیل ہونے کے باوجود ان کا دل کشمیر میں اَٹکا ہواہے۔
مطالعے کا ذوق بھی وہ دوسروں میں منتقل کرنا چاہتے تھے۔ اسلام آباد کی مشہور دکان ’مسٹر بکس‘ سے اگر کوئی اچھی کتاب انڈیا، پاکستان یا کشمیر پر دیکھتے تو خرید کر راؤ اختر صاحب کے ذریعے مجھے بھی بھیج دیتے۔ ایک دو بار اپنی تقریروں اور تحریروں میں میری تحریر کا حوالہ بھی دیا۔ شاید یہ ان کی طرف سے حوصلہ افزائی کا ایک خاص انداز تھا، جو آج بھی یاد آتا ہے۔
اگرچہ پروفیسر خورشید احمد آسودۂ خاک ہو چکے، مگر ان کی درجنوں کتابیں، بے شمار شاگرد، قائم کردہ ادارے اور فلاحی منصوبے ہمیشہ ان کی یاد کو زندہ رکھیں گے۔ وہ اپنے پیچھے ایک ایسا علمی و فکری سرمایہ چھوڑ گئے ہیں، جو ان کے لیے صدقۂ جاریہ کی صورت میں ان کی قبر کو روشن اور آخرت میں ان کے لیے نجات و کامیابی کا سامان بنے گا، ان شاء اللہ!
؍اپریل کی دوپہر فون موصول ہوا:
’’آپ سے کہا تھا، ’جب وہ ناظم اعلٰی تھے‘ کے پہلے تین حصے بھجوا دیں، اس کا کیا کیا ہے؟‘‘
’’عرض کیا: فائونڈیشن آنے والے ایک صاحب کو دے دیئے ہیں، ۲۰؍اپریل تک ان شاء اللہ وہ پہنچا دیں گے‘‘۔
پھر دریافت فرمایا: ’’اچھا، تو مئی کے شمارے کے لیے کون کون سے موضوعات پیش نظر ہیں؟‘‘
عرض کیا:’’غزہ کی تازہ ترین صورتِ حال اور انڈیا میں مسلم وقف کے خلاف پارلیمنٹ کے فیصلے کی نسبت سے اور…‘‘ لفظ ’اور‘ کہا تھا کہ فون کا سگنل کٹ گیا، لیکن پھر فون بحال ہوا تو ’اور‘ سے آگے انھوں نے خود بات مکمل فرمائی:
’’بلو چستان پر ضرور تحریر آنی چاہیے، صورتِ حال بڑی تکلیف دہ ہے۔ معلوم نہیں کیوں پورے ملک میں بے فکری کا مظاہرہ کیا جارہا ہے؟‘‘
یہ آخری فون تھا، جس کے تین دن بعد۱۳؍اپریل ۲۰۲۵ء کی شام ۶بج کر ۱۸ منٹ پر پروفیسر خورشیداحمد صاحب کے بیٹے حارث احمد صاحب کا پیغام فون کی اسکرین پر نمودار ہوا: Abbu has returned back to his Creator ___ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ!
یوں انسانی وجود میں وہ چراغِ راہ بجھ گیا۔ انھوں نے شعوری طور پر ۱۹۴۹ء سے کردار، افکار اور پیکار کی دُنیا میں قدم رکھا اور پھر ہرلمحہ اور ہرقدم پڑھتے، لکھتے، معرکوں کا حصہ بنتے اور صف بندی کرتے ہوئے اپنے ربّ کے حضور پیش ہوگئے۔
پروفیسر خورشید صاحب نے یوں شعوری زندگی کے پورے ۷۶ برس، سکون کو ایک طرف جھٹکتے ہوئے اس راہِ شوق پہ چلتے چلتے زندگی گزار دی۔ وہ زندگی جس میں:
ذرا پیچھے چلیں تو یہ اپریل ۱۹۹۰ء کی بات ہے کہ میں نے محترم پروفیسر صاحب سے پوچھا: ’’ آپ نے سب سے پہلے مولانا مودودی کو کب دیکھا تھا؟‘‘
فرمایا: ’’یہ غالباً ۱۹۳۸ء سے پہلے کی بات ہے۔ میں اسکول کا طالب علم تھا۔ مولانا مودودی، میرے والد صاحب کی دعوت پر دہلی ہمارے گھر تشریف لائے۔ والد صاحب نے ضمیربھائی اور مجھے اُن سے ملاتے ہوئے کہا: یہ میرے نہایت قابلِ احترام دوست اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کو نظم سنایئے۔ میں پہلے ذرا جھجکا اور پھر بڑے جوش سے ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ نظم سنائی:
اسلام کا ہم سکّہ دُنیا پہ بٹھا دیں گے
توحید کی دُنیا میں، اِک دھوم مچا دیں گے
گونجیں گی پہاڑوں میں تکبیر کی آوازیں
تکبیر کے نعروں سے، دُنیا کو ہلا دیں گے
اسلام زمانے میں، دبنے کو نہیں آیا
تاریخ میں یہ مضمون ، ہم تم کو دکھا دیں گے
اسلام کے شیروں کو ، مت چھیڑنا تم ورنہ
یہ مٹتے مٹاتے بھی، ظالم کو مٹا دیں گے
اسلام کی فطرت میں، قدرت نے لچک دی ہے
اتنا ہی یہ اُبھرے گا، جتنا کہ دبا دیں گے
مولانا مودودی نے شفقت سے پاس بلاکر دُعا دیتے ہوئے چند پیسے بطور انعام دیئے۔ یہ مولانا کو پہلی مرتبہ دیکھنے کا واقعہ ہے اور پھر دسمبر ۱۹۴۷ء میں اچھرہ، لاہور میں مولانا سے ملے‘‘۔
مارچ ۱۹۴۰ء میں قرارداد لاہور منظور ہونے کے بعد دو قومی نظریہ کی بنیاد پر تحریک پاکستان شروع ہوئی۔ جناب خورشیداحمد کے والد گرامی نذیراحمد قریشی ، جو ایک طرف مولانا محمد علی جوہر کے دوست رہے تھے، دوسری طرف قائداعظم محمدعلی جناح اور علامہ اقبال سے محبت کا تعلق تھا، اور تیسری جانب مولانا مودودی سے برادرانہ مراسم تھے۔ اس آسودگی، علم دوستی اور ملّی و قومی درد مندی سے رچی فضا میں پروان چڑھتے نوخیز خورشیداحمد نے دہلی کے رہائشی علاقے قرول باغ میں، ’بچہ مسلم لیگ‘ کا یونٹ قائم کیا، اور بچوں سے مل کر تحریک پاکستان کے نغمے، ترانے اور نعرے بلند کرنا شروع کیے۔
۷ تا ۹ ؍اپریل ۱۹۴۶ء کو آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس اینگلوعریبک کالج ہال، دہلی میں منعقد ہوا، جس میں ’قراردادِ لاہور‘ میں درج مطالبے ’مسلم اسٹیٹس‘ (Muslim States) کو ’مسلم اسٹیٹ ‘ (State) میں تبدیل کرنے کی متفقہ قرارداد منظو ر کی گئی اور اسلام سے وفاداری کے حلف نامے پر قرآن کریم کی آیات پڑھ کر قائداعظمؒ اور مسلم لیگ کی ساری قیادت نے دستخط کیے۔ اس اجلاس میں ۶۹’کل ہند مندوبین‘ کی خدمت پر مامور طالب علموں میں خورشیداحمد بھی شامل تھے۔ انھوں نے بتایا تھا کہ ’’اس دوران میں نے مسلم لیگ کی پوری قیادت کو دیکھا اور خاص طور پر قائداعظم کی شخصیت کے وقار، رُعب اور بزرگی کا گہرا تاثر آج تک دل و دماغ پر نقش ہے‘‘۔
یہی خورشیداحمد اپنے والدین کے ہمراہ ۱۹۴۷ء میں دہلی سے ہجرت کرکے لاہور پہنچے اور مسلم ٹائون میں عارضی رہائش اختیار کی اور کالج میں داخلہ لیا۔یہاں بہار سے ہجرت کرکے آنے والے ان کے ہم جماعت اور دوست اقبال احمد (۹۹- ۱۹۲۳ء) تھے، جو بعدازاں ایک لبرل دانش ور کی حیثیت سے معروف ہوئے۔مئی ۱۹۴۹ء میں خورشیدصاحب کے اہل خانہ لاہور سے کراچی منتقل ہوئے۔ یہاں پر اُنھوں نے نو مبر میں پہلا مضمون لکھا اور پھر زندگی کے آخری حصے تک فکر، قلم اور کاغذ کا یہ تعلق کبھی ٹوٹنے نہ دیا۔ ۱۹۴۹ء ہی میں ان کے بڑے بھائی ضمیراحمد، جو کراچی اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم تھے، ان سے ملنے والے جمعیت کے رفقا نے خورشیدصاحب کو سماجی تعلقات کی دُنیا میں سمولیا اور انھیں تحریک اسلامی کا مجسم و متحرک کارکن، لیڈر ، ترجمان اور مفکر بنادیا۔
پروفیسر صاحب کے علم و فضل اور شخصیت کے حُسنِ کمال پر لکھنے والے بہت کچھ اور بہت مدت تک لکھیں گے۔ ذاتی حوالے سے داستان سرائی سے گریز کے باوجود ایک عرض کرتا ہوں کہ فروری ۱۹۷۰ء میں مجھے انتہائی مخالف کیمپ سے اللہ تعالیٰ نے موڑ کر اسلامی جمعیت طلبہ، وزیرآباد کے دفتر کا رستہ دکھایا۔ میٹرک کا امتحان ہونے میں ابھی ایک ماہ باقی تھا۔ جیسے تیسے امتحان دیا، اور پھر مئی کا مہینہ آیا۔ گائوں کی دوپہر میں جھلساتی لُو، شیشم تلے، رات کو کبھی لالٹین اور کبھی چاند کی روشنی میں اسلامی لٹریچر پڑھنے اور جذب کرنے کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتا، تو یہ پیاس اور زیادہ بھڑکتی چلی جاتی۔ جون کا مہینہ آیا میں نے جمعیت سے کیا پایا؟ سے خرم مراد اور خورشید صاحب کے مضامین پڑھے تو دونوں شخصیات سے محبت کے رشتے میں بندھ گیا، اور جب کڑاکے کی گرمی شروع ہوئی تو پروفیسر خورشیداحمد صاحب کی گرفتاری میں گزرے روز و شب کی رُوداد تذکرہ زندان زیرمطالعہ آئی۔ جس نے شگفتہ بیانی، ادب کی تراوت اور اسلامی احیا کی مٹھاس سے یک جان کردیا۔ اگست میں، سالِ اوّل میں داخلہ لیا۔
اس سے اگلے ماہ پروفیسر صاحب کا پتہ معلوم کروا کے وزیرآباد کے مضافات میں اپنے گائوں کٹھوہر سے انھیں انگلینڈ خط لکھا، جس میں درج تھا: ’’میں نے سالِ اوّل داخلے میں انگریزی ایڈوانس کامضمون اس لیے لیا ہے کہ بڑا ہوکر مولانا مودودی کی کتابوں کا انگریزی میں اور سیّد قطب شہید کی انگریزی ترجمہ شدہ کتابوں کا اُردو میں ترجمہ کروں۔ آپ سے راہ نمائی اور دُعا چاہتا ہوں‘‘۔
نومبر ۱۹۷۰ء کا مہینہ قومی انتخابی ہنگامے کے عروج کا مہینہ تھا۔ وہ خط جو انھیں چھے سات بدخط سی سطروں میں لکھ کر ارسال کیا تھا، اس کے جواب میں پروفیسر صاحب کا ایروگرام موصول ہوا جس میں انھوں نے لکھا تھا: ’’عزیزم، آپ کے جذبے کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور ذاتی طور پر بڑی تقو یت محسوس ہوئی ہے، وہ تقویت جو اقبال نے اس طرح بیان کی ہے:
تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں
یہاں سیکڑوں کارواں اور بھی ہیں
قناعت نہ کر عالم رنگ و بُو پر
چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں
گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں
یہاں اب مِرے رازداں اور بھی ہیں
اس کے ساتھ ساتھ ہی مطالعے ، محنت اور یکسوئی کے لیے، تنظیم سے وابستگی اور تربیت کی پیاس بڑھانے کے لیے مشورے دیتے ہوئے لکھا: ’’نصاب پر بھرپور توجہ دینا بہ حیثیت طالب علم آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایک اچھا طالب علم بن کر ہی اسلام، قوم اور ملّت کی خدمت کرسکتے ہیں۔ پھر گنجائش پیدا کرکے ترتیب اور سلیقے سے قرآن، سیرت، ادب، اقبال، تاریخ اور مولانا مودودی کی کتب کا مطالعہ کریں‘‘۔ پھر یہ بھی لکھا کہ ’’علمی کاموں میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ادب کی اصناف افسانہ اور ناول پڑھنا ضروری ہے کہ ان اصناف میں داخلی اور خارجی کیفیات کا اظہار سادہ اور براہِ راست اسلوب میں ہوتا ہے‘‘___دو تین بار خط پڑھا، تو اس کا متن یاد ہوگیا۔ میرے لیے بڑی حیرانی کی یہ بات تھی کہ ایک عام دیہاتی سے لڑکے کو، جو ابھی سالِ اوّل کا طالب علم ہے۔ اتنے بڑے استاد نے کس طرح دل کے قریب لاکر، اپنے دل میں بٹھا لیا ہے!
اس طرح نومبر ۱۹۷۰ء میں پروفیسر خورشیدصاحب سے قلم کا جو رشتہ قائم ہوا، وہ ۱۹۷۹ء کے بعد روحانی ربط، ذاتی تعلق میں ڈھل گیا۔ ۱۹۷۴ء میں ملاقات بھی ہوئی اور ازاں بعد آپ کی تقریروں اور تحریروں کو مرتب یا ترجمہ کرنے کی سعادت ملی۔
دسمبر ۱۹۹۶ء میں خرم مراد صاحب کے انتقال کے بعد محترم قاضی حسین احمد نے پروفیسر صاحب کو ماہ نامہ ترجمان القرآن کا مدیر مقررکیا۔ ان دنوں سڑک پہ حادثے کے سبب جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ لوہے کے شکنجے میں جکڑا، مَیں گھر میں بستر پر پڑا ہوا تھا۔ پروفیسر صاحب نے رسالے کی ذمہ داری سنبھالتے ہی جنوری ۱۹۹۷ء کو پہلی مشاورتی میٹنگ ہمارے گھر، لاچار مریض کے ’ہوم کیئربیڈ‘ کے قریب بیٹھ کر منعقد کی۔ محبت و اُلفت، بزرگی و سرپرستی کے کس کس ورق کو پلٹا جائے؟ یہ ممکن نہیں۔ حوصلہ افزائی کے لیے انھوں نے کیا کیا جملے کہے یا لکھے، کیوں کر بیان کروں؟ ناممکن!
البتہ ایک واقعہ ترجمان القرآن میں شائع ہوگیا تھا۔ محترم خر م مراد کی یادداشتوں کو لمحات کے زیرعنوان مرتب کرنے کے بعد محترم میاں طفیل محمد صاحب کی یادداشتوں کو مشاہدات کی صورت میں مرتب کیا۔ اس کتاب کی تعارفی تقریب منصورہ میں منعقد ہوئی، جہاں محترم میاں طفیل محمد، محترم قاضی حسین احمد اور محترم پروفیسر صاحب نے خطاب کیا۔ پروفیسر صاحب نے میاں صاحب کی کتاب کے مندرجات کا شاندار الفاظ میں تعارف کرانے کے بعد، ذرا لطیف پیرائے میں فرمایا: ’’مشاہداتکو میں اس پہلو سے بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ محترم میاں صاحب نے اس میں ایک پورے دور کو جس سادگی سے مفصل اور مؤثرانداز میں پیش کر دیا ہے، وہ ہماری تحریکی زندگی اور تجربات کا خلاصہ ایک بڑا ہی قیمتی تحفہ ہے۔ مَیں علامہ اقبال کی طرح شکوہ تو نہیں کرسکتا، لیکن اپنی اس خواہش اور تمنا کا اظہار کرتا ہوں کہ کاش! سلیم منصور خالد دس سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے، اور مولانا مودودی سے بھی ان کی باتوں کو اسی طرح جمع کر لیا ہوتا‘‘۔ (اگست ۲۰۰۱ء)
ماہانہ بنیادوں پر ترجمان القرآن کی تدوین اور اس کے علاوہ تین خصوصی نمبروں کی ترتیب کے دوران صر ف ایک موقعے پر پروفیسر صاحب نے رسالہ دیکھ کر، ایک جملے میں اپنی ناراضی کا اظہار ان الفاظ میں کیا: ’’کیا یہ مضمون دینا ضروری تھا؟‘‘ میں نے وضاحت کی کہ تاریخ کے ایک ریکارڈ کے طور پر دے دیا ہے۔ یہ مضمون ایک ممتاز تاریخ دان اور بزرگ صحافی کا تھا، جس میں انھوں نے اپنے ہم مسلک رسالے کے مدیر کو لکھا تھا:’’مولانا [مودودی]نے جب واضح طور پر کہہ دیا کہ’’جو الفاظ مجھ سے منسوب کیے گئے [ہیں] وہ میں نے نہیں کہے‘‘،تو پھر سمجھ میں نہ آیا کہ آپ نے اس بحث کو اس درجہ طول دینے کی ضرورت کیوں محسوس فرمائی؟ گویا آج آپ کے لیے اس کے علاوہ کوئی [اور] مسئلہ ہے ہی نہیں، جس پر توجہ فرمائی جائے‘‘۔ دراصل پروفیسر صاحب اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، دو افراد کی باہمی خط کتابت کو ہم اپنی ضرورت کے لیے درج کریں۔
ہر مہینے ترجمان القرآن جب بھی آپ کو لسٹر ملتا تو ۴ تاریخ کے بعد دو تین بار فون کر کے فرماتے: ’’ابھی تک پرچہ نہیں ملا۔ شدت سے انتظار کر رہا ہوں‘‘۔ اور جب پرچہ مل جاتا تو سب سے پہلے فون پر ’جزاک اللہ‘ کہتے۔ پھر پرچے کے مجموعی تاثر پر دو تین جملے کہتے اور اس کے بعد کم و بیش ہرمضمون پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ تک اعتراف کرتے کہ ’انھوں نے جو یہ بات لکھی ہے مجھے پہلی بار معلوم ہوئی ہے‘، ’ان کی یہ دلیل بہت باکمال ہے‘، ’یہ مضمون ذرا طویل ہے‘، ’اس مضمون پر انھیں میری طرف سے شکریے کا فون کریں یا شکریے کا خط لکھیں‘، ’انھیں کہیے کہ مزید لکھیں‘، ’مضمون میں چند پہلو تشنہ رہ گئے ہیں، کہیے کہ ایک نئے مضمون میں وہ پہلو بھی زیربحث لائیں‘۔ یوں تقریباً دس پندرہ منٹ میں پورے رسالے کا جائزہ بیان کرتے۔
اس کے علاوہ مہینے میں سات آٹھ بار ایسا ہوتا کہ اپنے زیرمطالعہ اخبارات، رسائل اور کتب سے مضامین کی تصویر بنوا کر، ان پر اپنے قلم سے کمنٹ لکھتے اور مختلف مقامات نشان زد کرکے بھیجتے۔ جن پر اس نوعیت کی ہدایت ہوتی: ’بہت اہم مضمون ہے‘، ’اس کا ترجمہ کرکے ترجمان میں دیں‘، ’ا س کا ترجمہ و تلخیص کرلیں‘، ’اسے محفوظ رکھ لیں‘، ’اس کا ترجمہ تو نہ دیں مگر ذاتی طور پر توجہ سے مطالعہ کریں‘، ’بہت مفید معلومات اور تجزیہ ہے،مضمون طویل ہے، اخذ کر کے مضمون مرتب کرلیں‘، ’یہ مضمون امیرجماعت کو مطالعے کے لیے دیں‘ وغیرہ___ وہ برطانیہ، امریکا، پاکستان، انڈیا کے اخبارات و جرائد کے علاوہ الجزیرہ اور مختلف معروف تھنک ٹینکس کے مضامین مطالعے کے لیے ارسال کرتے۔ اتنی مشقت کے بعد پورا اعتبار کرتے کہ ہدایت پر عمل کرلیا ہوگا۔ اسی طرح قائداعظم، تحریک پاکستان اور اقبال کے بارے میں کتب خرید کر تحفہ عطا فرماتے۔
مختلف بزرگوں، جماعت سے باہر کے حلقے کے حضرات، دانش وروں اور صحافت کاروں کی صحت کے بارے میں دریافت کرتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے سخت سوالات اور تبصرے ٹیلی ویژن اور اخبارات میں دیکھے تو فروری ۲۰۱۸ء میں مجھے ہدایت فرمائی: ’’انھیں جاکر میرا پیغام دیں کہ قانون اور ضابطے کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے نتیجۂ فکر کو فیصلوں میں ضرور لکھیں، مگر عدالتی کارروائی کے دوران تلخ اور بلند آہنگ تبصروں سے گریز کریں۔ جج کی اصل قوت درست فیصلہ ہے، نا کہ زبانی و قولی تبصرہ‘‘۔انھیں اعلیٰ عدلیہ کی تبصراتی روش پر شدید دُکھ تھا کہ ’’اس سے عدالت کا وقار، فیصلے اور مقام و مرتبہ متاثر ہوگا۔ اس طرزِعمل نے اعلیٰ عدلیہ کو بازیچۂ اطفال بنا دیا ہے، جس سے لاقانونیت اور انتشار میں اضافہ ہوگا‘‘۔
جب کبھی کسی فرد کے انتقال کی خبر ان تک پہنچاتا تو ’انا للہ وانا الیہ راجعون‘ کہہ کر ان کی خوبیوں کے بارے میں ایک دو جملے کہتے اور مغفرت کے دُعائیہ کلمات ادا فرماتے۔ مشرقی پاکستان سے جماعت اسلامی کے راہ نمائوں کی پھانسیوں پر انھیں بڑے کرب کے ساتھ سنا۔ یکم ستمبر ۲۰۲۱ء کی شب سیّد علی گیلانی صاحب کے انتقال کی خبر دی: ’ابھی پندرہ بیس منٹ پہلے گیلانی صاحب انتقال فرما گئے ہیں‘۔ پروفیسر صاحب نے انا للہ وانا الیہ راجعون تین بار دُہرایا اور کہا: ’’گذشتہ دو گھنٹے سے میری حالت ایسی تھی کہ جیسے جان نکل رہی ہے۔ ذہن مائوف تھا، طبیعت میں سخت اضطراب تھا، اور دماغ چکرا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا ہورہا ہے؟ اب معلوم ہوا کہ گیلانی صاحب سفرِآخرت کی سمت روانہ تھے۔ بہت صدمہ ہوا، بہت بڑا نقصان ہوگیا ہے، اللہ مالک ہے‘‘۔
مگر ان سب کیفیات سے ہٹ کر ۲۴؍اپریل ۲۰۱۶ء کو مختلف انداز سے اظہار ہوا، جب فون پہ ڈاکٹر ظفراسحاق انصاری صاحب کے انتقال کی خبر کا تبادلہ ہوا تو فرمانے لگے: ’’دو گھنٹے پہلے انیس نے بتایا تھا۔ اُس وقت سے اکیلا بیٹھا ہوں اور قرآن میرے سامنے ہے۔ سلیم، سچّی بات ہے کہ راجا [ظفراسحاق]کے جانے سے دل ٹوٹ گیا ہے‘‘ اور فون بند کردیا۔ پھر تقریباً دو گھنٹے بعد ان کا اپنا فون آیا: ’’غم کی اس شدت میں قرآن کی مسلسل تلاوت نے مجھے سہارا دیا ہے۔ یاد رکھیں دُکھ اور درد کی گھڑی میں قرآن کے سوا کوئی چیز سہارا نہیں دے سکتی۔ قرآن ہی ایک مسلمان کو سنبھالتا ہے‘‘۔
پروفیسر صاحب ہر مہینے دو مہینے بعد پاکستان اور انڈیا سے شائع ہونے والی کتابوں کی ایک فہرست لکھواتے کہ ’’یہ بھجوا دیں، میں پیسے بھیج دیتا ہوں‘‘۔ گذشتہ تین برسوں میں سب سے زیادہ کتب قرآن کی تشریح کے بارے میں منگوائیں۔ پھر سیرتِ رسولؐ پر، اس کے بعد قانون اور یادداشتوں پر مشتمل کتب کا تقاضا کیا۔ کتب ملنے پر باقاعدہ شکریے کا فون کرتے۔ ہرعید کو لازماً ظہر کے بعد فون آتا، مبارک اور دُعائیں دیتے۔ جب کبھی انھیں طبیعت کی خرابی کی خبر ملتی تو کہتے: ’’بہترین علاج کرائیں، اس بارے میں تساہل سے کام نہ لیں‘‘۔ چند مواقع پر یہ فون آیا: ’’کام تو کوئی نہیں، بس خیریت معلوم کرنی تھی۔ اگر کبھی کوئی پریشانی ہو تو مجھے ضرور بتائیں، دُعا کے ساتھ دوا کرسکا تو مجھے دلی خوشی ہوگی‘‘۔
پروفیسر صاحب کو جتنا بھی قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ جذبے کی گہری آنچ رکھنے کے باوجود، غصّے اور جذبات سے کوئی کلمہ اُن کی زبان سے نہیں چھلکتا۔ اجتماعی زندگی کے معاملات پر واضح رائے رکھنے کے باوجود وہ کبھی نظم کی حد سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے بلکہ نظم اور تحریک کی پالیسی کے دفاع کے لیے بڑٰے توازن سے پوری قوت لگا دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ قائد تھے لیکن ان کے سراپے میں ایک بہترین صابر و شاکر کارکن متحرک تھا۔
مطالعے کے لیے راہ نمائی دیتے ہوئے فرماتے: ’’دینی لٹریچر کا آپ مطالعہ کرتے رہیں لیکن خاص طور پر اقبال کے کلام، خطوط اور نثری اثاثے کا مطالعہ کریں اور قائداعظم کی تقاریر اور خطوط کو بڑی توجہ، باریک بینی اور ترتیب سے پڑھیں۔ ان میں تاریخ اور رہنمائی بھی ہے اور ہمارے سماجی اُمور کو سمجھنے اور سلجھانے اور قانون کے راستے سے حل تلاش کرنے کا لائحہ عمل بھی‘‘۔ ایک روز فرمایا: ’’یاد رکھیں پاکستان کے بدخواہوں میں اتنی ہمت تو نہیں کہ اسلام اور پاکستان پر براہِ راست حملہ کرسکیں، مگر وہ اپنے مذموم مقصد کو پورا کرنے کے لیے اُوچھے اور گھٹیا ہتھکنڈے استعمال کرتے ہوئے اقبال، قائداعظم اور مولانا مودودی کو ہدف بناتے ہیں۔ اس لیے درست انداز سے حقائق کو پیش کرتے ہوئے ان کی مدافعت کے لیے ہروقت بیدار، تازہ دم اور متحرک رہیں‘‘۔
ایک روز فرمایا: ’’جولائی ۱۹۴۸ء میں مَیں نے لاہور میں کالج کی لائبریری میں ڈان سے قائداعظم کی تقریر پڑھی، جو انھوں نے اسٹیٹ بنک آف پاکستان کے افتتاح کے موقعے پر کی تھی۔ چونکہ میرا رجحان معاشیات پڑھنے کی طرف تھا، اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ اس تقریر کا مخاطب میں بھی ہوں، اور ساتھ ہی اسلامی معاشیات کے بارے موہوم سے سوالات اُٹھنے لگے۔ سال بھر کے بعد مولانا مودودی کے ہاں معاشیات کی اسلامی تفہیم و تشریح پڑھی تو دل ودماغ مکمل یکسوئی کے ساتھ اسلامی معاشیات سے وابستہ ہو گئے‘‘۔
یاد رہے قائداعظم نے یکم جولائی ۱۹۴۸ء کو کراچی میں اسٹیٹ بنک آف پاکستان کے افتتاح کے موقعے پر اپنی آخری تقریر میں فرمایا تھا: ’’معاشرتی اور معاشی زندگی کے اسلامی تصورات سے بنکاری کے نظام کو ہم آہنگ کرنے کے سلسلے میں آپ جو کام کریں گے، میں دلچسپی سے اس کا انتظار کروں گا۔ اس وقت مغربی معاشی نظام نے تقریباً ناقابلِ حل مسائل پیدا کر دیئے ہیں، اور شاید کوئی کرشمہ ہی دُنیا کو اس بربادی سے بچاسکے، جس کا اسے اس وقت سامنا ہے۔ یہ نظام افراد کے درمیان انصاف اور قوموں کے درمیان ناچاقی دُور کرنے میں ناکام ہوچکا ہے۔ مغربی دُنیا اس وقت میکانکی اور صنعتی اہلیت کے باوصف جس بدترین ابتری کا شکار ہے، وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔مغربی اقدار، نظریئے اور طریقے، خوش و خرم اور مطمئن قوم کی تشکیل کی منزل کے حصول میں ہماری مدد نہیں کرسکیں گے۔ ہمیں اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے اپنے ہی انداز میں کام کرنا ہوگا، اور دُنیا کے سامنے ایک ایسا اقتصادی نظام پیش کرنا ہوگا، جس کی اساس و بنیاد انسانی مساوات اور معاشرتی عدل کے سچّے اسلامی تصور پر کھڑی ہو۔ اس طرح ہم مسلمان کی حیثیت سے اپنا مقصد پورا کرسکیں گے، اور بنی نوع انسان تک امن کا پیغام پہنچا سکیں گے۔ صرف یہی راستہ انسانیت کو فلاح و بہبود اور مسرت و شادمانی سے ہمکنار کرسکتا ہے‘‘۔
اس طرح انٹرمیڈیٹ کے طالب علم خورشیداحمد نے اپنے قومی اور فکری قائدین سے، اپنے من کی دُنیا میں جو عہد کیا تھا، ساری زندگی اسی عہد کی تکمیل کے لیے تج دی۔ ۱۹۵۸ء میں اکنامکس پر پہلی کتاب Essays on Pakistan Economy لکھی اور ۱۹۶۱ء کو علی گڑھ یونی ورسٹی میں پروفیسر محمد نجات اللہ صدیقی کے نام خط لکھا: ’’کراچی یونی ورسٹی میں میرا تقرر ہوگیا ہے۔ Economic Planning اور Agricultural Economics پڑھا رہا ہوں۔ ’پلاننگ‘ کا پرچہ فائنل میں اور ’ایگریکلچرل‘ پر یویس میں۔ دُعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان نئی ذمہ داریوں کو اُٹھانے کی توفیق دے۔ پہلے بھی کام بہت تھے، اور اب تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ دو پرچوں [مراد ہیں اقبال اکادمی کا اُردو/ انگریزی Iqbal Review اور ماہ نامہ چراغِ راہ]کی ادارت، یونی ورسٹی، اجتماعی کام، ذاتی مصروفیات، ترجمہ و تالیف ___ خدا ہی ہمت دے اور ان کاموں کو بخیروخوبی انجام دلائے‘‘۔
سفرِشوق کی کٹھن راہوں پر چلتے ہوئے مسافر تھکا نہیں۔ ملازمت کے گوشے تک محدود رہنے کے بجائے اس طرزِفغآں کو پورے گلشن میں عام کرنے کے لیے مسلسل کوشش جاری رکھی، جس میں نوماہ جیل میں بھی گزارے، مگر نگاہیں منزل پر جمی رہیں۔ ۲۷؍اپریل ۱۹۶۸ء کو نجات اللہ صدیقی صاحب کو خط لکھا: ’’الحمدللہ، ہماری کوششوں سے ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، وہ یہ کہ کراچی اور پنجاب کی یونی ورسٹیوں نے ایم اے [اکنامکس] کی سطح پر Economics of Islam کا ایک پورا پرچہ ۱۰۰ نمبر کا متعارف کردیا ہے۔ آپ کو کراچی اور پنجاب کے سلیبس بھیج رہا ہوں، تاکہ آپ اس پر غور کرسکیں اور ہماری کچھ مدد کرسکیں‘‘۔
بعدازاں قومی اور عالمی سطح پر معاشیاتِ اسلام اور اسلامی بنکاری کے لیے کانفرنسوں، سیمیناروں کے انعقاد اور اداروں کی تشکیل و تعمیر، اور افراد سازی کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رکھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج مغربی علمی دُنیا انھیں ’فادر آف دی اسلامک اکنامکس‘ کے لقب سے یاد کرتی ہے۔
یہ ان کے لڑکپن کی بات ہے خورشید احمد صاحب، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا دستوری مسودہ تیار کرکے ارکان کو پیش کرنے والی سہ رکنی کمیٹی کے رکن تھے (دوسرے ارکان میں خرم مراد اور ظفر اسحاق انصاری شامل تھے)۔ خورشید صاحب نے بتایا: ’’جمعیت کے دستور کی تدوین کے وقت حلفِ رکنیت میں زندگی کے مقصد کے اظہارواعلان کے لیے جس قرآنی آیت کا انتخاب کیا گیا، وہ خرم بھائی اور راجا بھائی [ظفراسحاق]ہی کی تجویز کردہ تھی، اور جب انھوں نے تجویز کی تو اپنی کم علمی کے باوجود میری زبان سے بے ساختہ نکلا: ’میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ آیت مبارکہ ہے: اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلہِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۱۶۲ۙ (الانعام ۶:۱۶۲)’’کہو،میری نماز، میرے تمام مراسمِ عبودیت، میرا جینا اور مرنا، سب کچھ اللہ ربّ العالمین کے لیے ہے‘‘۔
پروفیسر صاحب نے اپنے دونوں مجوز ساتھیوں کی طرح اس عہد کو لکھا، پڑھا اور آخر دم تک نبھایا۔ اکتوبر ۲۰۱۶ء میں آنکھ کا آپریشن کرایا تو دائیں آنکھ ضائع ہوگئی لیکن اس تکلیف کے باوجود کمزور نظر اور محدب عدسے کی مدد سے مطالعہ کو جاری رکھا اور انتقال سے تین چار روز پہلے تک قلم سے رشتہ قائم رکھا___ دوسری تیسری کلاس کے بچّے نے مولانا مودودی کو جو نظم تحت اللفظ میں اور ہاتھ کے پُرجوش اشاروں کے ساتھ سنائی تھی، اس نظم کو اپنی زندگی کا ساز بنا لیا۔ اور پھر اس مغنی نے دُنیا کے گوشے گوشے میں اس نغمے کی گونج پھیلانے کے لیے تن من دھن لگادیا:
اسلام کا ہم سکّہ دُنیا پہ بٹھا دیں گے
توحید کی دُنیا میں اِک دھوم مچا دیں گے
اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے
اتنا ہی یہ اُبھرے گا، جتنا کہ دبا دیں گے
نتائج پیدا کرنا اللہ کی مشیت اور حکمت پر منحصر ہے، مگر شعوری طور پر زندگی لگادینا فرد کی ذمہ داری ہے۔ پھر لاہور میں قائداعظم کی آخری تقریر اخبار سے پڑھ کر جو عہد اپنے خالق سے باندھا تھا، پوری زندگی اس عہد کو نبھانے کے لیے وقف کر دی، جس کے روشن نقوش پوری دُنیا کی مالیاتی زندگی میں ایسے فرزانوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر علم کا علَم بلند کریں: مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاہَدُوا اللہَ عَلَيْہِ ۰ۚ فَمِنْہُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَہٗ وَمِنْہُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۰ۡۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا۲۳ۙ (احزاب ۳۳:۲۳) ’’اُن میں سے کوئی اپنی نذر پوری کرچکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ اُنھوں نے اپنے رویّے میں کوئی تبدیلی نہیں کی‘‘۔
پروفیسر خورشید احمد تحریک اسلامی کے اس قافلے کا آخری ستون تھے، جس قافلے کے سالار اور مجاہد اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرکے اللہ کے حکم پر ابدی دُنیا کو لوٹ گئے۔ وہ قافلہ جو فکر بھی تھا، طریقۂ زندگی بھی، جس نے سماجی اور اجتماعی زندگی کو ایک قرینہ عطا کیا ہے، جس قافلے نے طوفانوں کے سامنے کھڑا ہونے اور ایمانی و علمی اور منطقی اپروچ سے شائستگی و بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کا انداز سکھایا ہے، جس نے عددی قوت کی کمی کو کبھی نفسیاتی مسئلہ نہیں بننے دیا ہے اور اس کے ایک ایک فرد نے ہزار ہزار انسانوں کی سی عزیمت کو سر کا تاج بنایا۔ تربیت، تنظیم اور جہد ِ مسلسل کو زندگی اور زندگی کی معراج بنایا ہے۔ اس روایت کے آخری فرد تو بلاشبہ خاکی وجود میں خورشید احمد صاحب تھے،مگر الحمدللہ، وہ قافلہ نئے آہنگ اور نئے میدانوں میں ، نسلِ نو کے ساتھ معرکہ زن ہے ع
اِک روشنی کے ہاتھ میں ہے روشنی کا ہاتھ
اکثر دن کے تین سے چار بجے کے درمیان پروفیسر صاحب کے فون کا انتظار رہتا تھا۔ اب اس مہربان ہستی کا فون نہیں آئے گا۔دُنیا کی اسکرین سے بھی انسان اسی طرح چلا جاتا ہے، رہ جاتی ہے اس کی یاد اور صدقۂ جاریہ۔ کاش! ہم صدقۂ جاریہ بن سکیں اور مہلت ِ عمر کو اس دُنیا کی باثمر زندگی اور آخرت کی کامیابی زندگی بنا سکیں۔
خدا کا وجود اور مذہب انسانوں میں صدیوں سے موضوعِ بحث رہا ہے۔ اس ضمن میں کوریا کی ایک معروف یونی ورسٹی کے ایک پروفیسر اور ان کی ایک طالبہ کا مکالمہ یہاں مطالعے کے لیے پیش کررہا ہوں، جس کی تفصیل ایک پاکستانی طالبہ نے بھیجی ہے۔
پچاس سالہ پروفیسر اینڈریو بینٹ، جنوبی کوریا کی انتہائی معتبر یونی ورسٹی میں فلاسفی کے پروفیسر تھے، جو اپنی ذہانت اور حاضر جوابی میں بہت مشہور تھے اور اپنی زبان دانی، اور دلائل سے مخالف کو بے بس اور قائل بلکہ گھائل کردینے کے ماہر تھے۔ پروفیسر صاحب خدا کے وجود کے منکر تھے، اور اس ضمن میں وقتاً فوقتاً اپنے نظریات کا کلاس میں بھی کھل کر اظہار کیا کرتے تھے، جنھیں سن کر اکثر طلبہ وطالبات خاموش رہتے۔ کوئی بھی ان کے ساتھ بحث میں اُلجھنے کی جرأت نہ کرتا کیونکہ کوئی سٹوڈنٹ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بھری کلاس میں اس کی پَت اتر جائے اور کلاس فیلوز کے سامنے اس کی سبکی ہو۔
لیکن آخرکار اس بلاشرکت ِ غیرے گرفت رکھنے کا اقتدار چیلنج ہوگیا۔ پروفیسر اینڈریو کی کلاس میں ایک اٹھارہ سالہ طالبہ عائشہ بھی تھی، جس نے دو سال پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ عائشہ ایک خاموش طبع لڑکی تھی اور کلاس میں ہونے والے بحث مباحثوں میں کبھی حصّہ نہیں لیتی تھی۔ پروفیسر اینڈریو سے پنجہ آزمائی کرنے سے تو بڑے بڑے باتونی اور تیزطرار سٹوڈنٹ بھی گھبراتے تھے مگر اُس روز کلاس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک ایسا منظر جو کسی کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا۔
پروفیسراینڈریو نے کلاس میں آتے ہی اپنے من پسند موضوع خدا اور مذہب کی مخالفت پر بولنا شروع کردیا کہ ’’خدا کا تصوّر اور تمام مذاہب___ _ یہ سب انسانوں کی اپنی ایجاد ہیں۔ اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے انسانوں نے خدا کا تصوّر تخلیق کرلیا ہے‘‘۔ اپنے نظریے کے حق میں بات کرتے ہوئے پروفیسر اینڈریو نے طلبہ و طالبات سے سوالیہ انداز میں پوچھا: ’’اگر خدا موجود ہوتا تو دنیا میں اس قدر برائیاں کیوں ہوتیں اور انسان اس قدر تکلیفوں اور مصائب کا شکار کیوں ہوتے؟‘‘ پروفیسر نے اپنی بات کو دہرایا اور پھر کلاس کی جانب فاتحانہ انداز میں دیکھا۔ کلاس کی خاموشی کو پروفیسر اینڈریو نے اپنی دلیل کی فتح سمجھا مگر اچانک حیرت انگیز طور پر کلاس سے ایک ہاتھ کھڑا ہوا۔ سٹوڈنٹس کو مزید حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ ہاتھ انتہائی خاموش رہنے والی لڑکی عائشہ کا تھا۔
جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ عائشہ ایک خاموش طبع لڑکی تھی، جو اسلام قبول کرنے کے بعد اب اپنے کورس کے مطالعے کے بعد صرف قرآن اور اسلامک فلاسفی کو سمجھنے اور ذہن نشین کرنے میں مشغول رہتی تھی۔ پروفیسر نے اپنا سوال دُہرایا کہ ’’اگر کوئی خداموجود ہوتا تو دنیا میں اتنے دُکھ اور مصائب کیوں ہوتے؟ اور اگر خدا اتنا ہی انصاف پسند اور طاقت ور ہوتا تو انسانوں کو مصائب کا شکار نہ ہونے دیتا اور دنیا سے جہالت، جرائم اور برائیوں کا خاتمہ کردیتا‘‘۔ سب کی توقع کے برعکس عائشہ نے ہاتھ کھڑا کیا تو پوری کلاس حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کلاس کے تمام طلبہ و طالبات حیران تھے کہ یہ بے زبان سی لڑکی آخر کس اعتماد کی بنیاد پر ڈاکٹر اینڈریو جیسے کایاں شخص سے اُلجھنے کی جرأت کررہی ہے؟ ابھی ایک منٹ میں پروفیسر اسے لاجواب ہی نہیں بے عزّت کرکے رکھ دے گا۔ کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا تیز طرار سٹوڈنٹ بھی پروفیسر کو شکست تو کیا اس کے ساتھ اختلاف یا بحث کرنے کی کبھی جرأت نہیں کر سکا تھا۔ اس پس منظر میں عائشہ کا ہاتھ کھڑا کرنا واقعی حیران کن تھا۔ پروفیسر نے بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا:’’ہاں، عائشہ بتائو کیا جواب ہے تمھارا؟‘‘
عائشہ نے کہا:’’سر! آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟‘‘ پروفیسر نے تکبّر اور خوداعتمادی سے گندھی ہوئی آواز میں کچھ زیادہ ہی بلند آواز میں کہا:’’ہاں ہاں، ضرور پوچھو‘‘۔ اس پر عائشہ بولی:’’سر! کیا یہ درست ہے کہ ہم انسانوں کو کوئی بھی فعل اور عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے؟‘‘پروفیسر نے کہا:’’ہاں، بالکل ہمارے پاس reason and freedom (شعور اور آزادی) ہے اور ہم اسی شعور اور آزادی کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنے میں بااختیار ہیں‘‘۔
اس پر عائشہ نے اعتماد کے ساتھ کہا: ’’سر! آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اب یہ بھی بتادیں کہ اگر معاشرے میں پوری سمجھ، شعور اور آزادی کے ساتھ کوئی شخص جرم کرتا ہے، کسی کو قتل کردیتا ہے یا بہت بڑا فراڈ کرکے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو کیا ہم اس جرم یا برائی کا ذمّہ دار اُس شخص کو قراردیں گے یا وہاں کے لیگل سسٹم پر اس کی ذمّہ داری ڈال دیں گے؟‘‘
پروفیسر نے فوراً جواب دیا:’’سسٹم ذمہ دار نہیں ہوگا، جرم کرنے والا فرد ہی ذمہ دار ہوگا۔ لیگل سسٹم تو ہمیں راہ نمائی فراہم کرتا ہے۔ جرم کا ارتکاب تو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں‘‘۔ اب عائشہ نے اور زیادہ پُراعتماد لہجے میں کہا:’’سر! اگر معاشرے میں ہونے والے جرائم کی ذمہ داری ہم جرم کا ارتکاب کرنے والے شخص پر ڈالتے ہیں اور سسٹم کو اس کا ذمّہ دار قرار نہیں دیتے تو دنیا میں ہونے والی برائیوں کی ذمّہ داری برائیوں کا ارتکاب کرنے والے افراد کے بجائے خدا پر کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کیا اس کے ذمہ دار برائیوں کا ارتکاب کرنے والے افراد نہیں ہیں؟ ‘‘
سٹوڈنٹس اس مکالمے کو پوری توجہ سے سننے کے لیے دم بخود ہوگئے اور پروفیسر اینڈریو کی خوداعتمادی پہلی بار تھوڑی سی ڈگمگاگئی، مگر اس نے اپنا اعتماد قائم رکھتے ہوئے ایک اور سوال داغ دیا:’’مگر یہ کیسا خدا ہے جس نے دنیا کو اچھائیوں کے بجائے برائیوں (evils) سے بھر دیا ہے؟‘‘
عائشہ نے کہا:’’پروفیسر صاحب! ہم برائیوں کو نہ دیکھتے تو اچھائیوں سے لاعلم رہتے، ہمیں اچھائیوں کی اہمیّت کا اندازہ ہی برائیاں دیکھ کر ہوا ہے‘‘۔
یہ سن کر پروفیسر بولا :’’ٹھیک ہے مگر یہ وبائیں، طوفان، زلزلے اور آسمانی آفتیں جن سے ہزاروں انسان ہلاک ہوجاتے ہیں، یہ ہلاکتیں اور تباہ کاریاں تو انسانوں کی لائی ہوئی نہیں ہیں۔ اگر کوئی خدا ہوتا تو انسانوں کو ان ہلاکتوں اور مصائب میں کیوں مبتلا کرتا؟‘‘ اس پر طالبہ نے جواب دیا: ’’سر، آپ جانتے ہوں گے کہ بہت سے ڈاکٹر مریضوں کے لیے ایسی دوائیاں تجویز کرتے ہیں، جو بہت کڑوی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایسے انجکشن دیتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں‘‘۔
پروفیسر نے کہا:’’ہاں، میں خود بہت کڑوی دوائیاں کھاتا رہا ہوں اور بہت ہی تکلیف دہ ٹیکے لگواتا رہا ہوں‘‘۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا:’’پروفیسر صاحب، آپ تسلیم کریں گے کہ ڈاکٹر کڑوی دوائیاں اور تکلیف دہ ٹیکے اپنے مریضوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں دیتے بلکہ ان کے علاج اور صحت یابی کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ یہ ابتلائیں، مصائب، اور صدمے ڈاکٹر کے تکلیف دہ ٹیکوں کی طرح انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتے۔ تکلیف انسان کو صبر اور حوصلہ سکھاتی ہے، دکھ انسانی شخصیّت کی نشوونما کرتے ہیں اور مصائب سے انسانوں کی تکمیل ہوتی ہے‘‘۔ کلاس کے طلبہ سے ایک آواز بلند ہوئی: ’’واہ، بہت خوب دلیل ہے‘‘۔ مگر پروفیسر اینڈریو جیسا شخص اپنی ایک طالبہ سے شکست کیوں مان لیتا۔ لہٰذا اس نے کہا:’’اگر خدا ہوتا تو وہ ایک perfect world تخلیق کرتا جو جرائم، مصائب اور تکلیفوں سے پاک ہوتی‘‘۔ عائشہ نے استاد سے پوچھا: ’’پروفیسر صاحب، آپ ادبی کتابیں پڑھتے ہیں؟‘‘ پروفیسر نے کہا :’’ہاں، میں انسانی زندگی کے بارے میں کہانیاں اور ناول دلچسپی کے ساتھ پڑھتا ہوں‘‘۔ عائشہ نے یہ سن کر سوال کیا: ’’پروفیسر صاحب! کیا آپ کو انسانی زندگی کی ایسی کہانیاں پسند ہیں جن میں کوئی موڑ، کوئی مشکل اور کوئی چیلنج نہ ہو۔ ہیرو صاف اور سپاٹ سڑک پر سفر کرتا ہوا اپنے طے شدہ وقت پر منزل پر پہنچ جائے، یا آپ کو ایسے ناول پسند ہیں جس میں راستہ کٹھن ہو، جرم بھی ہو، تصادم بھی ہو، غیر متوقع چیلنجز بھی ہوں اور کرداروں کو مصائب اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے، اور دکھ بھی سہنے پڑیں؟‘‘ پروفیسر نے کہا: ’’کتاب تووہی دلچسپ ہوگی جس میں جرائم بھی ہوں، مشکلات بھی ہوںاور چیلنج بھی ہوں‘‘۔
عائشہ نے جواب میں کہا:’’بس زندگی کے خالق نے بھی اسے سیدھا اور سپاٹ رکھنے کے بجائے اس میں اُونچ نیچ، مشکلات اور چیلنج ڈال کر اسے سبق آموز اور دلچسپ بنادیا ہے۔ مصائب ہمارے اندر صبر اور انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ صدمات اور چیلنج انسانوں میں مشکل حالات پر قابو پانے کی ہمت (resilience) پیدا کرتے ہیں۔ مشکلات اور آلام نہ ہوں تو انسان میں ان سے نبرد آزما ہونے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہی نہیں ہوسکتی۔ ان چیلنجوں کے بغیر تو انسان کو زندگی کے صحیح معانی ہی معلوم نہیں ہوسکتے‘‘۔ پروفیسر کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا: ’’اچھا تو خدا نے زندگی کی کہانی دلچسپ بنانے کے لیے انسانوں کو ان دکھوں اور مصائب میں مبتلا کیا ہے؟‘‘ نہیں، خدا کے نزدیک زندگی ایک کہانی نہیں ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے‘‘، عائشہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔’’خالق نے اپنی واضح نشانیاں دکھا دی ہیں جو شعور رکھنے والے انسانوں کو سچائی تک یعنی خدا کے وجود تک پہنچنے میں راہ نمائی کرتی ہیں‘‘۔ اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔
پروفیسر نے جھنجلا کر ایک اور سخت وار کیا:’’ٹھیک ہے، اگر خدا واقعی ہے تو لوگ اس کے وجود سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ ‘‘۔ طالبہ نے سوال سنا اور معمولی توقف کے بعد کہا:’’پروفیسر صاحب! آپ یہ بتائیے کہ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہے، اس کے باوجود کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس غلط اور نقصان دہ عادت کو اپنائے ہوئے ہیں اور دن رات سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ وہ یہ نقصان دہ عمل کیوں کرتے ہیں؟‘‘فلسفے کے ماہر پروفیسر نے جواب دیا: ’’اس لیے کہ انھیں کوئی بھی عمل کرنے کا اختیار ہے، اور وہ اس اختیار کو وقتی خوشی یا لذّت کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں‘‘۔’’آپ نے بالکل درست کہا پروفیسر صاحب‘‘۔ عائشہ نے آواز قدرے بلند کرتے ہوئے کہا: ’’آپ نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ انسان اپنا اختیار (choice) ہمیشہ درست طور پر استعمال نہیں کرتے، وقتی لذّت، لطف، خوشی یا مفاد کے لیے وہ اس اختیار اور آزادی کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں اور ایک غلط اور نقصان دہ راستے پر بھی چل پڑتے ہیں۔ سچائی کو ماننا یا نہ ماننا بھی ہمارے اختیار یا انتخاب کا معاملہ ہے اور ہمارا انتخاب غلط بھی ہوسکتا ہے‘‘۔
اب کلاس کے طالب علموں کی اکثریت عائشہ کو ستائش کی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ مگر منطق اور دلیل کا ماہر پروفیسر اپنی ہی ایک سٹوڈنٹ سے شکست کھانے کو تیار نہ تھا، لہٰذا اس نے ایک اور تیرچلایا: ’’اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اس نے اپنے آپ کو مخفی کیوں رکھا ہوا ہے؟‘‘
طالبہ نے نپے تلے الفاظ میں جواب دیا:’’پروفیسر صاحب، جب خدا نے پردہ اٹھادیا اور اپنے آپ کو ظاہر کردیا، تو اُس دن امتحان ختم ہوجائے گا۔ اور امتحان کے ساتھ ہی دنیا کا بھی خاتمہ ہوجائے گا‘‘۔ پھر ایک وقفے کے بعد عائشہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا: ’’مگر کیا شعور رکھنے والوں کو اپنے آس پاس خدا کی واضح نشانیاں نظر نہیں آتیں؟ خدا اپنی نازل کی گئی کتاب قرآنِ مجید میں خود بار بار کہتا ہے کہ میری تخلیقات پر غور کرو، عقل اور شعور استعمال کرکے میری نشانیوں کے ذریعے مجھے تلاش کرو۔ تمھیں سچائی نظر آجائے گی۔ پروفیسر صاحب، خدا کے منکروں کا نظریہ کس قدر کھوکھلا ہے۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز مادّے سے پیدا ہوئی ہے مگر مادّے میں جان کس نے پیدا کی، ذرّے کو زندگی کس نے بخشی ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر یہ کہ جب مادّے میں جان پڑگئی اور نباتات اور حیوانات وجود میں آگئے تو ان میں سے ایک جانور کو شعور دے کر انسان کس نے بنایا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ محض یہ کہہ دینا کہ فطرت (Nature) خود بخود تخلیق کرتی ہے۔ ایک غیر عقلی اور غیر منطقی بات ہے۔ صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی فنکشنل چیز اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی۔ وہ پوری دنیا میں کوئی ایک عمارت، ایک پُل ایک پرندہ یا کوئی ایک مشین بتادیں جو خود بخود بن گئی ہو۔ Evolution (ارتقا)کے نظرئیے کے حق میں آج تک کوئی ایک معمولی سی شہادت بھی پیش نہیں کی جاسکی‘‘۔
اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا: ’’دوسری جانب جب خدا کہتا ہے کہ یہ کائنات اور انسان میں نے تخلیق کیے ہیں اور سورج اور چاند اور ہر چیز کو تمھارے لیے مسخر کردیا ہے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ دنیا میں ہر وہ سامان بہم پہنچادیا گیا ہے، جو انسانی زندگی کی بقا اور نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ کیا کوئی معمولی سی عقل رکھنے والا شخص بھی یہ مان سکتا ہے کہ سورج اور چاند خودبخود پیدا ہوگئے اور خودبخود صدیوں سے اعلیٰ ترین درجے کی precision [درستی]کے ساتھ اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور اپنا دیا گیا ٹاسک پورا کررہے ہیں؟ انسانی جسم کے اندر چلنے والے حیرت انگیز سسٹمز بھی پکار پکار کر کسی عظیم خالق کے ہونے کی شہادت دے رہے ہیں۔ انسان کے اعضاء مثلاً آنکھیں، ناک، کان، دل، جگر، آنتیں، ہر عضو کا مخصوص فریضہ اور ڈیوٹی ہے اور جس عضو کو جہاں ہونا چاہیے تھا اسے وہیں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے خدا نے انسان کو اپنی Best of Creations (تخلیق کا شاہکار) قرار دیا ہے۔ استاد محترم، میرا آپ سے سوال ہے کہ انسانی جسم کا حیرت انگیز سسٹم اور اس کے اندر چلنے والے کارخانے، کیا یہ سب اپنے آپ بن گئے ہیں؟ کیا آپ کا شعور اور عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے؟ نہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ اپنے آپ نہیں بن سکتا، یہ کسی بہت طاقت ور ہستی کی قوّتِ تخلیق کا شاہکار ہے‘‘۔
کلاس میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ مگر یہ واضح تھا کہ طلبہ و طالبات عائشہ کی باتوں کا اثر قبول کررہے ہیں، اور پروفیسر شکست ماننے کے لیے تیّار نہیں تھا، اس کے ترکش میں ابھی چند تیر باقی تھے۔ اس نے ایک اور تیر پھینکا :’’جیسا تم کہہ رہی ہو کہ خدا بڑا عظیم بھی ہے اور وہ انسانوں کا خیرخواہ بھی ہے تو پھر ہمیں دنیا میں unreasonable sufferings (نامناسب خرابیاں اور زیادتیاں)کیوں نظر آتی ہیں؟ اتنی بڑی تعداد میں معذور بچے کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟‘‘ عائشہ نے پورے سکون سے جواب میں کہا: ’’پروفیسر صاحب، آپ ایک لیجنڈری ہستی ہیلن کیلر کو تو جانتے ہوں گے‘‘۔ ’’ہاں ہاں، وہی نابینا اور بہری خاتون۔ جو بہت بڑی رائٹر بن گئی تھی‘‘، پروفیسر نے جواب دیا۔ عائشہ نے کہا: ’’جی وہی ہیلن کیلر جس نے اپنی معذوری کو نہ اپنی کمزوری بننے دیا اور نہ کبھی گلہ کیا بلکہ اس نے اپنی معذوری کو اپنی طاقت بنالیا اور کروڑوں معذور انسانوں کو ہمت اور حوصلہ دیا۔ہیلن کیلر کہا کرتی تھیں کہ سُکھ بھرا خوشگوار سفر نہیں___ بلکہ دکھوں سے لبریز کٹھن راستہ ہی انسانی کردار کو مضبوط کرتا اور کندن بناتا ہے‘‘۔ کلاس کے تمام سٹوڈنٹس ہمہ تن گوش تھے اور لیکچر روم اب مکمل طور پر عائشہ کی گرفت میں تھا۔ پروفیسر کا تکبّر ریزہ ریزہ ہوچکا تھا اور ہر طالب علم محسوس کررہا تھا کہ پروفیسر بھی عائشہ کی پُراثر باتوں سے کافی متاثر ہوچکا ہے۔
پروفیسر نے آخری سوال پوچھا:’’اچھا یہ بتائو تمھیں خدا کے وجود پر کیسے اس قدر یقین ہے؟‘‘ عائشہ نے اسی پُرسکون لہجے میں جواب دیا: ’’اس لیے کہ میں اپنے خالق کو محسوس کرتی ہوں۔ دماغ سے ہی نہیں، دل سے بھی خدا کو دیکھتی اور محسوس کرتی ہوں۔ میں جب نماز میں اپنے خالق سے ہمکلام ہوتی ہوں، جب اُس سے کوئی دعا مانگتی ہوں، جب پریشانیوں میں گھِرکر اسے پکارتی ہوں تو مجھے جواب مل جاتا ہے۔ مجھے سکون اور دلی اطمینان نصیب ہوجاتا ہے‘‘۔
پروفیسر نے بظاہر مسکراتے مگر شکست خوردہ لہجے میں کہا: ’’مگر مجھے روشنی کیوں نہیں مل سکی؟ مجھے خدا کیوں نہیں ملا؟‘‘ عائشہ بولی: ’’اس لیے کہ آپ نے اس کی تلاش میں صرف فلسفیانہ اور منطقی راستے اختیار کیے ہیں،جب کہ ایک اور راستہ بھی ہے۔ اور وہ ہے دل کا راستہ۔ اسے اختیار کریں وہ آپ کو سچائی اور حقیقت کی منزل تک ضرور پہنچائے گا‘‘۔
پروفیسر نے اپنے دل کے اردگرد نفرت اور تعصب کی جو مضبوط دیواریں کھڑی کی تھیں، ان میں دراڑ پڑچکی تھی۔ اس کا فلسفہ اور منطق ایک نوعمر لڑکی کی پُراخلاص باتوں کے آگے ڈھیر ہوچکا تھا۔ وہ دل شکستہ ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کی تھکی سی آواز اُبھری: ’’آپ جاسکتے ہیں‘‘۔
اسلامی تعلیمات تجارت میں بلا امتیازاورمنصفانہ مسابقت کا درس دیتی ہیں اور نجی کاروبار پر کوئی پابندی نہیں لگاتیں۔ تاہم، ان تعلیمات میں مفاد عامہ کو فوقیت حاصل ہے اور ہر وہ تجارتی ہدف اور لین دین جو ان تعلیمات سے متصادم ہو گا اور چند افراد یا کسی مخصوص گروہ کے لیے تو فائدہ مند ہو لیکن اس سے عوام کی بڑی اکثریت کے حقوق مجروح ہوتے ہوں، قابلِ گرفت ہے۔ ان متعین شدہ اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے موضوع کے مطابق پہلے پاکستان کے صنعتی سفر پر بات کریں گے اور ان کمزوریوں کا جائزہ لیں گے جو اس میدان میں ہمیں درپیش رہیں۔ بعد ازاں ماضی کے تجربات کی روشنی میں تجاویز پیش کی جائیں گی جن میں بالخصوص نجکاری کو زیرِ بحث لایا گیا ہے۔
ریاستی اداروں کی نجکاری کو دنیا کےکئی ممالک معیشت کو تقویت دینے اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے نسخۂ کیمیا سمجھ کر اپناتے رہے ہیں۔ یہ رجحان بلا استثناء مغربی اور مشرقی بلاک کے ممالک، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک، غرض ہر طرف دیکھا جاسکتا ہے۔ ہمارے لیے اس ضمن میں ان ممالک کے تجربوں کی طرف دیکھنا زیادہ مناسب ہوگا جو ہمارے ملک سے اپنی ترقی، اپنی معیشت کے حجم اور اپنے نظام اور اندازِ حکومت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوں۔ اس میں ارجنٹائن، یونان اور نائجیریا شاید ہمارے لیے موزوں مثالیں ہوں گی، بجائے اس کے کہ ہم امریکا، برطانیہ اور چین جیسے ممالک سے اپنا موازنہ کریں۔ ارجنٹائن چند سال قبل اپنے اقتصادی بحران کے سبب دیوالیہ ہو گیا تھا، جب کہ یونان یورپین یونین کے بیل آوٹ پیکج کی بنا پر دیوالیہ ہونے سے بچ گیا تھا۔ ان دونوں ممالک میں بڑے پیمانے پر نجکاری کے تجربات ناکام ثابت ہوئے۔ نائجیریا اپنے تیل کے ذخائر اور پیداوار کی بناء پر نسبتاً محفوظ رہا، تاہم نجکاری کے نتیجے میں ایک عام آدمی کے حالاتِ زندگی بہتر نہ ہو سکے۔ نائجیریا اپنی ضروریات کی اکثر اشیاء درآمد کرتا ہے، اس کے اہم شہر اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں اور تیل اور گیس کا شعبہ کرپشن کی آماجگاہ ہے۔ بڑے پیمانے پر پیش رفت کے باوجود اس خواب کی تعبیران تینوں ممالک نے نہیں دیکھی۔
۱۹۴۷ء میں بر صغیر کا وہ حصہ جو دنیا کے نقشے پر اسلامی جمہوریۂ پاکستان بن کر نمودار ہوا، وہ بنیادی صنعتی ڈھانچے سے تقریباً محروم تھا۔ ۱۹۵۰ء کی دہائی میں صنعتی ترقی کے ابتدائی دور میں سرکاری شعبے کے ساتھ ساتھ نجی صنعت کاروں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ سرکاری شعبے میں نئی اور جدید صنعتوں کا قیام زیادہ تر پاکستان انڈسٹریل ڈویلپمنٹ کارپوریشن (PIDC) کے ذریعے عمل میں آیا۔ اس وقت زیادہ تر نجی کاروباری ادارے بڑے پیمانے پر مادی اور مالی وسائل فراہم کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، جب کہ نوزائیدہ ملک میں بنیادی صنعتوں کے فقدان کی وجہ سے اشیائے خورد و نوش، تجارتی سرمائے اور سروسز کی بڑھتی ہوئی مانگ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس خلاء کو پُر کرنے کے لیے ملک کی ابتدائی قیادت نے مالیاتی اور صنعتی ادارے قائم کیے۔
ملک نے صنعتی ڈھانچے کی تعمیر میں نمایاں تیزی دکھائی، PIDC نے ۱۹۵۲ء سے شروع ہونے والے دور میں معیشت کے اہم شعبوں جیسے کھاد، سیمنٹ، کیمیکلز، چینی، دوا سازی، ٹیکسٹائل، کاغذ، اُون اور جوٹ میں ۹۴ صنعتی یونٹ قائم کیے۔ مغربی پاکستان میں ۷۳ اور مشرقی پاکستان میں ۲۱ یونٹ قائم کیے گئے۔ مغربی پاکستان کے ۷۳ یونٹوں میں سے ۲۹ پنجاب، ۱۹سندھ، ۱۷شمال مغربی سرحدی صوبے (خیبرپختونخوا) اور ۸ بلوچستان کے علاقوں میں واقع تھے۔ نجی شعبے نے زیادہ تر کراچی میں صنعتیں قائم کیں، یہ بندرگاہی شہر انفراسٹرکچر کی دستیابی اور ایک نمایاں صنعتی افرادی قوت کی موجودگی کے باعث نجی سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ پُرکشش تھا۔ کراچی پاکستان کا صنعتی اور اقتصادی مرکز ہونے کا درجہ رکھتا ہے۔ تاہم ۲۰۱۹ء کے Global Livability Index کے مطابق، کراچی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے معیار میں اب تنزلی پا کرآخری دس شہروں میں شامل ہو گیا ہے۔
ابتدائی دور میں صنعتی یونٹوں کا قیام زیادہ تر مقامی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے کیا گیا تھا، تاکہ غیر ملکی زرِ مبادلہ کی قلت اور برآمدات کی کمی کے پیش نظر بیرونِ ملک سے اشیاء کی درآمد میں کمی لائی جائے۔ کیونکہ مقامی مسابقت کم تھی اور درآمد شدہ اشیاء مہنگی تھیں، اس دور میں نجی کاروباری ادارو ں کے لیے سرمایہ کاری کے اچھے مواقع موجود رہے۔ نجی اور سرکاری دونوں ہی شعبوں نے نئے ملک کے لیے ضروری صنعتی بنیاد کے قیام میں اپنا حصہ ڈالا۔
بعدازاں، سرد جنگ کے ابتدائی دور میں، جب پاکستان نے مغرب کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دی، تو وہاں سے مالی امداد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دور میں زیادہ تر دیہی اور زرعی ترقی پر توجہ مرکوز رکھی گئی۔ شاید صنعتوں کےفروغ نہ پانے میں یہ خوف بھی کارفرما رہا ہو کہ سرد جنگ کے اس دور میں بائیں بازو کی تحاریک عام طور پر صنعتی اداروں سے متعلقہ مزدور طبقے سے منسلک سمجھی جاتی تھیں۔ مزید یہ کہ دیہی علاقوں سے فوج کے لیے بھرتیوں کو یقینی بنانا بھی پیش نظر رہا ہوگا۔ وہ علاقے جو تقسیمِ ہند کے بعد مغربی پاکستان بنے تھے، سپاہ کی فراہمی کے لیے ایک روا یتی مرکز (مارشل بیلٹ) کے طور پر جانے جاتے تھے اور دونوں عظیم عالمی جنگوں میں اس اعتبار سے اہم کردار ادا کرچکے تھے۔
صنعت کاری کے فروغ کے لیے ریاستی منصوبوں کے ساتھ نجی شعبہ بھی اہم ہوتا ہے، اور حکومت اس سرگرمی کو فروغ دینے کے لیے پالیسیاں بناتی ہے اور سرکاری اداروں کے ذریعے سہولیات فراہم کرتی ہے۔ نجی صنعت کاروں کو حکومتی قرضے فراہم کرنے کی غرض سے پاکستان میں کئی سرکاری ادارے قائم کیے گئے، تاہم ساری ہی کوششیں کرپشن، اقربا پروری، قرضوں کی عدم ادائیگی اور حکومتی و سیاسی مداخلت کے باعث ناکام ہوئیں، خصوصاً چھوٹے صنعت کاروں کے لیے قرضے فراہم کرنے کا کوئی مؤثر نظام قائم نہ ہو سکا۔ ان ناکامیوں کے سبب پاکستان میں نجی صنعتی سرمایہ کاری یہاں موجود روشن امکانات کے مطابق فروغ نہ پا سکی۔ یہ خلا آج بھی نجی شعبے کے کل حجم اور مصنوعات و سروسز کے معیارکے اعتبار سے موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر نئے پروگرام ترتیب دیے جائیں ورنہ آج کے نیشنل انکیوبیشن سینٹرز NICs ہوں یا بزنس انکیوبیشن سینٹرز (BICs) یا ان جیسے دیگر پروگرام، وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے جن سے ماضی کے سہولتی پروگرام دوچار ہوئے۔
ایک عرصے تک پاکستان میں بھاری صنعت کے حوالے سے کسی قابلِ ذکر ترقی کا آغاز نہیں ہوا۔ ایک اہم پیش رفت ۱۹۶۰ء کے دوسرے عشرے کے دوسرے نصف میں ہوئی، جب کراچی اسٹیل ملز (پاکستان اسٹیل) کا قیام عمل میں آیا۔ یہ منصوبہ اشتراکی روس کی مدد سے قائم کیا گیا تھا۔بھاری صنعت کی جانب اگلا بڑا قدم ۱۹۷۰ء کی دہائی میں چین کی مدد سے اٹھا یا گیا، جب ٹیکسلا اور کامرہ میں بھاری صنعتی کمپلیکس قائم کیے گئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ زیادہ تر صنعتی ترقی دفاعی پیداوار کے میدان میں رہی۔ پاکستان نے آزادی کے فوراً بعد واہ آرڈیننس فیکٹری جیسی دفاعی پیداوار کی اہم صنعت قائم کر لی تھی۔
کئی اہم شعبوں میں فوج کے ذیلی اداروں نے قدم جمائے۔ مثلاً توانائی کے شعبے میں ماری انرجی میں فوجی فاؤنڈیشن ۴۰ فی صد کے ساتھ سب سے بڑا حصے دار ہونے کے ساتھ انتظامی اُمور پر قادر ہے۔ ایف ڈبلیو او (FWO)جو ملٹری اور سویلین انفرا اسٹکچر کے شعبے میں ایک اہم فوجی ادارہ ہے اور اب یہ ادارہ معدنیات کے شعبے میں بھی قدم رکھ چکا ہے۔ این ایل سی (NLC)ایک قومی ادارہ ہے جو ملک میں اشیاء کے نقل و حمل، لاجسٹک سروسز کے علاوہ انفرا اسٹرکچر کی تعمیرات میں اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ ادارہ بھی بنیادی طور پر فوج کے زیر انتظام ہے۔ حال ہی میں ایس آئی ایف سی کی کوششوں سے این ایل سی نے ڈی پی ورلڈ لاجسٹک ایف زیڈ ای کے ۶۰ فی صد حصص حاصل کرنے کے لیے ’کمپیٹیشن کمیشن پاکستان‘ (CCP)کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ یوں اس ادارے کی توسیع کا عمل جاری ہے۔ ۲۰۱۰ء میں این ایل سی کا ایک کرپشن سکینڈل منظرعام پر آیا جس میں فوج کے اعلیٰ افسران ملوث پائے گئے تھے۔ یہ کہانی نہ نئی ہے نہ انوکھی، دنیا کے کئی ممالک اپنے بجٹ پر دفاعی اخراجات کا بوجھ کم کرنے کی غرض سے عسکری اداروں کے صنعتی اور دیگر شعبوں میں حصہ لینے پر کوئی پابندی نہیں لگاتے۔ تاہم، ان اداروں میں پروفیشنلزم کو یقینی بنائے بغیر بہتر نتائج کی توقع کرنا بے سود ہے۔ مزید یہ کہ ایک مستعد مانیٹرنگ سسٹم ہی کسی ادارے کو کرپشن سے دور رکھنے میں کارگر ہوتا ہے۔ یہ بھی کہ ان اداروں کو اپنے اثر ورسوخ کی بنیاد پر اجارہ داری قائم کرنے کی کسی طور آزادی نہ ہو، ایک بلا امتیاز مسابقت کا ماحول سب ہی کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔
’آرمی ویلفیئرٹرسٹ‘، ’فوجی فاؤنڈیشن‘، ’بحریہ فاؤنڈیشن‘ اور ’شاہین فاؤنڈیشن‘ جیسے فوج کے ذیلی اداروں کے تحت متعدد صنعتی ادارے اور منصوبے چلتے ہیں۔ ۲۰۱۵ء میں سینیٹ کی ایک کمیٹی میں ایسے ۵۰ تجارتی اداروں کی تفصیل پیش کی گئی تھی جو ایسے اداروں کے تحت چلتے ہیں (جن میں اب یقیناً خاصہ اضافہ ہو چکا ہے)، اس میں ہاؤسنگ اسکیمیں سر فہرست ہیں۔ تفصیل کے لیے روزنامہ ڈان کی اس رپورٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر عسکری سرپرستی میں چلنے والے اداروں کو چند مخصوص متعلقہ شعبہ جات میں کام کرنے کی آزادی ہو تو یہ ہماری رائے میں بہتر ماڈل ثابت ہوگا۔ دفاعی پیداواراور بعض دیگر حسّاس ادارے اس کی مثال ہیں، تاہم ان میں بھی اجارہ داری کے رجحان کو روکا جانا اور نجی شعبے کو مسابقت کے مواقع دینا قومی مفاد میں ہوگا۔ چند ایسے شعبے بھی ہیں جو سول اور عسکری دونوں میدانوں کے لیے یکساں ضروری ہیں اور ایسے شعبوں میں چین کے ملٹری سویلین فیوژن (MCF) پروگرام کی طرز کا ماڈل دونوں میدانوں میں ترقی کو تیز تر کرسکتا ہے۔ اس میں آئی ٹی، جہاز سازی، ایرو اسپیس وغیرہ کے شعبہ جات شامل ہو سکتے ہیں۔
بھاری صنعتوں میں کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ بھی ایک قابلِ ذکر صنعتی ادارہ ہے جو وزارت دفاع کے تحت ہے، جسے آزادی کے فوراً بعد قائم کیا گیا تھا۔ اسی طرح آزادی کے بعد پاکستان کو ملنے والی لاہور کی مغلپورہ ورکشاپ بھی اہم ہے۔ پاکستان مشین ٹول فیکٹری ۱۹۶۸ء میں سویٹزرلینڈ کی ایک پرائیویٹ کمپنی کے تکنیکی تعاون سے قائم ہوئی جو پاکستان کی صنعتی بنیاد کے لیے اہم تھی۔ ۱۹۷۵ء میں اسے کمپنیز ایکٹ کے تحت پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا درجہ دے دیا گیا۔ بعد ازاں دیگر کئی اہم صنعتی اداروں کی طرح جن میں ہیوی مکینیکل کمپلیکس، پیپلز اسٹیل ملز (اپنے اسی نام کے ساتھ) شامل ہیں، ایس پی ڈی کے تحت فوج کی تحویل میں چلے گئے۔ پی آئی اے کے تحت قائم ہونے والا ادارہ پریسیشن انجینئرنگ ۲۰۲۴ء میں پاک فضائیہ کے تحت ہوگیا۔ ان اداروں کے علاوہ کئی اور سرکاری ادارے فوج کے ریٹائرڈ افسران کی زیرِ نگرانی چل رہے ہیں۔ فوجی اپنی تربیت کے اعتبار سے اچھے ایڈمنسٹریٹر تو ہو سکتے ہیں، تاہم منیجمنٹ دراصل ایڈمنسٹریشن سے مختلف میدان ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کے بہتر تکنیکی اور اقتصادی ماہرین کی قیادت اور نگرانی میں ان اداروں کو حکومتی، عسکری اور سیاسی عدم مداخلت کی شرط کے ساتھ بہت فعال اور منافع بخش ادارے بنایا جاسکتا ہے۔ غالباً فوجی قیادت نے اسی سوچ کے پیش نظر اپنے زیرانتظام چلنے والے کئی اداروں کا نظم و نسق اب پروفیشنل سویلین قیادت کو سونپ دیا ہے۔
جن بھاری صنعتی شعبوں میں خاص طور پر پاکستان پیچھے رہا، ان میں آٹوموبائل، الیکٹرونکس، مائننگ اور زرعی مشینری سے متعلقہ صنعتیں شامل ہیں۔ یہ ایک ناقابلِ فہم بات ہے کہ ارضیاتی اعتبار سے بعض اہم معدنیات کے لیے موافق خطے میں موجود ہونے کے باوجود اس جانب خاطرخواہ توجہ نہیں دی گئی۔ پچھلے چند برسوں میں ریکوڈک اور تھر کول کے منصوبوں میں سرکار کی جانب سے فاش غلطیوں کے سبب جب یہ منصوبے عوامی بحث کا موضوع بنے، اس کے بعد ہی معدنیات کی جانب توجہ ہوئی۔ تاہم، اب تک اس شعبے کو ایک انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا جا سکا ہے اور اس سے متعلقہ صنعتیں بہت کم اور فرسودہ ہیں۔ اس بنا پر ہم اپنی بیش قیمت معدنیات کم قیمت پر خام شکل میں برآمد کر دیتے ہیں۔ ۲۰۲۵ء کی منرل پالیسی حال ہی میں پیش کی گئی ہے اور ابھی اس کے خدوخال واضح ہونا باقی ہیں۔ اس سلسلے میں صوبوں اور مرکز کے رول کو اس شعبے میں واضح ترقیاتی ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے متعلقہ فورمز یعنی پارلیمنٹ اور سی سی آئی میں زیرِ بحث لانا چاہیے۔
اس کے باوجود کہ ہمارے لیے زراعت اہم ترین میدان رہا ہے، زرعی مشینری کی پیداوار کے شعبے میں حال کوئی اچھا نہیں رہا ۔ لائیو اسٹاک اور فشریز کے شعبوں میں فوڈ پراسسنگ اور پریزرویشن کے شعبوں میں ہم کوئی خاص پیش رفت نہیں کرسکے۔ تعمیراتی اور زرعی شعبوں میں پاکستان جدید کاری کی طرف پیش قدمی میں ناکام رہا ہے۔ ہم ایک زرعی ملک ہونے پر فخر کرتے ہیں، تاہم زرعی شعبہ جی ڈی پی میں اپنے حصے میں تنزلی کے بعد اب ۲۴ فی صد پر آ گیا ہے، جس میں سے ۵۸ فی صد حصہ لائیو اسٹاک کے ذیلی شعبے کا ہے۔ تعمیراتی شعبہ جو کسی ملک کی ترقی کے لیے اہم ترین شعبوں میں سے ہوتا ہے، جس سے کئی متعلقہ شعبوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، فرسودہ طریقوں پرچل رہا ہے۔ ریئل اسٹیٹ جو تعمیرات سے متعلق ایک شعبہ ہے، کرپشن کی آماجگاہ ہے۔ آئے دن زرعی زمین کا رہائشی منصوبوں میں تبدیل ہو جانا اس کرپشن کا ایک شاخسانہ ہے۔ صوبہ پنجاب میں ۲ء۸ ملین ایکڑ زرعی اراضی جو کہ کل قابلِ کاشت اراضی کا ۱۵ سے ۲۰ فی صد ہے رہائشی اسکیموں کی نذر ہو چکا ہے (Punjab Land Use Report 2023 اور Pakistan Bureau of Statics 2023)۔
دوسرے نمبر پر صوبہ سندھ ہے جہاں ۱ء۲ ملین ایکڑ زرعی زمین رہائشی اسکیموں کی نظر ہوئی ہے۔ ہمیں مزید رہائشی منصوبوں کے لیے عمودی تعمیر پر توجہ دینا ہوگی۔ مزید یہ کہ زرعی اور تعمیراتی شعبوں کی اہمیت کے پیش نظرایک طرف تو فرسودہ طور طریقوں کو تبدیل کرنا ہو گا جس میں چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کی کارکردگی کو جدید طرز پر استوار کرنا شامل ہے، اور دوسری طرف ایسی نئی صنعتوں کے قیام کی طرف توجہ دینا ہوگی جو دور جدید کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔
۱۹۷۰ء کی دہائی میں وزیرِاعظم ذوالفقارعلی بھٹو کی حکومت کی جانب سے ا یک بڑی تعداد میں نجی صنعتی اور مالیاتی اداروں کو قومیانے کی پالیسی کے تحت کئی قومی ادارے معرضِ وجود میں آئے۔ یہ اقدامات زیادہ تر نظریاتی اور سیاسی محرّکات کے تحت کیے گئے تھے، جس میں اقتصاد ی اور سماجی پہلوؤں پر مناسب توجہ نہیں دی گئی۔ دوسری اور نسبتاً کمزور رائے یہ ہے کہ یہ قومیانے کا عمل نظریاتی مقاصد کے ساتھ ساتھ اس وقت کی مالی ضروریات کے پیش نظر کیا گیا تھا۔ قومیائے جانے والی صنعتوں میں لوہا ، بنیادی دھاتیں، بھاری انجینئرنگ، بھاری برقی آلات، موٹرگاڑیاں، ٹریکٹر، پیٹروکیمیکل، سیمنٹ، بجلی اور گیس کی یوٹیلٹی کمپنیاں اورآئل ریفائنریاں بھی شامل تھیں۔ دنیا کے کئی ممالک نے نیشنلائزیشن کے تجربے کیے، تاہم کامیاب تجربات ان ممالک کے رہے جہاں حکومتیں مستحکم اور ادارے مضبوط تھے۔ کئی ممالک نے اس ماڈل میں ناکامی کے بعد ڈی نیشنلائزیشن کی طرف پیش رفت کی، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ کوششیں تا حال جاری ہیں۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ صنعتوں کے قومیانے کا عمل جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا دور میں چند کاروباری گھرانوں پر کی جانے والی سختیوں کے فوراً بعد شروع ہوا، جس میں ۲۲ صنعتی گروپوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ کاروباری گھرانے وہ تھے جو آزادی کے فوراً بعد قائداعظم محمد علی جناحؒ کی درخواست پر بھارتی گجرات کے علاقے اور بمبئی سے پاکستان آئے اور انھوں نے پاکستان کی ابتدائی صنعتی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔
اُس وقت بھی اور آج بھی، بڑے صنعتی گروپوں کو ان کی سماجی ذمہ داریوں، مزدوروں کے حقوق سے متعلق قوانین اور ٹیکس وغیرہ کے حوالے سے ایک حد میں رکھنا ضروری تھا اور ہے۔ تاہم، کاروباری گروپو ں کو منصوبہ بندی اور ممکنہ نتائج کے اندازوں کے بغیر یوں نشانہ بنانے سے مارکیٹ میں غلط پیغامات جاتے ہیں، جس سے خوف و ہراس کی فضا پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں تاجر و صنعت کار منفی رجحانات کی طرف جا سکتے ہیں۔ ۱۹۷۰ء کی دہائی میں دباؤ کے جواب میں اور اپنے کاروبار کے تحفّظ کے پیش نظر پاکستانی نجی کاروباری حلقوں میں دو اہم رجحانات واضح نظر آتے ہیں:
پہلا، یہ کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو گئے اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاکر چلنے لگے اور انھوں نے ملک میں سیاسی، سماجی و اقتصادی پیش رفت کو تشکیل دینے میں اسٹیبلشمنٹ کے منصوبوں کے زیرِاثر اپنا کردار ادا کیا۔ یہ گٹھ جوڑ عام طور پر ملک کے لیے صحت مند نہیں رہا۔ یہ مضر گٹھ جوڑ آج تک جاری ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح ہمارے ہاں عسکری اداروں کے لیے بوجوہ استعمال کی جاتی ہے، جب کہ دراصل اس میں سول بیوروکریسی بھی شامل ہے، جن میں سےکئی اپنے مفادات کے حصول اور کمزوریوں کی پردہ پوشی کی جستجو میں حسبِ ضرورت فوج اور سیاسی قیادت کے آلہء کاربن جاتے ہیں۔
دوسرا رجحان پاکستانی نجی کاروباری حلقوں میں یہ پیدا ہوا کہ انھوں نے اپنی سرمایہ کاری کو مقامی سے غیر ملکی منصوبوں کی طرف منتقل کیا اور زیادہ تر سرمایہ کاری بیرون ملک کی۔ یہاں تک کہ مقامی سرمایہ کاری کے لیے بھی انھوں نے غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کو محفوظ راستہ جان کر اسےاختیار کیا۔ اس رجحان کے سبب، صنعتی شعبے میں پاکستان کا انحصارغیر ملکی سرمایہ کاری اور ٹکنالوجی کی فراہمی پر بڑھتا چلا گیا اور اندرون ملک تحقیق، ایجاد و اختراع میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ دنیا میں وہی ممالک صنعتی ترقی میں آگے ہیں جہاں تحقیق و ترقی (R&D) پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جس کی ایک بہترین مثال جنوبی کوریا کی ترقی میں دیکھی جا سکتی ہے۔
صنعتوں کے قومیائے جانے کے بعد کاروبار کے لیے گھٹن کے ماحول میں، صنعتوں میں جدّت، تنوع اور طرزِ جدید کی جانب کوئی پیش رفت نہ ہوسکی۔ نجی کاروباری اداروں نے محفوظ کھیل کھیلا اور دوسری جانب قومیائی گئی صنعتیں حکومت کی مداخلت کا شکار ہو کر مزید مسائل کا شکار ہوتی گئیں۔ یہ بھی کہ معیار کی جانچ پڑتال کے فعال نظام کی عدم موجودگی اور سرکاری بدانتظامی نے صورتِ حال کو مزید دگرگوں کر دیا۔ مزید یہ کہ سرکاری شعبے میں بھی صنعتی ترقی کے لیے درکار سائنسی اورتکنیکی تحقیق و ترقی (R&D) کی واضح کمی رہی۔ غرض ان دو بنیادی اسباب کی بنا پر ہم بین الاقوامی منڈیوں میں مسابقت نہ کر سکے۔ دفاعی صنعت کے بعض شعبوں میں اچھی پیش رفت دیکھنے کو ملی۔ شاید اس کی وجہ ۱۹۷۱ء کی جنگ میں شکست کے بعد پیدا ہونے والی ایک قومی نفسیات، دفاع وطن کا جذبہ اورعدم تحفظ کا احساس رہا ہو۔ پاکستان کا ایٹمی قوت بن جانا بھی اسی احساس کا نتیجہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قومی سطح پر کسی جذبے اور احساس کا موجود ہونا ترقی کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے اورقوموں کے مستقبل کی تشکیل میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔
گویا اندرونی جوہری ترقی وہ دوسرا مظہر ہے جو عوام کے فطری رجحانات پر منحصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، موجودہ دور میں IT سیکٹر پاکستانی نوجوان ورک فورس کی توجہ کا مرکز ہے، لہٰذا اس شعبے میں ترقی اور یہاں تک کہ اس سے متعلقہ دیگرشعبوں میں صنعتوں کا قیام آج ہمارے قومی ایجنڈے کا ایک اہم جز ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے جو کہ خوش آئند ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ جماعت اسلامی نے اسی صورتحال کے پیش نظر IT میں پیشہ ورانہ ورک فورس میں اضافے کے لیے ’بنو قابل‘ جیسے پروگرام شروع کیے ہیں۔ تاہم، اس ضمن میں حکومتی سطح پر بڑے پیمانے پر کام کی ضرورت ہے۔
اگرچہ ریاستی ملکیت والے ادارے(SOEs) اپنے قیام کے وقت موجود اہم معاشی اور سماجی ضروریات کے تحت قائم کیے گئے تھے، لیکن اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ طویل مدّت گزر جانے کے بعد ان میں سے اکثرادارے اپنے جیسے نجی اداروں کے مقابلے میں کارکردگی میں پیچھے رہ گئے۔ پاکستان میں ان سرکاری اداروں کی ناکامی کی بڑی وجوہ میں اعلیٰ انتظامیہ میں سول سرونٹس کا غلبہ اور وزارتوں کی جانب سے غیر پیشہ ورانہ نگرانی شامل ہیں۔ وقت کے ساتھ، قوم کو ان اداروں کی نااہلی کی قیمت کھربوں نہیں تو سیکڑوں ارب روپے کے نقصان کی صورت میں اٹھانی پڑی ہے۔
نااہلی کو دیکھنے کا ایک زاویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکاری اداروں کے ملازمین کو نجی شعبے کے مساوی ملازمت کے مقابلے میں نرم شرائط پرملازمت فراہم کی جاتی ہے۔ دوسری طرف اوقات کار کی کمی، چھٹیوں کی زیادتی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرٹ پر ترقی پانے کے لیے کارکردگی کی مناسب جانچ کے نظام کا فقدان وہ مسائل ہیں جو سرکاری کمپنیوں اور اداروں کو درپیش ہیں، اورانھیں حل کیا جانا نہایت ضروری ہے۔ ایک بنیادی مسئلہ ’بدانتظامی‘ ہے جس کو ترجیحی بنیادوں پر دور کیا جانا چاہیے، ورنہ مزید سرکاری ادارے بھی ماضی کی طرح کے انجام سے دوچار ہوں گے، اور ہم ایسے تمام اداروں کے لیے نجکاری کی تدابیر ڈھونڈتے پھریں گے۔ ہمیں اس مقصد کے لیے تکنیکی،مینجمنٹ، اقتصادی اور قانونی امور کے ماہرین کو اپنے اداروں میں ترجیحی بنیاد پر لیڈنگ رول ادا کرنا ہو گا، جہاں وہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے احکام پر چلنے کے بجائے پروفیشنل بنیادوں پر فیصلے کر سکیں۔ ہمارے ہاں وزارتوں میں ایسے کئی تجربہ کار افراد موجود ہیں اور جہاں ان کی کمی محسوس ہو ایسے ہنرمند افراد کی کمی نہیں اور اس سلسلے میں بیرون ملک سے بھی پروفیشنلز کو لانا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔
توانائی اور مالیات کے شعبوں میں چند مستثنیات کو چھوڑ کر، مختلف شعبوں میں اکثر سرکاری ادارے خسارے میں چلتے رہے ہیں۔ ان اداروں کو ٹیکس دہندگان کی محنت کی کمائی سے اور ملک پر قرضوں کا بوجھ ڈالتے ہوئے بیل آؤٹ فراہم کر کے زندہ رکھا جاتا رہا ہے۔ مجموعی طور پر، قومیائے گئے سرکاری ادارے اپنی پیداوار اور کارکردگی میں اپنے قومیائے جانے سے قبل کے دور کے مقابلے میں مسلسل تنزلی کا شکار رہے ہیں۔ وہ سرکاری ادارے جو حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے تھے، ان کی حالت بھی مختلف نہیں، کیونک وقت کے ساتھ ساتھ ان میں متعلقہ وزارتوں اور سیاستدانوں کی مداخلت میں اضافہ ہوتا گیا، جس نے ان اداروں کی کارکردگی کو متاثر کیا۔
مارشل لا کے اَدوار میں بالخصوص اور سول حکومتوں کے ادوار میں بھی عسکری اداروں کی بے جا مداخلت کے اثرات کم تباہ کن نہیں رہے۔ عسکری اداروں نے اپنے طور پر بھی صنعت کاری میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا، جو ایک جانب ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں خلل کا سبب بنتا رہا، تو دوسری جانب ایسے اداروں کو حاصل امتیازی مراعات عوام میں بے چینی اور احساس محرومی پیدا کرتی رہیں۔ نیز نجی اور سرکاری صتعتی ادارے منصفانہ مقابلے کی فضا سے محروم رہے۔ چین کی ترقی کے ماڈل میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ وہاں مختلف سرکاری صنعتی اداروں کو سب کے لیے ہموار میدان میں مسابقت کرنا پڑتی ہے۔
اس دلیل کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ حکومت کا صنعتی اور کاروباری اداروں میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ داری صرف نگرانی اور ضابطہ سازی تک محدود ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ عوامی خدمت اور اسٹرے ٹیجک اہمیت کے شعبوں میں کام کرنے والے سرکاری اداروں پر مناسب حکومتی کنٹرول رکھا جانا چاہیے۔ تاکہ عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکے اور اجارہ داروں اور منافع خوروں کے استحصال سے عوام الناس کو محفوظ رکھا جا سکے، ساتھ ہی ساتھ ان کی حسّاسیت کو بھی ملحوظ رکھا جا سکے۔
نجکاری کے بعد مالیاتی شعبے نے کچھ پہلوؤں میں اپنی کارکردگی کے اعداد و شمار میں بہتری دکھائی ہے اور اپنی سروسز کی کارکردگی کو بھی بہتر بنایا ہے۔ تاہم، عمومی فلاح و بہبود کے حوالےسے ان کی افادیت مشکوک ہے۔ توانائی کےشعبے میں او جی ڈی سی ایل(OGDCL) اور پی پی ایل (PPL) دو مختلف منظرنامے پیش کرتےہیں۔
پاور سیکٹر میں بڑے پیمانے پر نجکاری کا پلان بنایا جا رہا ہے اور اس کے لیے کراچی الیکٹرک (KE) کی نجکاری کو ایک مثبت پیش رفت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اوّل تو یہ امرخود بحث طلب ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ DISCOS جن کی نجکاری زیرغور ہے KE سے قدرے مختلف قسم کے ادارے ہیں، جو نہ توKE کی طرح بجلی کی پیداوار، اس کی ترسیل اور تقسیم کے تمام کاموں میں اپنی موجودگی کےسبب ایک مربوط حیثیت رکھتے ہیں اور نہ ان کے اثاثے انھیں نجکاری کے لیے موزوں میدان فراہم کرتے ہیں۔ KE دراصل اپنی تقسیم سے پہلے کے WAPDA کے ادارے کی طرح کا ایک مربوط ادارہ ہے اور اس کا موازنہ محض تقسیم و فراہمی (distribution) پر مامور DISCOS سے کرنا مناسب نہیں۔
پاکستان میں ریاستی اداروں(SOEs) کو ملک کی صنعتی اور سماجی ترقی کے لیے ایک مؤثر ذریعہ بنانے میں ناکامی اور ان کے قومی خزانے پر بوجھ بن جانے کے تناظر میں ۱۹۸۰ء کی دہائی سے مختلف حکومتوں نے نجکاری کو اقتصادی اصلاحات کے لیے ایک راستے کے طور پر اپنایا۔ نجکاری کے لیے منطق یہ رہی ہے کہ اس سےغیر فعالSOEs کی کارکردگی میں بہتری لائی جائے۔ انھیں ملک کی اقتصادی ترقی میں شراکت دار بنایا جائے اور حکومت پر غیر ضروری مالیاتی بوجھ کو کم کیا جائے۔
یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کسی صنعتی یونٹ، مالیاتی ادارے وغیرہ کی حیثیت کو تبدیل کرنا صرف ایک انتظامی فیصلہ یا مالیاتی ماہرین کے کچھ حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ اثاثے صرف زمین، مشینری اور آلات پر مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ انسانی وسائل ان اثاثوں کا سب سے اہم اور قیمتی حصہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کا انتخاب درست طریقے سے کیا جائے، تربیت کی مناسب سہولیات فراہم کی جائیں، تو ایسے اقدامات ان اثاثوں کی قدر میں نمایاں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بنیادی مسئلہ انسانی وسائل (HR) سے متعلق ہے۔ جس پر توجہ ضروری ہے۔ بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے صرف قلیل مدتی اہداف یا سیاسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نجکاری یا قومیانے کے فیصلے کرنا درست حکمت عملی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کے وسائل میں اہم ترین اس کی جواں سال ورک فورس ہو سکتی ہے، اگر اس کی تربیت اور اس کے مفاد کو خاطرخواہ اہمیت دی جائے۔ اگر نجکاری کرنا اشد ضروری ہو جائے اور نجکاری کے نتیجے میں کسی ادارے میں ملازمتوں میں کمی کا خدشہ ہو، تو ہر سطح کے کارکنان کو اسی نوع کی کسی دوسری صنعت کے لیے Retraining کے ذریعے تیار کیا جائے اور ان کے لیے روزگار کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔
پچھلے دور میں قومیائے گئے ریاستی اداروں کو واپس نجی ملکیت میں دینے کا عمل جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے دوران شروع ہوا اور ۱۹۸۰ء کی دہائی کے آخر میں نجکاری کے اگلے مرحلے کی صورت تک جاری رہا۔ اس دوران زیادہ تر چھوٹے پیمانے کے فوڈ، جینگ اور رائس ہسکنگ یونٹس کو نجی شعبے کے حوالے کیا گیا، جو زیادہ تر سابقہ نجی مالکان کو واپس دے دیے گئے۔ تاہم، قومیانے کے بعد پیدا ہونے والے نقصانات، مشینری کے بگاڑ اور فرسودہ ہونے کی وجہ سے ان یونٹس میں سے بیش تر کو دوبارہ بحال نہیں کیا جا سکا۔
۱۹۹۰ءکی دہائی کے اوائل میں وزیراعظم نواز شریف کے دور میں نجکاری کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے گئے، جب کہ حکومت نے ایک جامع نجکاری پروگرام شروع کیا، جس کا مقصد صنعتوں اور دیگر سرکاری اداروں میں سرکاری حصہ کم کرنا اور اقتصادی کارکردگی کو بہتر بنانا تھا۔ اس عمل کی نگرانی کے لیے ۱۹۹۱ء میں نجکاری کمیشن قائم کیا گیا۔ ۱۹۹۰ءکی دہائی کے اوائل کی نجکاری کی لہر کے دوران، اگرچہ نجکاری مبینہ طور پر شفاف اور نیلام کے ذریعے کی گئی تھی، تاکہ ممکنہ طور پر بدعنوانی اوراقربا پروری کو روکا جا سکے، لیکن نجکاری کا کوئی جامع منصوبہ موجود نہ تھا جو قومی معیشت میں ان یونٹس کی شمولیت اور بہتر کارکردگی کو یقینی بنا سکے۔
مزید یہ کہ اس میں عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے خاطرخواہ اقدامات نہیں کیے گئے تھے۔ لہٰذا، نصف سے زیادہ نجی ملکیت میں جانے والے اداروں کے مالکان نے ان کے ریئل اسٹیٹ اور دیگر کارپوریٹ اثاثے فروخت کردیے، کاروبار بند کر دیے یا پھر حاصل کیے گئے اثاثوں کو نئے کاروباری منصوبوں میں استعمال کیا۔ ہماری رائے کسی بھی ایسی نجکاری کے خلاف ہے جو ’جلدبازی‘ میں کی جائے۔ یہ بھی کہ مستقبل میں نجکاری کی کوئی بھی کوشش مکمل غور و فکر، ایوان میں مفصل بحث، تحقیق اور عوامی اثاثوں کے لیے نجکاری کے واضح اور طے شدہ راستوں کو متعین کرنے کے بعد ہی ہونی چاہیے، جن میں عوامی مفاد مقدّم ہو۔
۱۹۹۰ءکی دہائی کے وسط اور اس کے بعد ۲۰۰۰ء کےاوائل کی نجکاری کی لہروں میں مزید منظم کوششیں کی گئیں، جن میں سابقہ تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ بعض ماہرین کے مطابق، بینکنگ کے انڈر پرفارمنگ اداروں اور سست رفتار سیکٹر میں نجکاری سے نئی جان ڈالی گئی۔ اس دوران میں، متعدد مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں نے نجی اداروں میں سرمایہ کاری کی۔ اگرچہ بینکنگ سیکٹر نے زبردست ترقی کی، لیکن اس میں کچھ بنیادی نوعیت کی خامیاں موجود رہیں۔ اگرچہ نجکاری کے بعد بینکوں کے منافعے میں اضافہ ہوا، تاہم اسی دور میں اقتصادی ترقی کی شرح جمود کا شکار رہی۔ بینکوں نے پیداواری شعبوں کو قرض دینے کے بجائے حکومتی قرضوں میں زیادہ منافع بخش سرمایہ کاری کی۔ اس دوران پرائیویٹ سیکٹر میں، بشمول زراعت SMEs کو دیا جانے والا قرضہ ۲۰۰۰ء میں جی ڈی پی کا ۲۵ فی صد تھا جو ۲۰۱۵ء میں کم ہوکر ۱۶ فی صد ہو گیا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ سہولتوں پر عام آدمی کے مساوی حق کو نظر انداز کرکے صرف منظور نظر سرمایہ کاروں اور دیگر سرکاری اداروں کو فیضیاب کرنے والی نجکاری کو ایک اچھی پیش رفت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نجکاری وہی کامیاب سمجھی جائے گی جس کے نتیجے میں عوامی سطح کی فلاح و بہبود سامنے آئے۔
ٹیلی کام سیکٹر کا جائزہ لیں تو مرکزی ادارہ پی ٹی سی ایل پہلے جزوی نجکاری کے عمل سے گزرا، تاہم اس تبدیلی کے باوجود مختلف طرح کی حکومتی مداخلت نے کارکردگی میں بہتری کی راہ میں رکاوٹ ڈالے رکھی۔ ۱۹۹۰ء کی دہائی میں پی ٹی سی ایل نے اربوں روپے کی آمدنی حاصل کی اور تقریباً ۶۴ ہزار افراد کو روزگار فراہم کیا۔ ۲۰۰۶ء میں پی ٹی سی ایل کی نجکاری کے تحت اس کے ۲۶فی صد حصص فروخت کر دیے گئے، جس کے ساتھ ہی انتظامی اُمور بھی اتصالات کے پاس چلے گئے، جو خود کوئی نجی کمپنی نہیں بلکہ ایک عرب ملک کی قومی کمپنی تھی۔ اس فروخت میں سے اتصالات کی طرف سے ۸۰۰ ملین ڈالر کی ادائیگی ابھی باقی ہے۔ کمپنی کے بہت سے اثاثوں کی ملکیت کے معاملات میں ابھی بھی اختلافات موجود ہیں۔ ٹیلی کام سیکٹر میں بیرو ن ملک سے آنے والی سرمایہ کاری جو جنرل مشرف کی حکومت کے دور میں آئی ایک اچھی پیش رفت تھی، اس کے ذریعے پی ٹی سی ایل کے لیے ایک مسابقت کی فضا پیدا ہوئی۔
۲۰۱۰ءکی دہائی میں مسلم لیگ (ن) کی حکومت کے تحت نجکاری کے ایجنڈے کو دوبارہ زندہ کیا گیا، جس میں پاکستان اسٹیل ملز اور بجلی کی ترسیل کی کمپنیوں جیسے خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کا ہدف رکھا گیا، لیکن مختلف وجوہ کی بنا پر یہ عمل مکمل نہ ہو سکا۔ اس دوران نجکاری کمیشن نے کچھ چھوٹے یونٹس فروخت کیے اور بینکنگ و انرجی سیکٹرز میں اپنے حصص کے کچھ حصے کو فروخت کیا۔
ہماری نظر میں نجکاری کے کامیاب اور ناکام تجربات سے سیکھنا بہت اہم ہوگا۔ اس ضمن میں مثبت اور منفی اثرات مندرجہ ذیل ہیں:
ہمارا موقف ہے کہ آئندہ کسی بھی نجکاری کے عمل کو جامع تحقیق اور ایک مضبوط قانونی فریم ورک کے تحت ہی ہونا چاہیے، تاکہ بدعنوانی اور اقربا پروری سے بچا جائے اورعوام کے مفاد کو یقینی بنایا جاسکے۔
تاریخی طور پرجماعت اسلامی کا موقف نجکاری کے حق میں نہیں رہا۔ جماعتِ اسلامی کی بنیادی تشویش عوامی فلاح و بہبود اور سرکاری اداروں میں بڑی تعداد میں ملازم افراد کے مفادات کے تحفظ سے متعلق رہی ہے۔ مزید یہ کہ جماعت اسلامی نجکاری کے بعد اجارہ داری قائم ہو جانے اور بے قابو منافع خوری جیسے مسائل کے خدشات کو پیش نظر رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں چینی، سیمنٹ، کھاد اور دیگر شعبوں میں چند سرمایہ کاروں کی اجارہ داری اور کارٹیل کی تشکیل سے عوامی مفادات کو نقصان پہنچتا رہا ہے۔ بہرطور بدلتے ہوئے اقتصادی حقائق اور بیش تر سرکاری اداروں کی ناقص کارکردگی کی بنا پر قومی خزانے کو ہونے والے نقصان کے پیش نظر، نجکاری کو مکمل طور پر شجر ممنوعہ تو نہیں سمجھا جا سکتا، تاہم، جماعتِ اسلامی کی بنیادی تشویش بدستور ’وسیع ترعوامی مفاد کا تحفظ‘ ہی ہے۔
حال ہی (۲۰۲۴ء) میں حکومت پاکستان نے سرکاری اداروں کی نجکاری کا ایک نیا پروگرام ترتیب دیا ہے اور پہلے مرحلے میں ۲۴ سرکاری ادارے نجکاری کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، جن میں مزید ادارے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی ہدایت کے مطابق، حکومت کو سرکاری اداروں کو چار زمروں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے:
۱- اسٹرے ٹیجک یعنی حسّاس اور کلیدی نوعیت کےادارے ۲- وہ ادارے جنھیں نجکاری کی ضرورت ہے، ۳- وہ ادارے جنھیں تنظیم نو کے بعد درمیانی مدّت میں سرکاری اداروں کے طور پر برقرار رکھا جائے گا، اور ۴- وہ ادارے جن کی نجکاری تنظیم نو کے بعد عمل میں لا ئی جائے گی۔
پیش رفت یہ ہے کہ اب تک پی آئی اے کی نجکاری کی پہلی کوشش صرف اس عمل کو مزید مشکوک بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ کم سے کم، اس سے حکومت کی جانب سے تیاری کا فقدان تو ظاہر ہوتا ہی ہے، جو آئندہ نجکاری کی کوششوں کو مزید مشکل بنا دے گا۔
مختلف حکومتوں نے نجکاری کے اقدامات کا اعلان کیا اور کچھ پیش رفت بھی ہوئی۔ موجودہ حکومت نے بھی اپنی پالیسی کا اعلان کیا ہے جو اس کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ نجکاری سے متعلق فیصلے عوامی اثاثوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حقیقت کو سرکاری اداروں کے ایکٹ ۲۰۲۳ء کے تحت قانونی طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ نجکاری کی پالیسی کے مقاصد کو عوام اور پارلیمنٹ کے سامنے واضح کرے اور نجکاری کے کسی بھی اقدام کے لیے پارلیمانی منظوری کو یقینی بنائے۔
مئی ۲۰۲۴ء میں وزیراعظم شہباز شریف نے بیان دیا کہ حکومتِ پاکستان سوائے اسٹرے ٹیجک اداروں کے تمام سرکاری اداروں کی نجکاری کرے گی ۔ اوّل تو اس اصطلاح ’اسٹرے ٹیجک‘ کی وضاحت ضروری ہے۔ یہ واضح رہے کہ اس کے تحت صرف دفاعی ادارے نہیں آتے، گو کہ ہمارے ہاں اس کام کو صرف فوج ہی کا فرض سمجھا جاتا رہا ہے اور سول حکومتوں نے اس جانب توجہ نہیں کی ہے۔ اس بنا پر فوج میں تو اسٹرے ٹیجک پلانگ ڈویژن موجود ہے لیکن سول انتظامیہ محض پلا ننگ ڈویژن پراکتفا کرتی ہے ۔ دراصل کسی ادارے یا عمل کے اسٹرے ٹیجک ہونے یا نہ ہونے کا تعین اسٹرے ٹیجی کے وضع کیے جانے کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے، جوطویل مدّت کے لیے ہوتی ہے۔ سرکاری اداروں کے بارے میں بھی اسٹرے ٹیجی طویل مدّت کے لیے قومی اتّفاق رائے سے بنائی جانی چاہیے اورحکومتوں کی تبدیلی کے باوجود کم و بیش برقرار رہنی چاہیے۔
نجکاری کمیشن کے قوانین کو صوبائی مفادات کے تناظر میں ان کےآئینی حقوق کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ کچھ اثاثے وفاقی حکومت اور صوبوں کی مشترکہ ملکیت میں ہیں۔ اس معاملے میں مفادات کو ہم آہنگ کرنے کے لیے مشترکہ مفادات کونسل (CCI) ایک مناسب پلیٹ فارم ہے۔
ایسے ادارے جن سے عوام کی ایک بڑی تعداد کا مفاد وابسطہ ہے، ان کی نجکاری سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ مثال کے طور پر ٹرانسپورٹ سیکٹر میں موجود ریلوے کے قومی ادارے کی نجکاری کے بجائے اس کی تنظیمِ نو کی طرف توجہ دی جائے، جب کہ اسی سیکٹر میں ہوائی سفر کے لیے موجود قومی ہوائی کمپنی جو کہ ایک محدود طبقے کے لیے خدمات انجام دیتی ہے، اس میں ایک اچھے پی پی پی معاہدے کے تحت نجی شعبے کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ روڈ ٹرانسپورٹ اور اندرون شہر ٹرانسپورٹ کے نظام میں حکومت اور نجی شعبے کی مسابقت ایک اچھا ماڈل ہو سکتا ہے۔
تجویز ہے، کہ اس کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دلائی جائے، جس کے نتیجے میں ملک کو درج ذیل فوائد حاصل ہوں گے:
۱- بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی اور ان کے آبائی وطن کے درمیان تعلق مزید مضبوط ہوگا۔
۲- بیرون ملک پاکستانی، جو پہلے ہی ترسیلات زر کا ایک بڑا ذریعہ ہیں، اس اسکیم سے پاکستانی معیشت میں ان کا کردار اور بڑھ جائے گا۔
۳- چونکہ وہ نئی ٹکنالوجی اور جدید کاروباری ماڈلز سے زیادہ روشناس ہیں، اس بنا پر وہ نجکاری کے لیے پیش کردہ سرکاری اداروں کو دوبارہ فعال بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیےاداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ان کے حصص کے تناسب سے ان کا حصہ رکھا جائے۔ پاکستانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کو ان ممالک اور علاقوں میں حصص کی فروخت کے عمل کا انتظام کرنے اور سہولیات فراہم کرنے کا ہدف دیا جائے اور جن ممالک میں وہ موجود ہیں انھیں وہاں کے قوانین کے مطابق مالیاتی لین دین کو آسان بنانے اور دیگر انتظامی سہولیات فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔
۴- سرکاری اداروں کی نجکاری کی صورت میں پیش کردہ کل حصص کا جو حصہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مختص کیا جائے، اس کے حجم کا تعین نجکاری کمیشن کے ذریعے مخصوص سرکاری ادارے کی نجکاری کے وقت بحث اور ضروریات کے جائزے کے بعد کیا جائے۔
نجکاری کے لیے ایک ایسا ماڈل تشکیل دینا ضروری ہے، جس میں مارکیٹ کی قیمت سے کم پر نجکاری اورغیر شفاف لین دین سے بچا جائے۔ ملازمین کو نجکاری پروگرام سے با خبر رکھا جائے اور نجکاری کے بعد کارکردگی کی نگرانی کو یقینی بنایا جائے۔
مختلف شعبو ں کے معاملات مختلف اقسام کے ہیں۔ اس لیے ان کا الگ الگ گہرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، مثلاً پاور سیکٹر میں ’کراچی الیکٹرک‘ (KE )کی نجکاری کا جائزہ جو برقی تقسیم کاری و ترسیل کرنے والی کمپنی ہے، جب کہKAPCO بجلی کی پیداوار سے متعلق ہے۔ ان کمپنیوں کا جائزہ عوامی مفاد پر ان کی نجکاری کے بعد پڑنے والے اثرات کے اعتبار سے اور ان اداروں کی کارکردگی کی نگرا نی کے لیے ریگولیٹری اداروں کی کارکردگی کی جانچ کی غرض سے لینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح دیگر شعبہ جات جیسے کہ تیل اور گیس، ٹرانسپورٹ، آٹو موبائل وغیرہ کے لیے بھی یہی حکمتِ عملی اختیار کی جائے اور نجکاری کے عمل کو ’ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانکنے‘ کے مترادف نہ بنایا جائے، ہرادارے کےمخصوص حالات کو مد نظر رکھنا بہت اہم ہوگا۔
نجکاری کسی ایک حکومت کا کام نہیں، پوری قوم کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ اس لیے پارلیمانی کمیٹی برائے نجکاری کو فعال بنانا ضروری ہے اور اس میں حسب ضرورت اچھی شہرت رکھنے والے ماہرین کی خدمات حاصل کرنا بھی اہم ہوگا۔ عوام کو اس پیش رفت سے عوامی سطح پر ماہرین کے بحث و مکالمے کے ذریعےآگاہ رکھنا ضروری ہو گا۔ اس سے ایک قومی سوچ وجود پائے گی۔ نجکاری کے بہتر اقتصادی نتائج ترقی پذیراور ترقی یافتہ ممالک میں واضح پالیسیوں کی پیروی اور شفافیت ہی سے حاصل ہوئے ہیں۔
آئی ایم ایف کی ہدایات کے مطابق اوپر بیان کیے گئے مجوزہ زمروں میں سے نمبر (۳) وہ جنھیں تنظیم نو کے بعد درمیانی مدت میں سرکاری ملکیت میں برقرار رکھا جائے گا، اور (۴) وہ جن کی نجکاری تنظیم نو کے بعد کی جائے گی، کے اداروں کو نجکاری سے قبل اور درمیانی مدّت میں فعال رکھنے کے لیے کچھ اقدامات ضروری ہوں گے۔ اس تناظر میں بورڈ آف ڈائریکٹرز پر حکومت کے اثر و رسوخ کو کم کرنا اہم ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم ایک ایسی پالیسی وضع کرنے کی تجویز دیتے ہیں جو یہ یقینی بنائے کہ:
__ بورڈ آف ڈائریکٹرز صرف متعلقہ شعبوں کے ماہرین پر مشتمل ہوں۔
__ بورڈ میں اداروں سے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے قابل ماہرین کی شمولیت ہو تاکہ ادارے کی روایت اورعلم کا تسلسل برقرار رہے۔
__ کسی بھی سرکاری عہدے پر کام کرنے والا شخص بورڈ کا حصہ نہ ہو۔
__ بورڈ کے اراکین کا تقرر مکمل طور پر میرٹ کی بنیاد پر ہو، جس میں تکنیکی اور نفسیاتی جانچ شامل ہو۔
__ اصل مقصد مالی نقصانات کو روکنا، اقتصادی استحکام کو بڑھانا، آمدنی کو زیادہ سے زیادہ کرنا اور عوامی فلاح کو یقینی بنانا ہے۔
پاکستان میں نجکاری کے تجربات کامیابیوں اور ناکامیوں کا ملا جلا مجموعہ رہے ہیں۔ کارکردگی میں بہتری اور سرمایہ کا ری کے حصول میں کچھ کامیابیاں ضرور حاصل ہوئیں، لیکن عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے حصول میں اہم چیلنجز باقی ہیں۔ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے نجکاری کا ایک شفاف اور قابلِ احتساب فریم ورک تیار کرنا ہو گا۔ ریگولیٹری میکانزم کو مضبوط کرنے، اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے اور سیا سی عزم ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کرکے ایک بہترین طرزِ عمل کو اپناتے ہوئے پاکستان نجکاری کے ذریعے اقتصادی ترقی کو فروغ دے سکتا ہے اور اپنے شہریوں کے لیے خدمات کی فراہمی کو بہتراور ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنا سکتا ہے۔
غزہ پر ڈیڑھ سال کی مسلسل بمباری اور قتل عام کے باوجود قاتل ہاتھوں میں رحم کے آثار ہیں اور نہ مظلوم لیکن پرعزم مزاحمت کاروں کے پائے استقلال میں کوئی جنبش۔ ایک طرف تیر کی برسات ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، تو دوسری جانب دل و جان کی قربانی میں کوئی تعطل نظر نہیں آرہا۔ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کردینے والے بموں کے مقابلے میں اہل غزہ صرف نہتے ہی نہیں بلکہ بھوکے پیاسے بھی ہیں اور جبر اور صبر کا ایسا ٹکراؤ تاریخ نے اس سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ تمام تر جبر اور سفاکیت کے باوجود زخموں سے چور اہل غزہ کی مزاحمت بھی جاری ہے۔
ہنگری سے امریکا کی طرف سفر کے دوران اسرائیلی وزیراعظم نے اپنے خصوصی طیارے میں صحافیوں سے کہا: ’’دہشت گردوں ' کی کمر توڑ دی گئی ہے‘‘۔ اللہ کی شان کہ ۶؍ اپریل کی صبح جب نیتن یاہو نے یہ شیخی بگھاری اُدھر مزاحمت کاروں نے عین اسی وقت دس راکٹ اشدود کے بحری اڈے اور عثقلان عسکری کالونی کی طرف داغ دیے۔ پانچ کو امریکی ساختہ آئرن ڈوم نے فضا ہی میں غیر مؤثر کردیا، لیکن حفاظتی نظام کو پچھاڑتے ہوئے ہدف تک پہنچنے والے راکٹوں سے کئی جگہ آگ بھڑک اُٹھی۔
بمباری اور قتل عام کے ساتھ اپریل ۲۰۲۵ء کے ابتدائی دس دنوں سے اہل غزہ کو نقل مکانی کے عذاب کا سامنا کرنے کا آغاز ہوا۔ ہرروز انتباہ جاری ہوتا ہے کہ ’’اگلے تین گھنٹوں میں فلاں علاقے پر خوفناک فوجی کارروائی ہونے والی ہے، وہاں سے نکل جائو‘‘۔بے خانماں لوگ میلوں پیدل سفر کرکے دوسرے مقامات پر پہنچ کر خیمے گاڑہی رہے ہوتے ہیں کہ نئی نقل مکانی کا حکم جاری ہوجاتا ہے۔ اہل غزہ عیدالفطر کی شب سے مسلسل سفر میں ہیں۔اب تھکن کا یہ عالم ہے کہ ۶؍اپریل کو جب الشجاعیہ محلہ خالی کرانے کا حکم آیا تو نڈھال لوگوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ: ’’اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے‘‘۔ پھر مزاحمت کاروں نے عربی، انگریزی اور عبرانی میں پیغام جاری کردیا کہ ’’بہت سے اسرائیلی قیدی الشجاعیہ میں رکھے گئے ہیں جن کو یہاں سے نہیں ہٹایا جائے گا اور اگر بزور قوت قیدی چھڑانے کی کو شش کی گئی تو اس کے نتیجے میں اسرائیلیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے‘‘۔ اسرائیلی عوام کے نام پیغام میں ترجمان نے مزید کہا کہ ’’اگر نیتن یاہو حکومت کو اپنے قیدیوں کی فکر ہوتی تو وہ جنوری میں ہونے والے معاہدے کی پاسداری کرتا اور جنگ دوبارہ نہ چھیڑتا اور یہ قیدی اس وقت اپنے عزیزوں کے درمیان ہوتے۔ اب غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ اگر اسرائیلی قیدی بھی بمباری سے ہلاک ہوجائیں تو ہم سے شکوہ نہ کرنا‘‘۔
مزاحمت کاروں کے اس اعلان کے بعد قیدیوں کے لواحقین نے تل ابیب میں فوجی ہیڈکوارٹر پر زبردست مظاہرہ کیا۔ لوگ نعرے لگارہے تھے:’’تمھاری جنگ کی قیمت، ہمارے پیاروں کی زندگی‘‘۔ مظاہرین نے فوج کے سربراہ جنرل ایال ضمیر سے ملاقات کی۔سخت مشتعل لوگوں نے مطالبہ کیا کہ فوج، جنگجو نیتن یاہو کا تختہ الٹ دے۔جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے تل ابیب میں مظاہرہ روز کا معمول ہے، لیکن مغربی دنیا کی غیر مشروط سرپرستی کی بنا پر نیتن یاہو کسی کی کچھ سننے کو تیار نہیں۔ تین اپریل کو امریکی سینیٹ نے اسرائیل کو اسلحے پر پابندی کی قرارداد جس بُری طرح مسترد کی، اس نے اسرائیل کے جنگجو حکمرانوں کو مزید ’دلیر‘ کردیا ہے۔
امریکی وزیرخارجہ ہردوسرے روز نیتن یاہو کو فون کرکے امریکی حمایت کا اعادہ کرتے رہتے ہیں۔مزید فوجی امداد کی ضمانت لینے نیتن یاہو ۶؍ اپریل کو بنفس نفیس امریکا پہنچا۔ درحقیقت اس چوٹی ملاقات میں ’ٹرمپ غزہ‘ منصوبے کو آخری شکل دی گئی۔اسی دوران اسرائیلی وزیرخارجہ گدون سعر نے ابوظہبی میں وزیرخارجہ شیخ عبداللہ بن زید النہیان سے ملاقات کی۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماوں نے غزہ امن پر بات چیت کی، لیکن آزاد صحافتی ذرائع بتارہے ہیں کہ اصل گفتگو ایران پرحملے کی صورت میں ایرانیوں کی جوابی کارروائی سے متحدہ عرب امارات کو محفوظ رکھنے کے لیے امریکی و اسرائیلی اقدامات اور فلسطینیوں کے انخلا کے بعد مجوزہ 'ٹرمپ غزہ منصوبے کی تعمیر میں امارات کے کردارپر ہوئی۔
تحقیقات کے بعد اقوام متحدہ نے اس بات کی تصدیق کردی کہ ۲۳ مارچ ۲۰۲۵ء کو غزہ میں پانچ ایمبولینسوں، ایک فائر انجن اور اقوام متحدہ کی گاڑی کو اسرائیلی ڈرون نے شناخت کے بعد نشانہ بنایا۔ اس واقعے میں ۱۵ وردی پوش امدادی کارکن جان بحق ہوئے تھے۔ نیویارک ٹائمز نے وہ تصویر بھی شائع کردی جو خود اسرائیلی ڈرون نے حملے سے پہلے لی تھی، جس میں ایمبولنسیں صاف دکھائی دے رہی ہیں۔
اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA کا کہنا ہے کہ غزہ میں بمباری سے ہرروز ۱۰۰ بچے جاں بحق یا شدید زخمی ہورہے ہیں اور اسرائیل نے دو تہائی غزہ کو No Go ایریابنادیاہے۔اسرائیلی وزیراعظم نے بہت فخر سے کہا کہ ’’اسرائیلی فوج نے فلاڈیلفی راہداری کے متوازی ایک اور راہداری بناکر ر فح کے گرد گھیراؤ مکمل کرلیاہے اور اب مزاحمت کاروں کے لیے ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں‘‘۔ہتھیار ڈالنے کی اسرائیلی خواہش تو شاید پوری نہ ہو، لیکن لگتاہے کہ خون کی ہولی غزہ کے آخری بچے کے قتل تک جاری رہے گی۔ گذشتہ ہفتے ہلال احمر غزہ کے سربراہ نے اپنے پیغام میں کہا:’’ غزہ پر مسلسل آگ برس رہی ہے، پانی کی آخری بوند بھی ختم ہوچکی، ہر طرف موت نظر آرہی ہے‘‘۔ ' اسی کے ساتھ غزہ کے ڈائریکٹر صحت ڈاکٹر منیر البرش کا پیغام بھی نشر ہوا: ’’غزہ آخری سانس لے رہا ہے، دنیا کا بہت انتظار کیا ۔خدا حافظ‘‘۔
اسرائیلی فوج بمباری کے لیے بنکر بسٹر بم استعمال کررہی ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ بم پہاڑی علاقوں میں چٹانوں سے تراشے مورچوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور شہری علاقوں میں اس کے استعمال پر پابندی ہے، لیکن امریکا اور اسرائیل دنیا کے کسی ضابطے اور قانون کو خاطر میں نہیں لاتے۔ امریکا نے کنکریٹ کو چیر دینے والے یہ بم افغانستان میں بے دریغ استعمال کیے تھے۔ روایتی بم کسی سخت سطح سے ٹکراتے ہی پھٹ جاتے ہیں،جب کہ بنکر بسٹر بم عمارت کی چھت چیرکر دس انچ زمین کے اندر گھس کر پھٹتے ہیں جس کی وجہ سے عمارت کا ملبہ اور وہاں موجود لوگ فوارے کی طرح فضا میں بلند ہوجاتے ہیں۔ مرکزی غزہ پر بمباری کے جو بصری تراشے اسرائیلی فوج نے جاری کیے ہیں، اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح گردو غبار اور دھوئیں کے ساتھ بچوں کے لاشے کئی سو فٹ اُوپر فضامیں اُچھلے اور نیچے گر کر پاش پاش ہو گئے۔
غزہ کے ساتھ غربِ اردن میں بھی معاشرتی تطہیر کی مہم زور شور سے جاری ہے۔ عید کے دن اسرائیلی فوج نے جنین کے مضافاتی علاقے برقین اور وسطی غرب اردن کے شہر سلفیت پر حملہ کیا۔ اس دوران بمباری، ڈرون حملے اور ٹینکوں کے بھرپور استعمال نے دونوں قصبات کو کھنڈر بنادیا۔ بمباری اور فائرنگ سے درجنوں افرادجاں بحق ہوئے، زندہ بچ جانے والوں اور زخمیوں کو اردنی سرحد کی طرف دھکیل دیاگیا۔۶؍ اپریل کو غربِ اردن کے شہر ترمسعيّا پر فوجی سرپرستی میں قابضین (Settlers)نے حملہ کیا۔گھر، دکانیں اور گاڑیوں کو آگ لگادی۔ اندھادھندفائرنگ سے امریکی شہریت کا حامل ایک ۱۴سالہ بچہ عمر محمد ربیع جاں بحق ہوگیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دہرا معیار ملاحظہ فرمائیں کہ حماس کی قید میں اسرائیل شہری عیدن الیگزنڈر کی رہائی کے لیے ساری ٹرمپ حکومت سرگرم ہے لیکن اس امریکی بچے کے بہیمانہ قتل پر کسی کو کچھ تشویش نہیں، حتیٰ کے CNN نے اس واقعے پر امریکی حکومت کے ردعمل کے لیے جب وزارت خارجہ وائٹ ہائوس کو برقی خطوط بھیجے تو وہ ای میل مکتوب الیہ نے متن پڑھے بغیر ہی حذف کردی۔امریکا کے بعد جرمنی میں بھی غزہ نسل کشی کی مذمت کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہے۔
اس حوالے سے برصغیر کی خواتین کا جرأت مندانہ کردار ابلاغ عامہ پر چھایا رہا۔کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی معروف آرکیٹیکٹ محترمہ یاسمین لاری نے ایک لاکھ ڈالر کا اسرائیلی ایوارڈ یہ کہہ کر ٹھکرادیا کہ ' اسرائیلی ادارے سے انعام وصول کرکے میں فلسطینیوں کے زخموں پر نمک نہیں چھڑک سکتی۔ یکم اپریل کو بنگلہ دیش کی لڑکی امامہ فاطمہ نے امریکا کے International Women of Courage انعام کو ٹھوکر ماردی۔ امامہ کو ایوارڈ وصول کرنے کے لیے امریکا آنے کی دعوت خاتونِ اول ملانیا ٹرمپ اور وزیرخاجہ مارکو روبیو نے دی تھی۔ اپنے جواب میں امامہ نے لکھا:’’ فلسطینی عوام طویل عرصے سے اپنے بنیادی انسانی حقوق بشمول زمین کے حق سے محروم ہیں۔ فلسطین کی جدوجہد آزادی کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے میں اس ایوارڈ کو مسترد کر رہی ہوں‘‘۔
غزہ کے طول و عرض پر بمباری اور بحروبر سے شدید گولہ باری کے ساتھ اسرائیل اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے مصر کی ثالثی میں مزاحمت کاروں ' سے براہ راست مذاکرات بھی کررہاہے۔ جمعہ ۱۱؍ اپریل کو شناخت پوشیدہ رکھنے کی شرط پر ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے KAN نیوز ایجنسی کو بتایا:’’ نیتن یاہو، آٹھ قیدیوں اور آٹھ لاشوں کے عوض کئی سو فلسطینی رہا کرنے پر تیارہے۔اس دوران پائیدار امن مذاکرات کے لیے ۴۰ سے ۷۰دن حملے بند رہیں گے، جب کہ مزاحمت کار شہری علاقوں اور ر فح سے اسرائیلی فوج کی واپسی اور انسانی امداد کے راستے میں حائل تمام رکاوٹیں ختم کرنے کے مطالبے پرقائم ہیں‘‘۔
گفتگو کے مثبت اشاروں سے پھوٹنے والی امید کی کرن ۱۴؍ اپریل کو اس وقت ختم ہو گئی جب مزاحمت کاروں کے ترجمان سمیع ابوظہری نے الجزیرہ ٹیلی ویژن پر اس بات کی تصدیق کی کہ ’’اسرائیلی تجاویز کا متن ہمیں موصول ہوچکا ہے، جس کے مطابق دوسرے مرحلے کے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے مزاحمت کاروں کو غیرمسلح ہونا ہوگا اور ہم یہ مطالبہ کروڑوں بار مسترد کرتے ہیں۔لیکن اگر اسرائیل امن معاہدہ کرکے غزہ سے اپنی فوج واپس بلالے تو اس کے سارے کے سارے قیدی بیک وقت رہا کردیے جائیں گے‘‘۔
ہفتہ ۱۲؍ اپریل کو جہاں امن مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطحی وفد قاہرہ روانہ ہوا، وہیں اسرائیلی طیاروں نے سارے غزہ پر عربی زبان میں وزیردفاع اسرائیل کاٹز کے آخری انتباہ پر مبنی پمفلٹ گرائے۔ ٹائمز آف اسرائیل میں اس پمفلٹ کا جو متن شائع ہواہے، اس کے مطابق: ’’اسرائیلی فوج نے فلاڈیلفی راہداری کے شمال مغرب میں موراگ راہداری پر اپنا قبضہ مکمل کرلیا ہے۔ شمال میں بیت حنون کا علاقہ بھی اب اسرائیلی فوج کا سکیورٹی زون ہے۔ اہل غزہ کے لیے یہ جنگ ختم کرنے کا آخری موقع ہے‘‘۔
۹؍اپریل کو اسرائیل فضائیہ کے ایک ہزار سے زیادہ ریزرو افسران نے چیف آف ائر اسٹاف میجر جنرل تومر بار کو ایک خط لکھاجس کی نقول اسرائیلی اخبارات کو جاری کی گئیں۔ خط میں کہا گیا ہے: ’’شہری آبادی پر وحشیانہ بمباری مسئلے کا حل نہیں۔ قیدیوں کی آزادی کو لڑائی پر ترجیح ملنی چاہیے‘‘۔ اس خط پر نیتن یاہو کو سخت غصہ آگیا اور وزیردفاع کے نام ایک مکتوب میں کہا کہ :’’اس حرکت سے فوج میں بددلی اور قیادت پر عدم اعتماد پیدا ہوگا، لہٰذا ان سرکش بزدلوں کو فوراً برطرف کردیا جائے‘‘۔ یاد رہے کہ اسرائیل میں فوجی ملازمت ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی اور مناسب صحت کے حامل افراد کو محفوظ یا ریزرو دستے کا حصہ بنالیا جاتاہے۔ اس وقت غزہ میں پونے دولاکھ فعال سپاہ کے شانہ بشانہ ۳لاکھ محفوظ سپاہی لڑائی میں شریک ہیں، جوایک ماہ محاذ پر گزار کر ۳۰ دن آرام کرتے ہیں۔
ابھی ان اسرائیلی باغیوں کی گوشمالی کا کام شروع ہی ہوا تھا کہ اسرائیلی بحریہ کے ۱۵۰سے زیادہ ریٹائرڈ افسران نے وزیردفاع کے نام ایسا ہی ایک خط لکھ مارا۔ بحریہ کے افسران نے غزہ خونریزی فوراً بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریر کیا کہ ’’بے مقصد جنگ سے اسرائیل کو مالی و جانی نقصان اور عالمی سطح پر بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ جنگ دوبارہ شروع کرکے وزیراعظم نے ۵۹؍اسرائیلی قیدیوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے‘‘۔ شام کو میڈیکل کور کے سیکڑوں افسران نے اسی مضمون کا پیغام اپنی قیادت کو بھجوادیا۔ عبرانی چینل ۱۲ کے مطابق اسرائیلی بکتر بند دستے کے سیکڑوں اہلکاروں نے بھی فوج کے سربراہ کے نام خط میں کہا ہے:’’غزہ میں جاری لڑائی اسرائیل کے دفاع کے لیے نہیں بلکہ سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے لڑی جا رہی ہے‘‘۔
جمعہ ۱۱؍ اپریل کو فوج کے انتہائی اہم ۸۲۰۰؍انٹیلی جنس یونٹ کے ۲۵۰ ایجنٹوں کی طرف سے لکھے جانے والے خط نے اسرائیلی قیادت کو مزید پریشان کردیا۔جدید ترین ٹکنالوجی سے مزین ۱۸ سے ۲۱ سال کے ۵ہزار نوخیز جوانوں پر مشتمل اس یونٹ کو اسرائیلی فوج کا دل ودماغ اور اصل قوت سمجھا جاتا ہے۔ اپنے خط میں ان افسران نے کہا کہ طویل اور بے مقصد جنگ نے اسرائیلی فوج کو تھکادیا ہے اور لڑائی سے ہمارے قیدیوں کے لیے خطرات بڑھتے جارہے ہیں۔ خط میں جنگ ختم کرکے سفارتی کوششوں کے ذریعے قیدیوں کی رہائی یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے۔یونٹ ۸۲۰۰ کے خط پر وزیراعظم نے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ہمارے دشمنوں کے حوصلے بلند ہورہے ہیں۔
اس سے قبل ۱۴ فروری کو موساد کے سابق سربراہوں اور سیکڑوں سابق ایجنٹوں نے بھی جنگ بندی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور وزیراعظم کے نام کھلے خط میں انھوں نے قیدیوں کی رہائی کی خاطر فوری امن معاہدے کا مطالبہ کردیا: ’’لڑائی دوبارہ شروع کرکے نیتن یاہو نے اسرائیلی قیدیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں‘‘۔ اس خط پر موساد کے سابق سربراہ دانیال جاسم، ابراہیم حلوی اور تامر پاردو کے علاوہ۲۵۰سابق افسران کے دستخط ہیں۔
امریکی یونی ورسٹیوں میں غزہ نسل کشی کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو کچل دینے کاسلسلہ جاری ہے۔ جمعہ ۱۱؍ اپریل کو غزہ نسل کشی کے خلاف کولمبیا یونی و رسٹی میں طلبہ تحریک کے قائد محمود خلیل کی امریکا بدری کا فیصلہ سنادیا گیا۔محمود کے خلاف کسی پُرتشدد واقعے میں شرکت اور دہشت گردی میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیاگیا۔ گرین کارڈ ہولڈر محمود خلیل کے خلاف فردِ جرم، وزیرخارجہ مارکو روبیو کی دوصفحاتی یادداشت پر مشتمل ہے، جس پر تاریخ بھی درج نہیں ہے۔ میمو میں وزیرخارجہ نےتحریر کیاکہ ' ۷ مارچ کو انھیں ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ سے خلیل کے بارے میں معلومات ملی تھیں کہ خلیل کے امریکا میں قیام سے سام دشمنی کا مقابلہ کرنے کی امریکی خارجہ پالیسی کے مقصد کو نقصان پہنچے گا۔یہود مخالف مظاہروں کے فروغ کا سبب بن سکتا ہے۔ لوزیانہ کی امیگریش جج جیمی کومنز نے اپنے مختصر فیصلے میں لکھا: ’’میرے پاس مارکو روبیو کے خدشات پر سوال اٹھانے کا کوئی اختیار نہیں‘‘۔ فیصلہ سننے کے بعد محمود خلیل نے جج صاحبہ کو مخاطب کرکے کہا: ’’یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ حکومت نے مجھے اس عدالت میں بھیجا ہے، جو میرے خاندان سے ایک ہزار میل دُور ہے‘‘۔ جواں سال محمود خلیل ۸مارچ سے نظر بند ہے۔پیر ۱۴دسمبر کو کولمبیا یونی ورسٹی کے ایک اور طالب علم محسن مہدوی کو ریاست ورمونٹ (Vermont) سے اس وقت گرفتار کرلیا گیا، جب وہ شہریت کے لیے انٹرویو دینے آیا تھا۔ دوسری طرف غزہ نسل کشی کے خلاف مظاہروں کو روکنے میں ناکامی پر صدر ٹرمپ نے کورنیل یونی ورسٹی کی ایک ارب اور نارتھ ویسٹرن یونی ورسٹی کے لیے ۷۹کروڑ ڈالر کی وفاقی گرانٹ معطل کردی ہے۔
اس کے باوجود عرب ممالک کا تل ابیب سے تعاون جاری ہے۔ اپریل کے مہینے میں اسرائیل کے ساتھ مشترکہ فضائی مشقوں میں قطر اور متحدہ امارات نے شرکت کی۔ خلیج یونان پر ہونے والی اس مشق میں امریکا، انڈیا ، فرانس، اٹلی اور پولینڈ شریک ِ کار تھے، اور غزہ میں اسی طرح شہیدوں کے بے گوروکفن لاشے پڑے رہے۔ جھلستی دُھوپ میں اہل غزہ کو گھروں سے نکال کر جبری طور پر بکھیرا جاتا رہا۔
آج صبح ایک صحافی دوست نے فون کیا۔ ان کی کال کا مقصد حال ہی میں نافذ کیے گئے ’وقف (ترمیمی) ایکٹ ۲۰۲۵‘ پر حقائق کو جاننا تھا۔ واضح رہے کہ مسلمانوں سے متعلق ’وقف ایکٹ ۱۹۹۵/۲۰۱۳‘ میں ترمیم کو حکومتِ ہند نے ’لوک سبھا‘ (ایوانِ زیریں)اور ’راجیہ سبھا‘ (ایوانِ بالا) سے منظور کروا کر صدرِ ہند کے دستخط کے بعد باضابطہ طور پر نافذ کر دیا ہے۔ وقف کے قانون میں کی گئی یہ تبدیلی ملک بھر میں بحث و مباحثے کا موضوع بنی ہوئی ہے، اور مختلف مقامات پر اس کے خلاف احتجاج بھی جاری ہیں۔صحافی دوست کا ایک اہم سوال تھا: ’’ترکیہ اور سعودی عرب میں ’وقف‘ ریاست کے ماتحت ہے، تو پھر یہاں ہندستان کے مسلمانوں کو اس پہ اعتراض کیوں ہے؟‘‘ یہ ایک ایسا سوال ہے، جسے عوام کے ذہنوں میں ڈالنے کا کام خود حکومتِ ہند نے کیا ہے۔
جب سے ہندستان میں مسلمانوں کے خلاف ’لینڈ جہاد‘ (Land Jihad) کا من گھڑت پروپیگنڈا زور پکڑنے لگا، اسی وقت ترکیہ اور دیگر مسلم ممالک کا نام لے کر یہ تاثر پھیلایا گیا کہ ان ممالک میں وقف کا کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں ہے۔ ۸؍ اگست ۲۰۲۴ء کو جب ’وقف (ترمیمی) بل‘ لوک سبھا میں پیش کیا گیا، تو حکومت ہند نے اس بل کے حوالے سے ایک وضاحتی بیان سوال و جواب کی شکل میں جاری کیا۔ اس بیان میں ایک سوال یہ بھی تھا:’’کیا تمام مسلم ممالک کے پاس وقف جائیدادیں ہیں؟‘‘جس کے جواب میں کہا گیا: ’’نہیں، تمام مسلم ممالک کے پاس وقف جائیدادیں نہیں ہیں۔ ترکیہ، لیبیا، مصر، سوڈان، لبنان، شام، اردن، تیونس اور عراق میں وقف نہیں ہے۔ تاہم، بھارت میں نہ صرف وقف بورڈز سب سے بڑے شہری اراضی کے مالک ہیں بلکہ ان کے پاس ایک ایسا قانون بھی ہے جو انھیں قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے‘‘۔
پھر ۲؍ اپریل ۲۰۲۵ءکو جب ’لوک سبھا‘ میں وقف (ترمیمی) بل پر بحث ہو رہی تھی، تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ، سمبیت پاترا اور نشی کانت دوبے نے اپنی تقریروں میں دعویٰ کیا کہ کئی اسلامی ممالک جیسے ترکیہ، لیبیا، مصر، سوڈان، لبنان، شام، اردن، تیونس اور عراق میں وقف کا تو کوئی نظام موجود ہی نہیں ہے۔ مگر اگلے ہی روز، یعنی ۳؍ اپریل ۲۰۲۵ءکو راجیہ سبھا میں بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے کہا: ’’ترکیہ میں تمام وقف املاک کو بہتر انتظام اور شفافیت کے لیے ریاست کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ یہ کب کیا گیا؟ ۱۹۲۴ء میں، یعنی ۱۰۰ سال پہلے‘‘۔
جے پی نڈا اس بات سے واقف نہیں ہوں گے کہ ترکیہ میں وقف کا نظام خلافتِ عثمانیہ سے بڑی مضبوطی سے قائم ہو چکا تھا۔ اور آج تو حقیقت یہ ہے کہ ترکیہ میں وقف محض ایک خیراتی ادارہ نہیں، بلکہ ایک مؤثر اقتصادی ایجنسی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف سماجی بہبود کا علَم بردار ہے، بلکہ ملک کی معاشی ترقی اور مجموعی خوش حالی سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔
یہاں یہ جاننا بھی اہم ہے کہ جب ہندستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تب ہندوستان میں ترکیہ اور دیگر مسلم ممالک کی طرز پر اوقاف کی ایک وزارت یا محکمہ قائم کیے جانے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔ دی ٹائمز آف انڈیا میں ۱۷جولائی ۱۹۲۸ء کو شائع ایک خبر کے مطابق، شملہ میں ستمبر کے اجلاس کے دوران قانون ساز اسمبلی میں غیر سرکاری قراردادوں کے لیے مختلف موضوعات پر قراردادوں کے نوٹس دیے گئے تھے۔ ان ہی نوٹس میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے ایک رکن سرعبدالحلیم خان غزنوی (۱۸۷۶ء-۱۹۵۳ء) کا بھی تھا۔ اخبار لکھتا ہے: ’’مسٹر اے- ایچ- غزنوی، جنھوں نے پہلے ہی مسلمانوں کے اوقاف ایکٹ میں ترمیم کے لیے ایک بل پیش کرنے کی اجازت طلب کرنے کے ارادے کا اظہار کیا ہے، ایک قرارداد بھی رکھتے ہیں جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ’اوقاف کے انتظامات کی جانچ پڑتال کے لیےسرکاری و غیر سرکاری افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، تاکہ ہندوستان میں ترکی اور دیگر مسلم ممالک کی طرز پر اوقاف کی ایک وزارت یا محکمہ قائم کیا جا سکے‘۔ ۱۹نومبر ۱۹۲۹ء کے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق: ’’مسٹر غزنوی نے قانون ساز اسمبلی میں وقف کا یہ مسئلہ پھرسے اٹھایا‘‘… ایک اور سوال کے ذریعے وہ [مسٹر اے- ایچ- غزنوی] مطالبہ کرتے ہیں کہ ’’حکام اور غیر سرکاری افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، جو ہندستان میں اوقاف کے انتظامات کی جانچ کرے، تاکہ ترکی اور دیگر مسلم ممالک کی طرح ایک ’محکمہ برائے مذہبی اوقاف‘ قائم کیا جاسکے۔ یاد رہے کہ جناب غزنوی اسی مقصد کے لیے اسمبلی میں ایک بل پہلے ہی پیش کر چکے ہیں‘‘۔
بہرحال، ترکیہ میں وقف مینجمنٹ کے لیے ایک پورا سسٹم موجو دہے۔ سرکاری ادارہ Vakıflar Genel Müdürlüğü یعنی General Directorate of Foundations ترکیہ کے وقف کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ ’’ترکیہ میں کوئی بھی فرد اپنا نجی وقف قائم کر سکتا ہے اور اس میں حکومت کا کوئی دخل نہیں ہوتا‘‘۔ یہ بات ابھی گذشتہ دنوں ہی میرے ایک ترکش دوست نے بتائی ہے۔ یاد رہے کہ ترکی زبان میں ’وقف‘ کو Vakif لکھا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے ’فاؤنڈیشن‘ کہا جاتا ہے۔
ترکیہ میں ’وقف‘ کے نظام کی تاریخ
ترکیہ، خلافت عثمانیہ کے جانشین ملک کے طور پر، ’وقف‘ کے میدان میں ایک گہری اور بھرپور وراثت کا حامل ہے۔ خلافت عثمانیہ کے قیام کے وقت سے ہی، وقف کو روایتی طور پر ان کے نگہبانوں کے ذریعے ہی سنبھالا جاتا تھا۔ عام طور پر، نگہبان وہ لوگ ہوتے تھے جو ’اوقاف‘ کے بانی ہوتے تھے اور ان کی وفات کے بعد، ان کے بچے اور نسلیں ان کے منتظمین بن جاتے تھے۔
صباح الدین یونی ورسٹی استنبول کے اوزان مراشلی کے مطابق، ان نجی طور پر قائم کردہ اوقاف کے علاوہ، ایسے irsādī اوقاف بھی موجود تھے جو سلاطین نے ریاستی بجٹ سے مختص رقم کے طور پر وقف کیے تھے۔ یہ ریاستی سرپرستی میں قائم اوقاف اعلیٰ عہدے داروں، جیسے صدرِ اعظم اور شیخ الاسلام (اعلیٰ مذہبی اتھارٹی)، کی نگرانی میں تھے۔اس کے بعد اوقاف کا انتظام ۱۸۲۶ء میں مرکزی حکومت کے تحت آ گیا، جب کہ مکہ اور مدینہ کی دو مقدس مساجد سے متعلق وقف کی ایک خصوصی وزارت قائم کی گئی، جسے ’وزارتِ اوقافِ شاہی‘ (Evkâf-ı Hümâyun Nezâreti) کہا گیا۔ یہ عثمانی تاریخ میں ایک اعلیٰ بورڈ تشکیل دینے کی پہلی کوشش تھی، جو اسی طرح کے مقاصد کے لیے وقف کیے گئے تھے۔ بعد میں، اس وزارت کے دائرۂ کار کو بڑھا کر ان اوقاف تک پھیلایا گیا، جو سلاطین، ان کے اہلِ خانہ اور پاشاؤں نے قائم کیے تھے۔ ڈاکٹر اوزان مراشلی نےسال ۲۰۲۲ء میں ترکیہ میں وقف کا معاشی نظام عنوان پر پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کی ہے۔
غورطلب رہے کہ irsādī وقف وہ وقف ہے، جو حکومت کے ذریعے قائم کیے گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حکومت کے مخصوص آمدنی کے ذرائع کو مخصوص فلاحی مقاصد کے لیے مختص کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ایک جائز وقف ہو، جو کسی فرد یا انجمن کے ذریعے قائم کیا جائے۔ ترکیہ میں اس نوعیت کے وقف کی معروف مثالوں میں سوشل ایڈ اینڈ سولیڈیریٹی وقف، ترک ماحولیاتی تحفظ وقف اور ترک معارف فاؤنڈیشن شامل ہیں۔ ۲۰۱۸ء میں ترکیہ میں ۱۰۰۲ (ایک ہزار دو) سوشل ایڈ اینڈ سولیڈیریٹی وقف موجود تھے، جن کی ہر ضلع میں کم از کم ایک شاخ موجودہے۔ ان کا بنیادی مقصد غریبوں اور ضرورت مندوں کو براہ راست مالی و مادی امداد فراہم کرنا ہے، تاکہ ان کی خوراک، رہائش، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور دیگر ضروریات پوری کی جا سکیں۔
۲ مئی ۱۹۲۰ء کو وقف کے انتظامی معاملات کو ترکیہ کی پہلی ’گرینڈ نیشنل اسمبلی‘ نے وزرا کے انتخاب کا ایک قانون منظور کیا، جس کے تحت ’وزارتِ شریعت و اوقاف‘ (Şeriye ve Evkaf Vekâleti) قائم کی گئی جس نے پرانی ’وزارتِ اوقافِ شاہی‘ کی جگہ لے لی۔ حالانکہ اس دورکے ابتدائی حصے میں پرانی ’وزارتِ اوقافِ شاہی‘ بھی فعال تھی، خاص طور پر استنبول کے علاقے میں۔ ۳مارچ ۱۹۲۴ء کو وزارتِ شریعت و اوقاف کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم کے ماتحت ایک نیا ادارہ،’ڈائریکٹوریٹ جنرل آف وقف‘قائم کیا گیا۔
مرات چیزاکچا نے اپنے ریسرچ پیپر From Destruction to Restoration: Islamic Waqf in Türkiye and Malaysia میں لکھا ہے: ’’۱۹۶۷ء کے نئے وقف قانون نے ترکیہ میں وقف کے نظام کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ ’صرف اوقاف کے جائیداد کے حقوق کی دوبارہ ضمانت نہیں دی گئی، بلکہ وقف اور کمپنیوں کے روابط کو بھی مضبوط کیا گیا‘‘۔
ڈاکٹر مراشلی اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں لکھتے ہیں:’’ ترکیہ میں سب سے حالیہ وقف قانون ۲۰۰۸ء میں متعارف کرایا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت تمام حکومتی اداروں کو پابند کیا گیا کہ وہ قبضے میں لی گئی وقف جائیدادیں اصل اوقاف کو واپس کریں۔ اس حوالے سے، صرف استنبول میں، ۷۷ اہم وقف جائیدادیں اس قانون کے تحت واپس کی گئیں، جن میں سلیمانیہ مسجد، فاتح مسجد، سلطان احمد مسجد (بلیو مسجد)، آیاصوفیہ مسجد، حرکۃِ شریف مسجد، ایوپ سلطان مسجد، یینی مسجد، بیشکتاش ووڈافون پارک اسٹیڈیم (جزوی)، شیشلی اطفال ہسپتال، عدیلہ سلطان محل، معمار سنان گوزل سنات یونی ورسٹی، گالاتا ٹاور، مسالہ بازار، اور گرینڈ بازار شامل ہیں۔
ایک اور اہم پیش رفت جوترکیہ کے ’ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فاؤنڈیشنز ‘ نے شروع کی، وہ ہے پرانی وقف جائیدادوں کی بحالی۔ جس کے تحت سال ۲۰۱۸ء کے آخر تک تقریباً ۵ہزار۲سو۵۰ وقف املاک کو بحال کیا گیا۔ یہ بحالی ’بحال کرو، چلاؤ، منتقل کرو‘ یا ’تعمیر کرو، کرایہ پر دو/چلاؤ، منتقل کرو‘ جیسے طریقوں پر کی گئی۔
آج ترکیہ میں وقف کی پانچ مختلف اقسام ہیں، جو کہ ’مضبوط‘ (mazbūt) وقف، نئے وقف، ’ملحق‘ (mülhak) وقف، اقلیتی وقف اور ’ارسادی‘ (irsādī) وقف ہیں۔ اگست ۲۰۱۹ء تک ترکیہ میں ۵۲ہزار مضبوط (mazbūt) وقف، ۵ہزار۲سو۶۸ نئے وقف — جو ۱۹۲۶ء کے بعد قائم ہوئے ہیں، ۲۵۶ ملحق (mülhak) وقف، اور غیر مسلم اقلیتی کمیونٹیز کے ۱۶۷ وقف موجود تھے۔
یہ بھی واضح رہے کہ ’مضبوط (mazbūt) وقف‘ وہ وقف ہیں، جن کا انتظام اور نمائندگی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فاؤنڈیشنز (DGF) کے ذریعے کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی منتظم نہیں تھا جب سے انھیں ریاست کے ہاتھوں منتقل کیا گیا تھا۔ ان کی آمدنی کا اہم ذریعہ ان جائیدادوں سے کرائے کی آمدنی ہے، اوریہ آمدنی ان مقاصد کے لیے، جو ان کے وقف ناموں (waqfiyah) میں درج ہیں، جیسے کہ قرآن کی تلاوت، غریبوں، محتاجوں اور مسافروں کو خوراک فراہم کرنا، ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے طلبہ کو وظائف دینا، یتیموں اور معذوروں کو ماہانہ وظیفے دینا، تعلیمی، صحت کی دیکھ بھال اور سماجی امداد کے ادارے اور سہولتیں قائم کرنا، عوام کے لیے سوپ کچن چلانا، اور غریب اور محتاج غیر ملکی مریضوں کا علاج کروانا وغیرہ پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ’ملحق (mülhak) وقف‘ سلطنت عثمانیہ کے ان اوقاف کو کہا جاتا ہے، جو ۱۹۲۶ء سے قبل قائم ہوئے تھے اور آج بھی ان کے بانیوں کی نسلوں کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔
اگست ۲۰۱۹ء تک، ترکیہ میں ۵ہزار ۲سو ۶۸ نئے وقف قائم ہوئے ہیں، جو ۱۹۲۶ء کے بعد بنائے گئے ہیں۔ اسی نئے وقف کے تحت فی الحال، ترکیہ میں ۷۳ وقف یونی ورسٹیاں اور چار پیشہ ورانہ اعلیٰ تعلیم کے اسکول ہیں، جن میں ۸ لاکھ ۲۸ ہزار ۶ سو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ وقف اسلامی تعلیم کے لیے بھی قائم کیے گئے ہیں، جب کہ کئی دوسرے وقف ہیں جنھوں نے پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے ساتھ ساتھ پری اسکول کے ادارے بھی قائم کیے ہیں، جن کا ترک معیشت پر قابلِ ذکر اثر ہے۔ کچھ وقف ایسے بھی ہیں جو ثانوی اور تیسری سطح کی تعلیم میں کامیاب طلبہ کو وظائف دیتے ہیں۔ کئی وقف ایسے قائم کیے گئے ہیں جو تعلیم کی حمایت اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے لیے آگاہی اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکیہ کے معاصر وقف نظام کی ایک اہم اور جدید ترین شکل ’وقف کمپنیوں‘ کی صورت میں سامنے آئی ہے، جو نہ صرف فلاحی مقاصد کے لیے قائم کی جاتی ہیں بلکہ معاشی قدر بھی پیدا کرتی ہیں، اور یوں وقف کی روایت کو ایک نئے انداز میں آگے بڑھاتی ہیں۔
اقلیتی (کمیونٹی) یعنی غیرمسلموں کے ’وقف‘ ترکیہ کی سرحدوں میں بسنے والی غیر مسلم برادریوں نے ترک جمہوریہ کے قیام سے قبل قائم کیے تھے۔ آج کے دور میں، ترکیہ میں کل ۱۶۷ اقلیتی اوقاف رجسٹر ہیں، جو رومن آرتھوڈوکس، آرمینیائی آرتھوڈوکس، کیتھولک، اور یہودی برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اوقاف چرچوں، خانقاہوں، یا اسکولوں کے لیے وقف ہیں۔ انھیں ’جماعت وقف‘ (Cemaat Vakıfları) بھی کہا جاتا ہے۔
ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فاؤنڈیشنز (DGF) کی ویب سائٹ کے مطابق، وہ اوقاف جن کے مرکزی دفاتر بیرونِ ملک واقع ہیں اور جن کی ترکیہ میں شاخیں یا نمائندہ دفاتر موجود ہیں (یعنی غیر ملکی اوقاف)، وہ بین الاقوامی سطح پر تعاون کو مفید سمجھنے کی صورت میں، باہمی اصول (ریسپروسٹی) کے تحت، وزارتِ خارجہ اور بوقتِ ضرورت دیگر متعلقہ اداروں کی رائے لینے کے بعد، وزارتِ داخلہ کی اجازت سے ترکیہ میں سرگرمیوں، شراکت، شاخ یا نمائندہ دفاتر کے قیام، اعلیٰ ادارے (فیڈریشن وغیرہ) کے قیام، پہلے سے قائم اعلیٰ اداروں میں شمولیت یا پہلے سے قائم اوقاف کے ساتھ تعاون کرسکتے ہیں۔
اس کے علاوہ، بیرونِ ملک قائم اوقاف کی ترکیہ میں شاخیں یا نمائندہ دفاتر کھولنے اور یہاں سرگرمیاں یا شراکت داری قائم کرنے کے لیے اجازت دینے کے معاملات پر انجمنوں سے متعلق قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس دائرہ کار میں، غیر ملکی اوقاف سے متعلق تمام اُمور و کارروائیاں ’سول سوسائٹی سے تعلقات کی جنرل ڈائریکٹوریٹ ‘ کے ذریعے طے قوانین کے تحت انجام دی جاتی ہیں۔
ترکیہ میں نقد وقف کے ذریعے قائم کردہ وقف بینک
ترکیہ میں ’نقد وقف‘ (Cash Waqf) کا ایک منظم اور مضبوط نظام بھی موجود ہے، جسے ابتدائی طور پر شہریوں کو جائیداد اور دیگر مقامی ٹیکسوں کی ادائیگی میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ان اوقاف کے ذریعے عوام سے فنڈز جمع کیے جاتے تھے، اور ٹیکس ریلیف کے علاوہ ان فنڈز کو مقامی سطح پر مختلف سماجی اور کمیونٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔
ڈاکٹر اوزان مراشلی کے مطابق، ۱۹۵۴ء میں ’ڈیموکریٹ پارٹی‘ کے دورِ حکومت میں نقد اوقاف کے سرمائے کو استعمال کرتے ہوئے وقف بینک (Vakıf Bank) قائم کیا گیا تھا۔ آج ’وقف بینک‘ ،ترکیہ کے ہر شہر میں اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے، اور اثاثوں کے حجم کے لحاظ سے ملک کا دوسرا سب سے بڑا بینک شمار ہوتا ہے۔ وقف بینک کے علاوہ ترکیہ میں ایک اور بینک ’وقف پارٹی سپیشن بینک‘ (Vakıf Katılım Bank) بھی موجود ہے، جو ایک شراکت داری (اسلامی) بینک کے طور پر کام کرتا ہے، جس سے وقف کے ورثے اور اس کے ترکیہ کے جدید مالیاتی نظام میں کردار کو مزید وسعت ملتی ہے۔
آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ترکیہ میں ایک اور ’ایش بینک‘ (İş Bankası) بھی وقف بینک کی حیثیت رکھتا ہے، جو ہندستانی مسلمانوں کی طرف سے ۱۹۲۲ء میں بھیجے گئے عطیات کی مدد سے قائم کیا گیا تھا۔میرے پاس موجود تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آبائی شہر چمپارن (بہار) کے لوگ بھی عطیہ دہندگان میں شامل تھے۔ مصطفےٰ کمال پاشا نے اس فنڈ کو جنگ کے بعد ملک کے زخموں پر مرہم رکھنے کے ساتھ ساتھ اسی فنڈ کی بنیاد پر ’ایش بینک‘ قائم کیا۔
انقرہ میں وقف میوزیم کا آنکھوں دیکھا حال
ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ کی ’ملکہ خاتون مسجد‘ کے بائیں جانب ’وقف ورکس میوزیم‘ ہے۔ اس میوزیم کے اندر جاکر معلوم ہوا کہ یہ میوزیم ۲۰۰۹ء میں یورپی میوزیم فورم کی جانب سے نامزد کیا گیا۔اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ترکیہ کے وقف نظام سے متعلق کئی اہم کتابوں، مخطوطات اور وقف پر نکلنے والے میگزین کا دیدار ہوتا ہے، جسے پڑھ کر ترکیہ کے وقف کے نظام کو کافی بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ان میں زیادہ تر مواد ترکی زبان میں ہے، تاہم یہ وقف کے نظام پر گہری بصیرت فراہم کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اندر کی جانب بڑھتے ہیں، میوزیم میں قالین، دری، قدیم گھڑیاں، تاریخی برتن، خطاطی کے فن پارے اور نایاب مخطوطات سمیت مختلف نادر اشیاء کی نمائش کی گئی ہے۔
اسی میوزیم میں مولانا جلالالدین رومی کی مثنوی، جسے ۱۲۷۲ ہجری میں درویش مہمت فہمی [محمد فہمی]نے فارسی میں لکھا تھا، موجود ہے۔ اس میوزیم میں آکر ہی پتہ چلا کہ ۱۶ویں صدی سے لے کر ۲۰ویں صدی کی پہلی سہ ماہی تک، مسلمانوں کے نزدیک سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال بلاانقطاع سلطنتِ عثمانیہ سے مکہ مکرمہ بھیجا جاتا تھا۔ اس موقع پر ترکیہ میں ایک عظیم الشان تقریب ’سُرّہ-ہمایوں‘ کے نام سے منعقد کی جاتی تھی۔ ابتدا میں غلافِ کعبہ، جسے 'ستارہ ' بھی کہا جاتا ہے، مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ تاہم، سلطان احمد اول کے دورِ حکومت میں اس کی تیاری سلطنتِ عثمانیہ کو منتقل کر دی گئی، جہاں یہ استنبول کے شاہی محل کے زیرِ نگرانی تیار ہوتا اور پھر سُرّہ عَلائی (وہ فوجی دستہ جو عثمانیوں کی جانب سے جمع کردہ امداد کعبہ لے جاتا تھا) کے ذریعے خانہ کعبہ تک پہنچایا جاتا۔
یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ اٹھارھویں صدی کے کعبہ کے دو غلاف، جو نیوشہرلی داماد ابراہیم پاشا، جو ایک مشہور وزیر اعظم تھے، نے نیوشہر میں بنائی گئی قُرشُنلو مسجد کو حج کے بعد وقف کیے تھے۔ یہ دونوں غلاف ۲۰۰۳ء میں نیوشہر کی قُرشُنلو مسجد سے چوری کر لیے گئے تھے اور جنرل ڈائریکٹوریٹ آف فائونڈیشنز نے اس کی اطلاع ملکی اداروں، تنظیموں اور دیگر ممالک کو دی۔ جب ان غلافوں کو لندن میں ایک قدیم اشیاء کے تاجر فرانسسکا گیلوے کو فروخت کرنے کی کوشش کی گئی، تو تاجر نے ’ٹوپ کاپی محل‘ کے میوزیم سے ان اشیاء کے بارے میں رائے مانگی۔ میوزیم کی ڈائریکٹریٹ نے فاؤنڈیشنز جنرل ڈائریکٹوریٹ کو مطلع کیا اور اس موضوع پر تحقیقات کے بعد ۲۴ فروری ۲۰۰۴ء کو ترک سفارت خانے نے یہ تاریخی کعبہ کے غلاف فاؤنڈیشنز جنرل ڈائریکٹوریٹ کو واپس کردیے۔ اب یہ دونوں غلاف اسی میوزیم میں محفوظ ہیں۔
میوزیم میں موجود خوب صورت قالینوں اور دریوں کو دیکھ کر میں حیران ہوا کہ ان کا وقف سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دریافت پر معلوم ہوا کہ ماضی میں جنازوں کے دوران میت کے تابوت پر قالین بچھانا عام رواج تھا، اور تدفین کے بعد اہلِ خانہ یہ قالین بطورِ صدقہ مسجد کو وقف یا عطیہ کردیتے تھے۔ یہ قالین، جو نہ صرف نفیس ڈیزائن کے حامل ہوتے بلکہ جذباتی اور تاریخی اہمیت بھی رکھتے تھے، اب اس میوزیم میں محفوظ اور نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ، سیکڑوں قالین مزید بھی محفوظ ہیں جو فی الحال نمائش کا حصہ نہیں ہیں۔اس میوزیم کا بنیادی مقصد ان لوگوں کی یادگاروں کو محفوظ رکھنا اور پیش کرنا ہے، جنھوں نے وقف کی تہذیب کو پروان چڑھایا۔ اس کے ذریعے نئی نسلوں کو وقف کی عظمت، اس کی معاشرتی اہمیت اور اس کے دیرپا اثرات سے روشناس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
سعودی عرب میں وقف کا نظام
سعودی عرب میں بھی وقف مینجمنٹ کا ایک بہترین نظام موجود ہے۔ یہاں کی ’جنرل اتھارٹی برائے اوقاف‘ (GAA) وقف املاک کی دیکھ بھال اور ترقی کی نگرانی کرتی ہے، تاکہ انھیں اقتصادی اور سماجی ترقی کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے، اور ساتھ ہی واقف کی نیت و ارادے کو بھی محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہاں وزارت حج و اوقاف اور وقف کی اعلیٰ کونسل بھی موجود ہے۔
سعودی عرب نے وقف کے نظام کو بہت سنجیدگی سے منظم کیا ہے۔ ۱۹۶۶ء میں سعودی عرب نے اس مقصد سے وقف محکمہ قائم کیا۔ بنیادی طور پر، وقف کا یہ محکمہ مختلف وقف سے متعلقہ امور کو سنبھالنے کا ذمہ دار ہے، جیسے کہ وقف املاک کی منصوبہ بندی اور ترقی، منظور شدہ وقف پروگراموں کا فروغ، وقف کی آمدنی کو مستحق افراد میں تقسیم کرنا۔
یہ بات پیش نظر رہے کہ سعودی عرب نے وقف کی نگرانی اور ترقی کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے ہیں، جن میں ’وزارت حج و اوقاف‘ کا قیام بھی شامل ہے۔ یہ وزارت وقف کو ’واقف‘ کی شرائط کے مطابق فروغ دینے اور نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اسی کے ساتھ، وقف پالیسی کی نگرانی کے لیے حکومت نے ایک ’وقف اعلیٰ کونسل‘ قائم کی، جس کی صدارت وزیر حج و اوقاف کرتے ہیں۔ اس کونسل کے ارکان میں وزارت انصاف کے اسلامی قانون کے ماہرین، وزارت معیشت و خزانہ کے نمائندے، محکمہ نوادرات کا ڈائریکٹر، اور تین افراد اہل دانش اور صحافیوں میں سے شامل کیے گئے ہیں۔ یہ کونسل وقف کی ترقی سے حاصل شدہ آمدنی کے استعمال اور ’واقف‘ کی شرائط کے مطابق وقف کے فروغ کے اقدامات کے تعین کا اختیار رکھتی ہے۔
سعودی عرب میں وقف کی مختلف اقسام موجود ہیں، جیسے ہوٹل، زمینیں، رہائشی عمارتیں، دکانیں، باغات، اور عبادت گاہیں۔ ان میں سے کچھ ’اوقاف‘ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جسے مقدس و محترم شہروں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، وقف سے حاصل ہونے والے تمام فوائد کا مقصد ان دونوں مقدس شہروں کی ترقی ہے، جیسے رہائشی مکانات کی تعمیر، مسجد الحرام اور مسجد نبویؐ کے گرد ہوٹلوں کی تعمیر، اور دیگر سہولیات جو حجاج کرام اور عمرہ زائرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ عوام براہِ راست ان وقف املاک سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں، جنھیں حکومت نے منظم کیا ہے، یہاں تک کہ بیرون ملک سے آنے والے حجاج کرام بھی ان سہولیات سے مستفید ہوتے ہیں اور مکہ و مدینہ میں جاری ترقی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق۲۰۲۰ء تک، وہ وقف املاک جو جنرل اتھارٹی آف اوقاف (GAA) کے تحت منظم کی جا رہی تھیں، ان کی مجموعی مالیت ۶۳؍ ارب امریکی ڈالر تھی۔
سعودی عرب میں وقف کا ایک منظم اور مؤثر نظام موجود ہے، جس کا ہندوستان میں رائج وقف نظام سے کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے بھی، سعودی عرب میں جمہوریت کا نظام نہیں ہے، جب کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ اس لیے انڈین حکمرانوں کی یہ ساری منطق بے معنی اور غیرحقیقی اور مضحکہ خیز ہے کہ ’’ترکیہ و سعودیہ میں بھی تو وقف ریاست کے کنٹرول میں ہے‘‘۔ ہم نے دونوں ممالک میں اوقاف کی نوعیت اور عملی صورت بیان کردی ہے جن کا نام لے کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔
یہ سوال پیدا ہوتا ہے: ’’امریکا کی نام نہاد ’وار آن ٹیرر‘ کیا ختم ہو گئی ہے ؟ یہ امریکی کھیل کب تک جاری رہے گا ؟ اس جنگ کی نوعیت اور شکل کیا ہے ؟‘‘
اُردن کی حکومت نے ۲۳؍ اپریل کی سہ پہر ملک کی سب سے مؤثر جماعت ’اخوان المسلمون‘ پر مکمل پابندی عائد کرنے سے ایک ہفتہ پہلے اس کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم چلا رکھی تھی، اور پھر پابندی عائد کرتے ہی اس کے تمام دفاتر کو بند کرکے اس کے اثاثے ضبط کر لیے۔ وزیرِ داخلہ مازن فرایہ نے اعلان کیا: ’’یہ فیصلہ جماعت کے ایک رہنما کے بیٹے کے ہمراہ پندرہ افراد کی گرفتاری کے بعد کیا گیا ہے۔ اخوان المسلمون کی تمام سرگرمیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے اور جو کوئی بھی اس کے نظریات اور کتب کو پھیلائے گا، اسے قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے گی۔ اس پابندی میں جماعت کے دفاتر اور املاک کی بندش اور ضبطی شامل ہے۔ اخوان نے غیرقانونی طور پر اپنا دفتری ریکارڈ تلف کیا ہے‘‘۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر اخوان کی حمایت یا اس کی کسی سرگرمی کو پھیلانے پر بھی پابندی عائد کردی ہے۔
پابندی کے اعلان سے چند گھنٹے پہلے ہی پولیس نے اخوان المسلمون کے مرکزی دفتر کا محاصرہ کرکے تلاشی شروع کردی تھی۔ اخوان کئی عشروں سے اُردن میں قانونی طور پر سرگرم ہے اور تمام بڑے شہروں میں اسے وسیع پیمانے پر عوامی حمایت حاصل ہے۔
اُردن، طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ میں استحکام کی علامت سمجھا جارہا ہے۔ اُردن نے ۱۹۹۴ء میں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ ملک کی نصف سے زیادہ آبادی فلسطینی نژاد ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف عوامی غم و غصے کی لہر موجود ہے، جس کا فائدہ اخوان المسلمون اور اس سے وابستہ جماعتوں کو عوامی حمایت کی صورت میں ملا ہے۔ تھنک ٹینک ’مڈل ایسٹ آئی‘ (MEE) کی ۲۷؍اپریل کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق: ’’اُردن میں اخوان کے خلاف یہ مہم سعودیہ، امارات اور اسرائیل کے مربوط دبائو کے تحت چلائی جارہی ہے۔ یاد رہے گذشتہ ۱۸ ماہ سے اُردن میں اسرائیل کے خلاف تقریباً روزانہ عوامی مظاہرے ہورہے ہیں‘‘۔
اسی طرح مشرق وسطیٰ کے کئی عوامی اور سیاسی و علمی حلقوں نے اخوان المسلمون کے خلاف ان اقدامات کی مذمت کی ہے۔ مغربی ممالک کی انجمنوں نے بھی اس اقدام کو سیاسی دباؤ اور آزادیوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے کہ ایسی کارروائیاں معاشی، سماجی اور سیاسی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہیں اور علاقے میں مزید تناؤ کو جنم دیتی ہیں۔
درحقیقت یہ سب ایک پرانا کھیل دُہرایا جا رہا ہے، جیسا کہ ۲۰۰۳ء میں برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر اور امریکی صدر بش نے عراق کو صریحاً جھوٹے اور بے بنیاد الزامات عائد کرکے لاکھوں انسانوں کے قتل و غارت کا کھیل کھیلا تھا۔اب وہی عالمی سامراجی عناصر مسلم دُنیا میں جگہ جگہ اسلامی قوتوں کو نشانہ بنانے کے لیے من گھڑت الزامات عائد کر کے اور کمزور مسلم حکمرانوں کو ڈرا کر، انھیں اپنے ہی ہم وطنوں کے خلاف ایسے اقدامات پر اُبھارتے ہیں۔
۲۳؍اپریل کی شام تل ابیب سے انٹرنیٹ پر شائع شدہ اخباری اطلاع میں یروشلم پوسٹ نے اخوان پر پابندی کو اطمینان کی نظر سے دیکھتے ہوئے لکھا :’’اخوان المسلمون نے اُردن کی رائے عامہ کو اسرائیل کے خلاف کھڑا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور بڑے پیمانے پر جلسے جلوس منعقد کیے تھے۔ یہ چیز اسرائیل کے لیے خطرہ بڑھا رہی تھی‘‘۔اسی طرح اُردن کی سیاسی اشرافیہ، اخوان کو خارجہ اور داخلہ سطح پر ایک بوجھ سمجھتی ہے اور علاقے کے طاقت ور ملکوں کی خوش نودی حاصل کرنے کے لیے اس سے چھٹکارا پانے اور اسرائیل سے تعلقات بڑھانے میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے امکانات دیکھتی ہے۔
ابتدا میں جو سوال اُٹھایا گیا تھا،وہی سوال سب اہل دل کے لیے غور طلب ہے کہ مسلم دُنیا کے تمام دینی اور قومی حلقے اس نام نہاد جنگ کے علَم برداروں کی اوچھی حرکتوں کو غور سے دیکھیں اور ان کی گھاتوں،وارداتوں کو سمجھیں۔ اظہارِ رائے اور انعقادِ اجتماع اور انجمن سازی پر بڑھتی ہوئی پابندیوں کے بارے میں بیدار رہیں۔
بہت سے والدین اس وقت شدید حیرت اور ندامت محسوس کرتے ہیں، جب ان کے بچّے بڑے ہو کر اپنے بچپن کی تلخ یادوں کا ذکر کرتے ہیں، —خاص طور پر وہ الفاظ جو والدین نے غصے یا مایوسی میں کہے تھے۔ والدین کا حقیقی مقام حاصل کرنا، اور ان ذمہ داریوں کو نہایت درجہ فکرمندی کے ساتھ ادا کرنا ایک مشکل کام ہے۔ لیکن اس راستے پر انسان چل پڑے تو پھر کچھ مشکل بھی نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اپنی خامیوں کو قبول کیا جائے اور اپنی محبت اور اپنے خلوص پر توجہ دی جائے۔
بچوں کی پرورش ایک ایسا سفر ہے جس میں خوشی اور آزمائشیں دونوں شامل ہیں۔ بعض اوقات، دباؤ کے لمحات میں والدین کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، جن پر بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ یہ جملے بظاہر معمولی یا بے ضرر لگتے ہیں، لیکن ایک نفسیات دان کی حیثیت سے میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کی خود اعتمادی اور جذباتی نشوونما پر ان کا بڑا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ آئیے ان سات عام جملوں پر نظر ڈالیں، جو والدین اکثر کہہ دیتے ہیں اور ان کے بچوں پر پڑنے والے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں:
مثال: ’’تم اپنے بھائی کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے؟‘‘
ایسے موازنے بہن بھائیوں کے درمیان رنجش،رقابت، غیر ضروری مقابلے اور بعض اوقات نفرت تک کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ اس سے بچے کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی انفرادیت اور حیثیت نہیں ہے یا وہ والدین کی نظر میں کم تر ہے، جو خود اعتمادی کو مجروح کر سکتا ہے۔
مثال: ’’تم ہمیشہ میری بات بھول جاتے ہو!‘‘
ایسے جملے بچوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتے یا بہتری نہیں لا سکتے، جس سے ان کی خود اعتمادی اور سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ والدین جملے کو یوں کہیں: ’’مجھے لگتا ہے کہ تم بعض اوقات باتیں بھول جاتے ہو، کوئی بات نہیں، آپ اس پر ذرا سی توجہ دیں‘‘۔
مثال: ’’ہمیں امید تھی کہ تم بہتر کرو گے‘‘۔
والدین کا اپنے بچوں سے توقعات رکھنا فطری ہے، لیکن اگر مایوسی کا اظہار رہنمائی یا مدد کے بغیر کیا جائے تو بچے خود کو ناکام محسوس کر سکتے ہیں۔ اس سے ان کے اندر دباؤ اور ناکامی کا خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ والدین حوصلہ افزا الفاظ کا انتخاب کریں جیسے: ’’مجھے معلوم ہے کہ تم محنت کر رہے ہو، چلو دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں؟‘‘
مثال: ’’تم حد سے زیادہ ردِعمل دے رہے ہو‘‘۔
بچوں کے جذبات کو نظر انداز کرنا یا انھیں غیر ضروری قرار دینا، ان کی خود اعتمادی کو متاثر کرسکتا ہے۔ اگر بار بار ایسا ہو تو بچہ اپنے احساسات کو دبانے لگتا ہے اور جذباتی طور پر کمزور ہو سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ والدین اس کے احساسات کو تسلیم کریں، مثلاً: ’’مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات تمھیں تکلیف دے گی، میں آیندہ خیال رکھوں گا‘‘۔
مثال: ’’تم بہت سست ہو‘‘۔
منفی القابات بچوں کے ذہن میں اپنی شخصیت کے بارے میں منفی تصور پیدا کرتے ہیں۔ اگر بچے کو بار بار ’سُست‘، ’بدتمیز‘ یا ’نکمّا‘ کہا جائے، تو وہ واقعی اپنے بارے میں ایسا ہی سوچنے لگتا ہے، جو اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ والدین مسئلے پر بات کریں، نہ کہ شخصیت پر، مثلاً: ’’مجھے لگتا ہے کہ تمھیں تھوڑی مزید محنت کرنی چاہیے، میں تمھاری مدد کر سکتا ہوں‘‘۔
مثال: ’’دیکھو تمھارا دوست کتنا اچھا کر رہا ہے، تم ویسا کیوں نہیں کر سکتے؟‘‘
ایسے موازنے بچوں میں احساسِ کمتری پیدا کرتے ہیں اور انھیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کبھی ’کافی اچھے‘ نہیں ہیں۔ یوں بچوں میں بے جا مقابلے اور عدم تحفظ (insecurity) کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ والدین بچے کی اپنی صلاحیتوں پر توجہ دیں اور کہیں: ’’میں جانتا ہوں کہ تم محنت کر رہے ہو، چلو مل کر دیکھتے ہیں کہ تمھیں کہاں بہتری کی ضرورت ہے؟‘‘
مثال: ’’کاش! تم پیدا ہی نہ ہوتے!‘‘
غصے اور جھنجھلاہٹ میں کہے گئے سخت اور تلخ الفاظ بچے کی شخصیت پر گہرے، اَنمٹ منفی نفسیاتی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ ایسے جملے بچے میں یہ احساس پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ ناپسندیدہ ہے یا والدین اس سے محبت نہیں کرتے، یا یہ کہ وہ گھر میں ایک فضول اور اضافی وجود ہے۔ اگر والدین کو غصہ آرہا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں اور بعد میں ذرا نرمی سے مسئلے پر بات کریں۔ اگر غلطی سے کوئی تکلیف دہ بات کہہ بھی دیں تو ان کا اپنے بچّے سے معذرت کرنا بھی ضروری ہے، مثلاً: ’’مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایسا کہا، میں غصے میں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا‘‘۔
والدین بننا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مایوسی یا غصے کے لمحات ہر گھر میں آتے ہیں، مگر ہمارے الفاظ کا بچوں کی ذہنی اور جذباتی صحت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی بات چیت میں نرمی، صبر اور محبت کا عنصر شامل کریں، تو ہم اپنے بچوں کی خود اعتمادی کو بڑھا سکتے ہیں اور انھیں ایک مضبوط، مستحکم اور باوقار شخصیت میں ڈھال سکتے ہیں۔ اپنی جگہ پر تو والدین بھی کامل (Perfect) نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے الفاظ اور رویے میں شعوری بہتری لا کر اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ اور محبت بھرا متوازن اور خوش گوار ماحول ضرور بنا سکتے ہیں۔(انگریزی سے ترجمہ: ادارہ)
سوال : اگر ہمارے پیش رو لغزشوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے تو ہمارا دامن کیسے پاک رہ سکتا ہے اور اقامت ِدین کے لیے ہم میں جرأت عمل کیسے پیدا ہوسکتی ہے؟
جواب : انسان جب تک انسان ہے،اس کی سعی بشریت کے تقاضوں اور محدودیتوں سے پاک نہیں ہوسکتی۔ ہر شخص کو اپنی حد تک اپنا فرض بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اﷲ سے دُعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں ارادی لغزشوں سے بچائے اور غیر ارادی لغزشوں کو معاف فرمائے۔
سوال : تمام عالم ِاسلام کی اسلامی تحریکوں کو متحد کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟
جواب : اس وقت بدقسمتی سے تمام مسلمان ملکوں میں قومیت پرستی کا دور دورہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بات ممکن نہیں ہے۔ کم و بیش تمام مسلم ممالک کے سربراہ اپنے ملکوں میں تحریک ِاسلامی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس صورت میں وہ متحد ہو کر اسلامی تحریکوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا، فی الوقت اتنا ہی کافی ہے کہ یہ تحریکیں صحیح خطوط پر چلتی رہیں اور ایک دوسرے سے صِرف واقفیت اور ہمدردی رکھیں۔
یہ بات قابلِ غور ہے کہ انبیا علیہم السلام کے مقابلے میں اُٹھ کر باپ دادا کی تقلید کا جھنڈا بلند کرنے والے ہر زمانے میں اپنی قوم کے کھاتے پیتے لوگ ہی کیوں رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی حق کی مخالفت میں پیش پیش اور قائم شدہ جاہلیت کو برقرار رکھنے کی کوشش میں سرگرم رہے، اور وہی عوام کو بہکا اور بھڑکا کر انبیا علیہم السلام کے خلاف فتنے اُٹھاتے رہے؟
اس کے بنیادی وجوہ دو تھے:
ایک یہ کہ کھاتے پیتے اور خوش حال طبقے اپنی دُنیا بنانے اور اُس سے لطف اندوز ہونے میں اِس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ حق اور باطل کی، بزعمِ خویش ، دُور ازکار بحث میں سر کھپانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اُن کی تن آسانی اور ذہنی کاہلی انھیں دین کے معاملے میں انتہائی بے فکر، اور اس کے ساتھ عملاً قدامت پسند (Conservative) بنادیتی ہے، تاکہ جو حالت پہلے سے قائم چلی آرہی ہے، وہی قطع نظر اس سے کہ وہ حق ہے یا باطل، جوں کی تُوں قائم رہے اور کسی نئے نظام کے متعلق سوچنے کی زحمت نہ اُٹھانی پڑے۔
دوسرے یہ کہ قائم شدہ نظام سے اُن کے مفاد پوری طرح وابستہ ہوچکے ہوتے ہیں اور انبیا علیہم السلام کے پیش کردہ نظام کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں وہ بھانپ جاتے ہیں کہ یہ آئے گا تو ان کی چودھراہٹ کی بساط بھی لپیٹ کر رکھ دی جائے گی اور ان کے لیے اکلِ حرام اور فعل حرام کی بھی کوئی آزادی باقی نہ رہے گی۔
(’تفہیم القرآن‘، سیّدابوالاعلیٰ مودودی، ترجمان القرآن، مئی ۱۹۶۵ء، ص ۲۱)