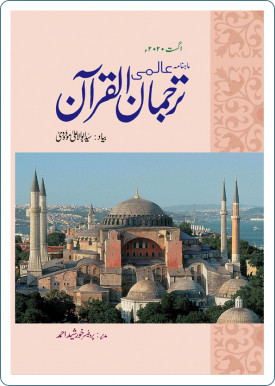
تاریخ قوموں کا حافظہ اور ان کے نشیب و فراز کی داستان کا آئینہ ہے۔ اس میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں، جنھیں تاریخی موڑ کہا جاتاہے۔ ۲۴جولائی ۲۰۲۰ء ترکی اور عالمِ اسلام کی تاریخ میں ایسا ہی ایک موڑ ہے۔
’آیا صوفیہ‘ [Hagia Sophia: مقدس دانش] جس میں یکم جون ۱۴۵۳ء کو پہلی نمازِ جمعہ کا انعقاد ہوا تھا اور جو سلسلہ ۱۹۳۱ء میں اس وقت تک جاری رہا، جب ترکی کے نئےسیکولر حاکم مصطفےٰ کمال [م: ۱۹۳۸ء] نے ریاستی جبر کے ذریعے مسجد کو مقفل کیا، اور پھر ۱۹۳۵ء میں اسے عجائب گھر (میوزیم) بنادیا۔ اس طرح ۸۸سال تک یہ مسجد اذان اور سجدوں سے محروم رہی۔ الحمدللہ، ثم الحمدللہ ، ۲۴جولائی ۲۰۲۰ء کو آیا صوفیہ کی رونق ایک بار پھر اذان، خطبے اور نماز سے بحال ہوئی اور مسجد میں اور اس کے نواح میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد افراد نے ربِ کریم کا بہ چشم تر شکر ادا کیا، جب کہ ساری دنیا کے مسلمان عوام نے ان کی آواز سے ہم آواز ہوکر شکر اور مسرت کا اظہار کیا۔
۲۹ مئی ۱۴۵۳ء فتح قسطنطنیہ کا یادگار لمحہ ہے۔ پھر جس طرح یکم جون ۱۴۵۳ء آیا صوفیہ کے ترکی دولت ِ عثمانیہ کے روحانی قلب بننے کا یادگار دن ہے، اسی طرح ۲۴جولائی ۲۰۲۰ء کے روز مسجد کی بحالی، مسلم تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ یہ ہراعتبار سے ایک عظیم ظلم کی تلافی اور مسلمانوں کے ایک بنیادی دینی اور تہذیبی حق پر دست درازی کا خاتمہ ہے۔ اسے کسی مسجد اور چرچ کے تنازعے کی شکل دینا تاریخی بددیانتی ہی نہیں، سیاسی دھوکا دہی بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اختصار سے اس مسئلے کی اصل حقیقت کو واضح کریں تاکہ اس تاریخی تبدیلی کو اس کے اصل پس منظر میں دیکھا اور سمجھا جاسکے۔
بازنطینی (Byzantine) دورِ حکومت میں ’آیا صوفیہ‘ بلاشبہہ ایک چرچ تھا، جو تاریخی اعتبار سے بازنطینی سلطنت کے اہم مقام کی حیثیت رکھتا تھا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ محض ایک چرچ نہیں تھا بلکہ سیاسی اقتدار کا مرکز اور فوجی اور استعماری کارروائیوں کی فیصلہ گاہ بھی تھا۔ اس طرح بازنطینی اور یونانی آرتھوڈکس چرچ کی اصل قوت و اقتدار (seat of power) کی حیثیت رکھتا تھا۔(آیا صوفیہ کے زیرعنوان مضمون (history.com) میں لکھا ہے: ’’چونکہ یونانی آرتھوڈوکس، بازنطینی سلطنت کا سرکاری مذہب تھا، آیا صوفیہ کو اس مذہب کا مرکزی چرچ(گرجاگھر) سمجھا جاتا تھا، اوراسی لیے یہ وہ جگہ طے پاگئی تھی، جہاں نئے شہنشاہ کی رسم تاج پوشی سرانجام دی جاتی تھی۔ یہ تقریبات گرجے کے درمیانی حصے یا نافِ کلیسا میں منعقد ہوتی تھیں۔ یہ دراصل رنگارنگ پتھروں پر مشتمل سنگ مرمرسے بنا ہوا مذکورہ حصہ ہے، جو فرش میں آپس میں بل کھاتے ہوئے گندھے ہوئے گول ڈیزائن کی شکل میں ہے۔ آیا صوفیہ نے اپنے وجود کے ۹۰۰برسوں کے زیادہ تر حصے میں بازنطینی ثقافت اور سیاست میں نہایت مرکزی کردار ادا کیا ہے‘‘۔)
یہی وجہ تھی کہ سلطان محمدفاتح نے جہاں عیسائیوں اور تمام مذہبی اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور ان کے مذہبی اداروں اور عبادت گاہوں کو آزادانہ کام کا پورا پورا موقع دیا، وہیں اس سیاسی اور مذہبی مرکز کو مسجد کبیر کی حیثیت سے عثمانی حکومت کا دینی مرکز قرار دیا۔ البتہ انھوں نے یہ کام غیرمعمولی احتیاط کے ساتھ کیا۔ انھوں نے یہ اقدام سیاسی تسلط کی قوت کو قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اخلاقی برتری قائم کرنے اور اسلام کی اعلیٰ روایات کا احترام کرتے ہوئے تاریخی روایات کے مطابق اپنی ذاتی دولت سے اس جگہ کی قیمت ادا کرکے خریدا، اور اسے مسجد اور عبادت، تعلیم و تحقیق اور دعوت کے لیے وقف کر دیا۔
اب مسجد کی بحالی کا جو فیصلہ ہوا ہے، وہ ترکی کی اعلیٰ ترین عدالت کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں ہوا ہے، اور جس میں مصطفےٰ کمال اور اس کی کابینہ کے ۱۹۳۵ء کے فیصلے کو غیرقانونی اور ناجائز قرار دیا گیا ہےاور ملکی قانون کے مطابق وقف کی بحالی اور وقف کے اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت سے بحال کیا گیا ہے۔
جہاں تک میں اس مسئلے کا مطالعہ اور تجزیہ کرسکا ہوں، مجھے اس امرکے اظہار میں ذرا بھی تردّد نہیں کہ قانون، اخلاق، اسلامی روایات اورعالمی تعامل، ہراعتبار سے یہ اقدام صحیح اور قابلِ فخر ہے۔ چند حقائق مختصراً عرض ہیں:
اصلاً یہ عمارت ایک Pagan (پاگان: غیرعیسائی بت پرست) قوم کی عبادت گاہ تھی جس میں بتوں اور اَرواح کی پوجا ہوتی تھی۔ عیسائی حکمران جسٹینین نے اس پاگان عبادت گاہ کو ختم کرکے یہاں پر چرچ بنایا اور پرانی عبادت گاہ کے کچھ حصوں کو اس میں شامل کرلیا۔ پھر یہ عمارت مختلف اَدوار سے گزرتی ہوئی، جس میں عیسائیت کے دو بڑے فرقوں کے درمیان اور رومن ایمپائر اور بازنطینی ایمپائر کے عرصۂ تسلط میں ادل بدل ہوتا رہا ہے۔ آخرکار آیاصوفیہ بازنطینی اور یونانی آرتھوڈکس چرچ کا مرکز بنی۔ بلاشبہہ یہ عمارت فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اور مغرب اور مشرق دونوں کے نوادرات اس کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں کہ اوّلاً یہ ایک چرچ تھا۔ درست بات یہ ہے کہ یہ جگہ اوّلاً ایک غیرعیسائی بت خانہ تھا، جسے زبردستی چرچ بنایا گیا اور جو بالآخر بازنطینی سلطنت کا سیاسی مرکز بنا، جسے سلطان محمد فاتح نے ۲۹مئی ۱۴۵۳ء کے فاتحانہ اقدام کے ذریعے اسلامی قلمرو کا حصہ بنالیا ۔
اس پس منظرمیں چرچ کی بحالی یا چرچ کے زبردستی مسجد بنانے کے دونوں دعوؤں میں کوئی صداقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۴۵۳ء سے تاحال کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کبھی یورپی اقوام یا چرچ کے نمایندوں نے اس چرچ کی بحالی کا کوئی دعویٰ کیا ہو، حتیٰ کہ ۲۴جولائی کو ۱۹۲۳ء کے ’معاہدہ لوزان‘ (Treaty of Lausanne) تک میں، جس کے تحت ترکی کی موجودہ حکومت وجود میں آئی اور دولت عثمانیہ کی زمینوں اور علاقوں سے ترکی کو محروم کرکے اس کے لیے نئی اور محدود سرحدیں مقرر کی گئیں، اور غیرمسلموں اور ان کے مذہبی آثارکے سلسلے میں سخت احکامات ضبط ِ تحریر میں لائے گئے۔اس میں بھی جہاں چرچوں، کنیسہ (Synagogues)، قبرستانوں، اقلیتوں، مذہبی اور ثقافتی اداروں کے تحفظ کے بارے میں جو چار دفعات (۴۶، ۴۲، ۴۰، ۴۸) ہیں ،ان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ گویا اسے مسجد تسلیم کیا جانا ایک بدیہی امر تھا۔
واضح رہے کہ ۱۹۱۹ء میں جب استنبول پر برطانیہ، فرانس، یونان اور اتحادی اقوام کا قبضہ تھا تو یونان کی افواج نے آیا صوفیہ میں گھسنے کی کوشش کی۔ اس پر شکست خوردہ ترک فوج اور عوام اس کے آگے سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوگئے، اور سرفروشی کی لازوال مثال پیش کرتے ہوئے انھیں اس پر قبضہ نہیں کرنے دیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جذبۂ ایمانی سے سرشار ان مجاہدین نے ایک مسجد ہی کے دفاع کے لیے قربانی دی تھی۔ اس صورتِ حال میں دوسری یورپی اقوام نے بھی یونان کو اس سے روکا اور یوں آیا صوفیہ کے مسجد بنانے کی حقیقت کو تسلیم کرلیا گیا۔ان حقائق کی روشنی میں آیاصوفیہ کے مسجد ہونے کا انکار ایک تاریخی بددیانتی اور دھوکا ہے۔
یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ عیسائی مذہب میں چرچ کی ابدی حیثیت نہیں۔ چرچ ایک خاص عمل کے ذریعے عبادت گاہ بنتا ہے اور اسے ایک خاص عمل کے ذریعے اس حیثیت سے خارج بھی کیا جاسکتا ہے۔ زمانہ حال تک صدیوں سے یہ عمل جاری ہے۔ آج بھی ہزاروں چرچ ہیں، جو فروخت ہوئے ہیں۔ یورپ اور امریکا میں گذشتہ ۵۰برسوں میں سیکڑوں چرچ مسلمانوں نے خرید کر ان میں مسجد، مدرسہ اور اسلامی مراکز قائم کیے ہیں۔ اس طرح بہت سے چرچ، یہودیوں نے خرید کر سینی گاگز (کنیسہ) بنائے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ کئی چرچ تو جواخانے (casino)، شراب خانے، تھیٹر وغیرہ بنانے کے لیے بھی فروخت کیے گئے ہیں، جب کہ مسجد کے سلسلے میں اسلامی فقہی پوزیشن یہ ہے کہ جس جگہ ایک بار جائز طور پر مسجد بن جائے اور اس مقصد کے لیے استعمال ہو، وہ ذاتی ملکیت میں نہیں آسکتی اور اس کی خریدوفروخت کا دروازہ بند ہوجاتا ہے۔ مسجد کی ہرصورت میں حفاظت اجتماعی ذمہ داری ہے۔ معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ پہلو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔
اسی طرح یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آیا صوفیہ کی پندرہ سو سالہ تاریخ میں اس پر جب بھی عملاً سخت وقت آئے تو وہ خود عیسائیوں ہی کے اپنے ہاتھوں آئے ہیں ۔ تین بار اس کو آگ لگائی گئی اور بادشاہ کے قانون کے تنازعے کے دوران چرچ ہوتے ہوئے اس کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ پھر سب سے زیادہ تباہی ۱۲۰۴ء میں اس موقعے پر ہوئی جب رومن ایمپائر نے کنسٹنٹن پول پر قبضہ کیا اور چوتھے کروسیڈ (Crusade 4) کے موقعے پر، عیسائیت کے ان دونوں فرقوں کی جنگ کے بعد رومیوں کا تسلط قائم ہوا۔ اس وقت آیا صوفیہ کی بے حُرمتی اور تباہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔
مؤرخ لکھتے ہیں:
یہ محض ایک حملہ نہیں تھا۔ شہر کو تین روز تک بُری طرح لوٹ مار اور تاراج کا نشانہ بنایا گیا۔ جنگجوؤں نے آیا صوفیہ میں بھی لُوٹ مار کی۔(حوالے کے لیے دیکھیے: History of Hagia Sophia پر مضمون history.com میں، اور جیفری دوویلار دوین [م: ۱۲۱۳ء] کی کتاب On the Conquest of Constantionple میںاس تباہی اور لُوٹ مار کی تفصیل دی گئی ہے۔)
عیسائی مؤرخین نے جو تفصیلات لکھی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آیا صوفیہ چرچ میں قتل و غارت گری، عمارت کو نقصان پہنچانے، پادریوں کا خون بہانے اور قیمتی چیزوں کو لوٹ لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔جو بے حُرمتی خود عیسائیوں نے اپنے چرچ کی کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔
اس کے مقابلے میں جب سلطان محمدفاتح نے آیا صوفیہ میں قدم رکھا، تو اس نے اس جگہ سے خاک اُٹھا کر اپنے عمامے اور کپڑوں پہ ڈالی، عاجزی کے ساتھ عمارت میں داخل ہوا۔ عمارت میں جن لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی، انھیں عام معافی دی اور وہی الفاظ استعمال کیے جو فتح مکہ کے وقت حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، یعنی لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ۰ۭ (یوسف ۱۲:۹۲)، آج کے دن تم پر بازپُرس نہیں۔ پھر آیا صوفیہ کی مذہبی نسبت سے احترام کا رشتہ قائم کیا اور اپنی جیب سے قیمت ادا کرکے اسے حاصل کیا۔ ساتھ ہی نہ صرف دوسرے چرچوں کو تحفظ دیا بلکہ شہر کے دوسرے بڑے چرچ، ’کلیسائے حواریاں‘ کو یونانی اور آرتھوڈکس فرقے کا مرکزی چرچ بنانے کا موقع دیا، جو آج تک قائم ہے۔ آج اس وقت بھی ترکی میں ۴۳۵ چرچ پوری آن بان کے ساتھ موجود ہیں حالانکہ عیسائیوں کی تعداد آبادی میں صرف ۰ء۲ فی صد ہے۔
ہمیں یہ اعتراف ہے کہ مسلمانوں سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہردور میں مسلم دنیا میں غیرمسلموں کو جو تحفظ، عزت اور انصاف حاصل رہا اس کی کوئی مثال دوسری تہذیبوں میں نہیں ملتی۔ ایڈورڈگبن [م:۱۷۹۰ء]کی کتاب The History of the Decline and Fall of the Roman Empire، ٹی ڈبلیو آرنلڈ [م:۱۹۳۰ء]کی شہرئہ آفاق کتاب The Spread of Islam in the World اور جوزف آرنلڈ ٹائن بی [م:۱۹۷۵ء]کی تحریریں اس کا ثبوت ہیں۔(اسرائیلی مؤرخ اوڈ پیری اعتراف کرتا ہے: ’’مسلمانوں کی فتح کے چارسوسال بعد یروشلم کا مضافات عیسائی اور عیسائی مذہبی عمارتوں سے بھرپور تھا‘‘۔ پھر دی واشنگٹن پوسٹ (۲۵ جولائی ۲۰۲۰ء) برملا لکھتا ہے:مسلمان حکمرانوں نے نہ صرف یونانیوں کو مکمل تحفظ دیا بلکہ آرمینی عیسائیوں کو موقع فراہم کیا کہ وہ استنبول میں عیسائیت کے آثار کی تعمیرنو کرسکیں۔ اسی طرح جلد ہی ہسپانیہ کے یہودیوں کو خوش آمدید کہا، جنھیں کیتھولک عیسائیوں کے مظالم کا سامنا تھا۔)
۲۴جولائی ۲۰۲۰ء میں آیا صوفیہ سے دوبارہ مسجد کبیر بننے کے عمل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس امر کا پورا پورا ادراک کیا جائے کہ اصل ظلم تو مصطفےٰ کمال پاشا کے ہاتھوں ہوا تھا جس نے محض مغربی اقوام کو خوش کرنے اور اپنے زعم میں ترکی کو ماڈرن بنانے کے لیے جبر اور قوت کے ذریعے ترک قوم پر سیکولرزم کو مسلط کیا اور قوم کو اس کے اسلامی ماضی سے کاٹنے کی ظالمانہ، قبیح اور تباہ کن کوشش کی، لیکن اس فسطائیت کو ترک قوم نے کبھی قبول نہ کیا اور ہرموقع ملتے ہی، اس سے نجات کی کوشش کی، اور الحمدللہ کامیاب رہی۔
مصطفےٰ کمال ایک کامیاب فوجی کمانڈر تھا اور اس کی قیادت میں ترکی نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی، جس کے باعث اسے قوم نے بجا طور پر ہیرو کا مقام دیا، مگر اس کے ساتھ یہ افسوس ناک حقیقت بھی ہے کہ مصطفےٰ کمال نے اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے، نہ صرف عثمانیہ خلافت کا خاتمہ کیا بلکہ مغرب سے دوستی کے سراب کے تعاقب میں دین اسلام کے شعائر کو بھی پامال کیا۔ عربی زبان اور رسم الخط کو نہ صرف ختم کیا بلکہ عربی زبان میں اذان تک پر پابندی لگا دی۔ مسجدوں اور مدارس کو بند کردیا، دینی تعلیم کو ختم کردیا۔ عربی میں کتب کی اشاعت پر پابندی لگا دی، لباس کو تبدیل کیا اور جبراً قوم کو مغربی لباس پہننے پر مجبور کیا۔ عورتوں کے حجاب پر پابندی لگا دی۔ علما کو جیلوں میں ڈال دیا اور پھر آیاصوفیہ جو اسلام کا سمبل تھی، اسے پہلے بند رکھا۔اس کے قیمتی قالین کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا اور ایک مینار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ یہ سارا کام فوجی قوت کے ذریعے کیا گیا۔ پھر فوج ہی مصطفےٰ کمال کی قیادت میں اصل حکمران قوت بن گئی۔ نیز فوج کو بھی مکمل طور پر سیکولرزم کے رنگ میں رنگ دیااور سرکاری مداخلت کے ذریعے زندگی کے ہرشعبے سے اسلام اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو خارج کیا گیا۔
۱۹۳۰ء کے عشرے کے وسط میں اس زعم میں کہ ’’ترک عوام اپنی دینی شناخت میں کمزور ہوکر سیکولر فکروعمل میں ڈھل گئے ہوں گے‘‘ ایک انتخاب منعقد کیا گیا، لیکن اس کے نتیجے کو بھی تسلیم نہ کیا گیا، جس کی تفصیل خود مصطفےٰ کمال کے سوانح نگار ایچ سی آرم سٹرانگ نے Grey Wolf نامی کتاب [۱۹۳۷ء] میں دی ہے۔ اس طرح فوجی آمریت کا سلسلہ ۱۹۵۰ء تک جاری رہا۔ مصطفےٰ کمال کا انتقال ۱۹۳۸ء میں ہوا، لیکن اس کی پارٹی عصمت انونو [م: ۱۹۷۳ء]کی قیادت میں اسلام دشمنی اور سیکولرزم کی جبری ترویج پر عمل پیرا رہی۔البتہ پہلے ہی آزاد انتخاب میں عوام نے برسرِ اقتدار پارٹی کو شکست دی اور اس کے بعد آج تک وہ کبھی واضح اکثریت حاصل نہیں کرسکی۔ عوام نے اس پہلے انتخاب میں عدنان میندرس اور اس کی پارٹی کو قیادت سونپی، جس نے ۱۸سال کے بعداذان کو عربی زبان میں جاری کیا تو ترک عوام اذان کی اس آواز پر، جہاںوہ موجود تھے سجدے میں گر گئے۔ البتہ عدنان میندرس کو ان ’جرائم‘ کی یہ سزا ضرور ملی کہ ۱۹۶۰ء کے فوجی انقلاب کے بعد ان کو سزاے موت دی گئی اور اس طرح وہ ۱۷ستمبر۱۹۶۱ء کو شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ترک عوام بلاشبہہ آج بھی جنگ ِ آزادی میں مصطفےٰ کمال کے کردار پر نازاں ہیں، لیکن اس کے سیکولرزم کو آہستہ آہستہ ترک کر رہے ہیں اور خصوصیت سے نجم الدین اربکان [م:۲۰۱۱ء] اور طیب اردگان کی قیادت میں جو سیاسی اور نظریاتی تحریک برپا ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں آج الحمدللہ آیا صوفیہ دوبارہ مسجد بن گئی ہے۔ اس اقدام میں طیب اردگان اور ان کی پارٹی کا کردار مثالی اور قائدانہ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ترک قوم کی عظیم اکثریت کی ان کو تائید حاصل ہے۔
اکانومسٹ،لندن میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق ترک عوام کے ۷۳ فی صد نے اس اقدام کی تائید کی ہے۔ ترکی کی کم از کم دو سیکولر پارٹیوں نے کھل کر اس کی تائید کی ہے۔ اسی طرح عالم اسلام میں عوامی سطح پر عظیم اکثریت اس تبدیلی کا خیرمقدم کررہی ہے۔ خاموشی یا ملفوف ناپسندیدگی کا اظہار چند عرب ممالک کی قیادتوں کی طرف سے بھی ہے، لیکن اصل مخالفت کی آوازیں مغربی دنیا سے اُٹھ رہی ہیں، جو ترکی اور خصوصیت سے طیب اردگان کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ اسی طرح عیسائی قیادتیں اسے مسجد اورچرچ کا تنازعہ بنا کر پیش کر رہی ہیں، جس میں کوئی صداقت نہیں۔ کچھ مسلمان لبرل دانش وَر بھی اپنے اضطراب کا اظہار کر رہے ہیں، اور دور از کار خدشات اور خودساختہ ’اخلاقی مصالح‘ پر قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ روس، یونان اور امریکا کی سیاسی قیادت اور یونیسکو نے بھی تنقید کے تیر چلائے ہیں۔
اگر انصاف سے دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ ان اعتراضات میں کوئی جان نہیں۔ آیا صوفیہ کا بطور مسجد احیا قانونی، اخلاقی، سیاسی اور سماجی، ہراعتبار سے مبنی برحق ہے اور اس سلسلے میں خود ترکی کی عدالت کے فیصلے میں قانونی نکات کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے اور اس کی عالمی حیثیت اور زائرین کے لیے کھلا ہونا ایک مسلّمہ حقیقت ہے اور رہے گی۔ کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے جارہے اور کسی دوسرے مذہب یا تہذیب کے آثار کو مٹایا نہیں جارہا۔ نہ ایسا ماضی میں ہوا اور نہ آج ہوگا۔ آیا صوفیہ کے مذہبی نوادرات کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ نہیں ہوئے ہیں۔ عثمانی حکمرانوں نے توان کے نقش و نگار اور تصاویر تک کو بھی برباد نہیں کیا کہ جن کا ایک مسجد میں وجود درست نہیں۔ صرف ان پر پلاسٹر لگا کر نظر سے اوجھل کر دیا ہے۔ آیا صوفیہ کی اگر کسی نے بے حُرمتی کی ہے، تو وہ خود عیسائی دور کے مقتدرافراد تھے۔
بی بی سی کے ایک مقالہ نگار نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا:
صدیوں تک رومن کیتھولک دنیا اور بازنطینی سلطنت کےدرمیان مذہب کی بنیاد پر تنازع رہا ہے۔ ۱۲۰۴ء میں جب یورپی حملہ آوروں نے شہر پر دھاوا بول دیا تو مسیحیت کے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو تاراج کر دیا۔ انتہائی اہم تاریخی نوادرات اس جنگ کی وجہ سے ضائع ہوگئے، جن میں [مبینہ طور پر] حضرت عیسٰیؑ کے روضے کا پتھر، وہ نیزا جو حضرت عیسٰی ؑ کے جسم میں پیوست ہوا تھا، حضرت عیسٰیؑ کا کفن، جو اصلی صلیب تھی اس کے کچھ ٹکڑے، سینٹ تھامس کی مشتبہ انگلی، اور ہڈیاں شامل تھیں۔ آیا صوفیہ ایک کیتھولک چرچ توبہت کم عرصے کے لیے رہا، لیکن حملہ آوروں کی کارروائیوں کے نتائج دُور رس اور گہرے تھے، جو مشرق میں مسیحیت کی تباہی کے براہِ راست ذمہ دار ہیں۔ (بی بی سی اُردو، آیا صوفیہ، ۱۳جولائی ۲۰۲۰ء)
صدر طیب اردگان ، عدالت کے فیصلے اور ترکی کے اسلامی اُمور کے شعبے کے ڈائرکٹر نے صاف الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ تاریخی آثار کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان کو محفوظ رکھا جائے گا اور آیاصوفیہ ترکی کی دوسری مساجد کی طرح دنیا کے تمام انسانوں اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے کھلی رہے گی۔
یونیسکو اور دوسرے اداروں نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے، وہ زیادہ تر خود ان کے اپنے دہرے معیار کے ترجمان ہیں۔ عثمانی حکمرانوں کا تاریخی کردار رواداری اور بقاے باہمی (co-existance) کا رہا ہے اور ان شاء اللہ رہے گا۔
البتہ جو ادارے اور مغربی حکمران سوالیہ نشان اُٹھا رہے ہیں، ان کے اپنے کردار پر اگر نظر ڈالی جائے تو بڑی تکلیف دہ اور ناخوش گوار صورتِ حال نظر آتی ہے۔ ان تمام ممالک میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک برتا جارہا ہے، اس کا نہ کوئی حساب دے رہا ہے اور نہ کوئی اس کا مداوا کر رہا ہے۔ مساجد پر حملے اور مساجد کے قیام میں دشواریاں بے حدوحساب ہیں۔
حد یہ ہے کہ ریاست ہاے متحدہ امریکا کی ۲۸ ریاستیں ایسی ہیں، جن میں صوبائی سطح پر یہ متعصبانہ قانون سازی کی گئی ہے کہ مسلمان اپنے معاملات میں بھی شریعت اسلامی کے مطابق معاملات طے نہیں کرسکتے۔ فرانس، ہالینڈ اور کئی یورپی ممالک میں مسلمان خواتین کے لیے نقاب کا استعمال، حتیٰ کہ کچھ مقامات پر حجاب کا استعمال بھی قانونی طور پرممنوع ہے۔ جب کہ آزادی راے کے ان دعوے داروں کا حال یہ ہے کہ پوری مغربی دنیا میں تاریخی حقائق کی بنیاد پر بھی جرمنی میں یہودیوں کے ’قتل عام‘ (ہولوکاسٹ) کا انکار، حتیٰ کہ اس میں مارے جانے والوں کی تعداد کو چیلنج کرنا بھی قانونی جرم قرار دیتی ہے اور کئی سال کی حراست کا مستحق بنا دیتی ہے۔ آج پوری مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا کے تاریک سایے ہرطرف پھیلے نظرآرہے ہیں۔
دوسری طرف صورتِ حال یہ ہے کہ بظاہر مغربی دنیا سب کی آزادی اور حقوقِ انسانی کی خلاف ورزی کے خلاف جنگ کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس کا معاملہ بڑا ہی مختلف ہے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہورہا ہے، خواہ و ہ فلسطین ہو یا کشمیر، میانمار ہو یا سنکیانگ، بوسنیا ہو یا کوسوو، سربیا ہو یا چیچنیا۔ اسی طرح فرانس ہو یا اسرائیل، بھارت ہو یا سری لنکا، ان کی زبانیں بند رہتی ہیں۔ دوغلاپن اور ریاکاری (hypocrisy) ان کا شعار ہے۔ اتنے داغ دار دامن کے ساتھ محض ان خیالی اندیشوں پر واویلا کہ آیاصوفیہ کے مسجد بننے سے ترکی میں عیسائیوں پر آسمان ٹوٹ پڑے گا، صریح دھوکا نہیں تو کیا ہے:
اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت
دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ
ملّتِ اسلامیہ کے احیا کی طرف پیش رفت
مسئلے کاایک اور پہلو جس کی طرف ہم متوجہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ترک عوام نے کبھی دولت ِ عثمانیہ کے اپنے تابناک ماضی سے تعلق کو منقطع نہیں کیا۔مصطفےٰ کمال اور مغرب کے پرستار عناصر کی ہرزیادتی پر وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور دین اسلام، اسلامی روایات اور اسلامی شعائر کے تحفظ میں انھوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تحریک ِ خلافت کی شکل میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے جس طرح دولت عثمانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ اس کا نفش ان کے دل و دماغ پر آج بھی قائم ہے۔ جو مالی اعانت برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے کی تھی اس کے لیے ممنونیت وہ آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ خلافت کے خاتمے کے بعد اس رقم سے انھوں نے ایک بنک قائم کیا جو آج تک کام کر رہا ہے۔ پاکستانی عوام کا دل سے احترام اگر کسی ملک میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے تو وہ ترکی ہے۔ مجھے خود یہ تجربہ باربار ہوا ہے کہ ہوٹل تک یہ جاننے کے بعد کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہوٹل والوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور ’مہمان مہمان‘ کہہ کر ہمارا شکریہ ادا کیا۔ آیا صوفیہ کو مسجد بنانا ان کے دل کی آرزو تھی، اور جس کا اظہار ہرسطح پر کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ضیا گوک الپ [م:۱۹۲۴ء] جو مصطفےٰ کمال کا پسندیدہ شاعر اور اس کا موید تھا آیا صوفیہ کے باب میں اپنے اضطراب کا اظہار کرتا رہا۔ اسی کے اشعار پڑھنے پر طیب اردگان کو ۱۹۹۷ء میں گرفتار کیا گیا تھا:
The Mosques are our barracks,
The Domes are our helmets,
The Minarets are our bayonets,
And the faithful are our soldiers
مسجدیں ہماری بیرکیں ہیں اور گنبد ہمارے زرئہ سَر ہیں۔
مینار ہمارے نیزے ہیں اور صاحب ِ ایمان ہمارے سپاہی ہیں۔
آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت سے بحالی مسلمانوں کی آرزو، دُعا اور کوشش تھی۔ اس کا عجائب گھر ہونا ان کے دل پر زخم کی حیثیت رکھتا تھا، جس کا اظہار ہرسطح پر کیا جاتا تھا۔بڑےواشگاف الفاظ میں مسجد کی بحالی کے موقعے پر جمعہ کے خطبے میں امام نے ا ن الفاظ میں کیا کہ ’’آج ہمارا برسوں کا دُکھ ختم ہوا، جو ہماری تذلیل ہوئی تھی اس کا خاتمہ ہوا اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا‘‘۔ صرف طیب اردوگان ہی نہیں، ترک شعرا اور دانش وَروں نے بھی اس پورے عرصے میں اپنے دُکھ اور مسجد کی بحالی کے عزم کا اعادہ کیا اور اس کا سب سے مؤثر اظہار ایک چوٹی کے شاعر نجپ فاضل کیساکورک نے ۲۹ستمبر ۱۹۶۵ء آیاصوفیہ ہی میں ایک کانفرنس کے دوران کیا کہ سیکولرقیادت نے آیا صوفیہ کو عجائب گھر بناکر ترکی کی خودمختاری کو بدترین حد تک مجروح کیا ہے اور اپنی روح کو مغرب کی جدت پسندی کے قدموں پر ڈال دیا تھا۔ یہ ترکی قوم کی تذلیل کی انتہا تھی:
لادینی جمہوریہ نے ترکی کی خودمختاری کوبُری طرح مجروح کیاہے: جس نے اس کی روح کو مغربی جدیدیت پسندی کی خاطر فروخت کردیاہے۔آیا صوفیہ کی حیثیت کی تبدیلی اس تذلیل کی علامت ہے۔(دی نیو یارک ٹائمز، ۱۴جولائی ۲۰۲۰ء)
اس نے طنزاً کہا تھا کہ مسجد کو عجائب گھر بنانا ترکوں کی روح کو میوزیم میں نظربند کرنا تھا:
آیا صوفیہ کی عمارت کو عجائب گھر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ، ترکوں کی حقیقی روح کو ایک عجائب گھر میں قید کر دینے کے مترادف تھا۔(ایضاً)
اس نے مزید کہا کہ:
مغربی دنیا نے ہمارے اندر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جو کچھ ظلم کیا ہے،وہ نہ صلیبی حملہ آور اور روسی کمیونسٹ کرسکے، نہ کیتھولک عیسائی اور یونانی حملہ آوروں نے وہ ظلم کیا۔(ایضاً)
اسی نے ۱۹۶۵ء میں آیا صوفیہ میں کھڑے ہوکر یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ ایک دن یہ پھر مسجد بنے گی اور ہماری قیدی روح آزاد ہوگی۔
طیب اردگان نے تاریخی عمل کے مکمل ادراک کے ساتھ اس کا افتتاح ۲۴جولائی ۲۰۲۰ء کو کیا، جو ’لوزان معاہدے‘ کی ۹۷ویں سالگرہ تھی۔ یہ ہے ترک قوم کا جواب اور ملت اسلامیہ کے احیا کا ایک منظر! مغربی اقوام ،اداروں اور عیسائی دنیا کی قیادت کے اضطراب کو اس پس منظر میں سمجھا جاسکتا ہے۔
ترکی میں ہی نہیں، پوری دنیا میں اسلام اور مغرب کے سامراجی نظام کے درمیان کش مکش ہے۔ مغربی دنیا میں جس طرح اسلام کو ہدف بنایا جارہا ہے اور اسے ایک خطرہ بلکہ اصل خطرے کے طور پر پیش کیا جارہا ہے۔ یہ کسی کے حق میں بھی نہیں۔ بلاشبہہ اسلام کا اپنا تہذیبی اور سیاسی نظام ہے اور مسلم اُمت فطری طور پر اس نظام کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ہم تہذیبوں کے تصادم کے فلسفے کو ایک شیطانی فلسفہ سمجھتے ہیں۔ تہذیبوں کے درمیان صحت مند مسابقت، تعاون اور مکالمہ ہی فطری راستہ ہے۔اختلاف، تنوع کا مظہر ہے، تصادم کا پیش خیمہ نہیں۔ ترکی کا موجودہ اقدام ماضی کی ایک عظیم تاریخی غلطی اور جبری اقدام کی اصلاح ہے، کسی کے خلاف کوئی سازش اور جبری اقدام نہیں۔
ہم ان گزارشات کو صدرطیب اردگان کے ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں جو انھوں نے آیاصوفیہ کے مسجد کے طور پر آغازِ نو کے موقعے پر کہے:
ہم آیا صوفیہ کو اس کی اصل بنیادوں کے مطابق استوار کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کے ثقافتی ورثے کو مکمل طور پر محفوظ رکھیں گے۔ ہم نے آیا صوفیہ کو ایک نہایت غلط فیصلے کے تحت ایک عجائب گھر بنایا اور اب ہم اسے بجا طور پر دوبارہ مسجد بنا رہے ہیں، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آیا صوفیہ ایک چرچ سے مسجد نہیں بنائی جارہی بلکہ ایک عجائب گھر سے مسجد بنائی جارہی ہے۔ کسی کو فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے پورے ثقافتی ورثے کی حفاظت کریں گے۔
قیصر جسٹینین اوّل کے حکم پر ۵۳۲ء سے ۵۳۷ء کے دوران آیا صوفیہ کی تعمیر ہوئی۔ یہ عمارت، تب سے لے کر اب تک، بازنطینی طرز تعمیر کا ایک اعلیٰ شاہکار ہے، جسے فن تعمیرات کی تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اپنی اوّلین شکل میں اس عمارت کو یونانی آرتھوڈوکس کیتھڈرل کے طور پر بنایا گیا۔ بعد ازاں اپنی طویل تاریخ میں یہ پر شکوہ عمارت، عروج و زوال کی کئی داستانوں کی گواہ بنی۔ آئیے کچھ پہلوؤں پر ہم غور کرتے چلیں:
یہ بات قابل ذکر ہے کہ موجودہ عیسائی دنیا مبہم و متضاد تعلیمات پر مبنی کئی فرقوں میں تقسیم ہے۔ خاص طور پر یونانی آرتھوڈوکس اور رومن کیتھولک عیسائیوں کے درمیان نہایت بنیادی اختلافات کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اوّل الذکر پوپ کی معصومیت کا قائل نہیں اور مؤخر الذکر گنہگار تسلیم نہیں کرتا۔ ایک کے نزدیک پادریوں کی شادی ہوچکی ہو تو جائز ہے، دوسرے کے ہاں کسی حال میں جائز نہیں۔ دونوں کے درمیان عالم برزخ کے وجود و عدم وجود اور محطات الصليب (stations of the cross) کے عقیدے کے اقرار و انکار پر عداوتیں چلی آرہی ہیں۔ اوّل الذکر کے نزدیک مذہب کی اساسی تعلیمات و عقائد میں کسی تبدیلی کی گنجایش نہیں، تو مؤخر الذکر عقائد میں ارتقا کے قائل ہیں۔ یہ ایسے بنیادی اختلافات ہیں، جن سے یہ دو مسلک نہیں بلکہ دو مختلف دین نظر آتے ہیں۔ صرف باہر سے نہیں بلکہ ان کا باہمی رویہ بھی تاریخی طور پر ایسا نہیں رہا ہے، جس سے ان کے باہمی اختلافات پر محض فرقہ وارانہ اور مسلکی ہونے کی تہمت لگائی جاسکے۔
ان کے اختلافات نے وقتاً فوقتاً کبر و نخوت اور تفسیق و تکفیر کی ہی نہیں بلکہ سیاسی محاذ آرائی اور جنگ و جدال کی شکل اختیار کی ہے۔ چنانچہ صلیبی جنگوں کے دوران ۱۲۰۴ء میں کیتھولک صلیبیوں نے آرتھوڈوکس بازنطینیوں پر حملہ کر دیا اور قسطنطنیہ پر قبضہ جمالیا۔ یہ ایک ہی مذہب کو ماننے والوں کے درمیان کا ایک اتفاقی سیاسی جھگڑا نہ تھا، ورنہ اتنی رواداری تو برتی جاسکتی تھی کہ آیا صوفیہ کے مذہبی تشخص کو بحال رکھا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے برعکس چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب صلیبی، قسطنطنیہ کےآرتھوڈوکس شہریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، ان کے اموال و املاک پر قابض ہورہے تھے، یہاں تک کہ انھوں نے آیا صوفیہ کی سابقہ حیثیت کو ختم کرکے اسے رومن کیتھولک کیتھڈرل بنا ڈالا۔ پھر جب بازنطینی سلطنت کو ۱۲۶۱ء میں دوبارہ اقتدار حاصل ہوا، تو اس وقت آیا صوفیہ کی شناخت میں پھر انقلاب آیا اور وہ آرتھوڈوکس کیتھڈرل کی حیثیت میں لوٹ گیا۔ آرتھوڈوکس اور کیتھولک عیسائیوں کے درمیان یہ عداوت و مخاصمت ایسی شدید تھی کہ آرتھوڈوکس عیسائی، مسلمانوں کو کیتھولک عیسائیوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ یہ کوئی ڈھکا چھپا اقرار نہ تھا بلکہ ان کے بڑے بڑے مذہبی رہنما باقاعدہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے اور ان کے قول تاریخ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ قسطنطنیہ پر ۱۲۰۴ء کی صلیبی فتح اور ۱۴۵۳ء کی عثمانی فتح کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ آرتھوڈوکس عیسائیوں کی کیتھولک صلیبیوں سے بدظنی محض مسلکی تعصب پر ہی نہیں بلکہ عقلی و تجرباتی بنیادوں پر بھی قائم تھی۔
آج ترکی کی آبادی تقریباً ۸کروڑ ۲۰لاکھ ہے۔ اس میں صرف ۰ء۲ فی صد عیسائی ہیں۔ یہ تعداد زیادہ سے زیادہ دو سے تین لاکھ بنتی ہے۔ ان میں کم و بیش۸۰ ہزار اورینٹل آرتھوڈوکس، ۳۵ہزار کیتھولک، ۱۸ ہزار انطاکی، ۵ہزار یونانی آرتھوڈوکس، اور ۸ہزار پروٹسٹنٹ شامل ہیں۔
باقی سوالوں کو فی الحال نہ چھیڑتے ہوئے اگر یہ فرض بھی کرلیں کہ مفروضہ انصاف کا تقاضا مسجد آیا صوفیہ کو چرچ بنادینا ہی ہے، تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے؟
کیا اسے یونانی آرتھوڈوکس عیسائیوں کے سپرد کیا جائے کہ یہ انھی کے فرقے کا کیتھڈرل رہا ہے؟ مگر ان کی تعداد تو بڑی کم ہے، تاریخ کے اس طویل سفر کے بعد اس اقلیت کو ترکی کی موجودہ عیسائی اقلیت کا نمایندہ نہیں سمجھا جاسکتا۔
کیا اسے اورینٹل آرتھوڈوکس کو دیا جائے کہ ان کی تعداد ترکی میں زیادہ ہے؟ مگر اورینٹل آرتھوڈوکس دنیا بھر کے عیسائیوں کی نمایندگی نہیں کرسکتے۔
کیا اسے رومن کیتھولک فرقے کو دیا جائے کہ ان کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے؟ مگر انصاف کی آڑ میں یہ تو شدید ترین ظلم ہوگا کہ یہ تاریخی عمارت انھیں بھینٹ میں دے دی جائے، جو نہ صرف اس معبد بلکہ اس شہر اور اپنے ہم مذہب شہریوں کی اینٹ سے اینٹ بجا چکے۔
کیا پھر یہ پروٹسٹنٹس کو دے دی جائے کہ وہ نسبتاً نئے اور تاریخی طور پر کم متنازع ہیں؟
یا اسے ورلڈ کونسل آف چرچز یا اسی طرح کے کسی ادارے کے حوالے کردیا جائے؟
یہ سوالات بڑے ٹیڑھے اور ناہموارہیں۔
اس پورے قضیے میں ایک قابلِ ذکر سوال یہ ہے کہ کیا کسی عیسائی فرقے نے آیا صوفیہ کے لیے اپنا دعویٰ بھی پیش کیا ہے، یا قانونی جنگ لڑی ہے؟ دلائل و شواہد مہیا کرائے ہیں؟ ۱۴۵۳ء سے نہ سہی، ۱۹۳۱ء اور ۱۹۳۵ء سے کوئی جدوجہد کی ہے؟ تحریک چلائی ہے؟ غلط ہی سہی کم از کم دعویٰ تو کرتے۔ چلیے سلطان محمد فاتح کو ظالم قرار دے کر، عیسائی ان سے ڈر گئے۔ اسی طرح اردوغان سے بھی ترکی کے عیسائی ڈر گئے۔ لیکن پوپ سمیت دنیا بھر کے عیسائی کس سے اور کیوں ڈرے رہے؟
الٹرا لبرل و سیکولر عینکیں اتار کر دیکھیں تو بات صاف سمجھ میں آجائے گی۔ آیا صوفیہ کی عجائب گھر والی حیثیت قانونی طور پر ناجائز ٹھیری ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کی مسجد والی حیثیت قانونی و تاریخی حیثیت سے اتنی مسلّم ہے کہ کوئی قابل ذکر عیسائی فرد بھی اسے چرچ نہیں کہہ رہا ہے۔ ورلڈ کونسل آف چرچز کے عبوری سیکریٹری جنرل آیان ساکا نے اردوغان کو لکھے اپنے خط میں آیا صوفیہ کو عجائب گھر سے مسجد بنانے کے فیصلے پر’افسوس‘کا اظہار کیا ہے۔ اس کونسل کو عالمی سطح پر ۳۵۰سے زائد پروٹسٹنٹ، آرتھوڈوکس، انجلائی چرچوں کی سرپرستی کا اعزاز حاصل ہے۔ لیکن اس کونسل کے جنرل سیکریٹری نے رسمی لفظوں میں بھی نہیں کہا کہ ’’اصل انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ آیا صوفیہ کو چرچ بنادیا جائے‘‘۔ پوپ فرانسس نے بھی اس اقدام پر’درد‘تو محسوس کیا، لیکن وہ بھی ایسی دیدہ دلیری کا مظاہرہ نہ کرسکے کہ اس مرکز توحید کو چرچ بنانے کی بات کہتے۔ ان راہبوں کی خداپرستی کی شان نرالی ہے۔ خداے بزرگ و برتر کی عبادت گاہ تماشا گاہ اور عجائب خانہ بن کر اُجڑی رہے یہ انھیں منظور ہے، مگر وہ خدا کے بندوں کے سجدوں سے معمور ہو، یہ منظور نہیں۔ ہمارے کچھ بھائیوں کا حال اس سے بھی برا ہے۔ تثلیث کے حامی تو مسجد کو عجائب گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن ان موحدین کا کیا کیا جائے جو مسجد کی بازیافت پر بارگاہ الٰہی میں ہدیۂ تشکر پیش کرنے کے بجائے فیس بک پر اس بات کا غم منا رہے ہیں کہ مسجد، مسجد کیوں بن گئی، چرچ کیوں نہ بنی؟
حقیقت یہ ہے کہ آیا صوفیہ کو چرچ بنانے کی بحث انصاف سے زیادہ فتنے کا وہ دروازہ ہے، جس کے اوروں کی عیاری سے ٹوٹنے کا اتنا امکان نہیں، جتنا سادگی سے متنازع بنائے جانے کا ہے۔
آج جہاں مسجد آیا صوفیہ قائم ہے اس زمین پر انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق پہلے پہل قسطنطین اوّل نے ایک پرانے غیر عیسائی (pagan) معبد کی بنیادوں پر ۳۲۵ء میں ایک چرچ تعمیر کرایا۔ ملک کے داخلہ ہنگاموں کے دوران ۴۰۴ء کو لکڑی سے بنے اس سیدھے سادے کلیسا میں آگ لگ گئی۔ کونسٹانس اوّل نے اس کی تعمیر نو کرائی۔ لکڑی سے بنی یہ عمارت ایک بار پھر داخلی خلفشار کے دوران ۵۳۲ء میں نذر آتش ہوگئی۔ جس کے بعد جسٹینین اوّل نے دو ماہر معماروں کو تعمیر کا کام سونپا۔ ۵۳۷ء میں یہ کام پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ مختصراً یہ کہ ۳۲۵ء سے قبل اس جگہ کی حیثیت ایک غیر عیسائی معبد، مابعد۳۲۵ء اس کی حیثیت ایک چرچ، بعد ازاں خصوصاً ۵۳۷ء کے بعد اس کی حیثیت بازنطینی کیتھڈرل کی ہوگئی۔ عیسائیوں کے باہمی اختلافات اس دوران شدت اختیار کرتے رہے، جس کے اثرات آیا صوفیہ پر بھی پڑے۔ خصوصاً آٹھویں صدی عیسوی میں عمارت سے بتوں، تصویروں اور کچھ دیگر شعائر کو ہٹانے کے لیے ایک مہم چلی۔ اس متنازعہ دور کو Iconoclastic Period بھی کہتے ہیں۔ ۱۰۵۴ء میں یہ قضیہ اپنے انجام کو پہنچا اور کیتھڈرل پر یونانی آرتھوڈوکس فرقے کے عیسائیوں کا تسلط قائم ہوگیا۔ مسیحی تاریخ میں اس اہم وقوعے کو The Great Schism کہا جاتا ہے۔
۱۲۰۴ء میں قسطنطنیہ پر صلیبیوں کے حملے کے نتیجے میں آیا صوفیہ کو رومن کیتھولک کیتھڈرل میں تبدیل کردیا گیا۔ ۱۲۶۱ء میں بازنطینیوں کے دوبارہ اقتدار میں آنے پر اس کی یونانی آرتھوڈوکس کیتھڈرل والی حیثیت بحال ہو گئی۔
۱۴۵۳ء میں سلطان محمد فاتح کی قیادت میں مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر فتح حاصل کی۔ قسطنطنیہ استنبول اور کیتھڈرل آیا صوفیہ، جامع کبیر آیا صوفیہ ہوگیا۔ کیتھڈرل کی مسجد میں یہ تبدیلی کیا شرعاً و قانوناً جائز ہے؟ اس سوال پر ذرا رُک کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اس ذرا رُکنے سے میری مراد تین اہم نکات کو ذہن میں تازہ کرلینے سے ہے:
پہلا نکتہ: خیال رہے کہ اپنے تمام تر عقل و شعور کے باوجود انسان ایک مادی و حسی وجود ہے اور اکثر و بیش تر خود کو زمان و مکان کی حدود و قیود سے آزاد نہیں کرپاتا۔ تاریخ کے مطالعے کی بدترین شکل یہ ہے کہ ہم اپنے دور میں رہ کر اپنے دور کے مسلمات کے مطابق ماضی کی ہر چیز کا جائزہ لینے لگیں اور بدقسمتی سے اکثر ایسا ہی کیا جاتا ہے، جو مطالعہ تاریخ کے باب میں انتہا درجے کی زیادتی ہے۔ ایسی تنقید آج کے کسی آٹھ سالہ پوتے کی اٹھاسی سالہ دادا پر کی گئی اس تنقید کے مترادف ہے کہ ’’اتنے بڑے ہوگئے ہیں مگر آپ کو موبائل چلانا کیوں نہیں آتا؟‘‘ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثال صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ٹکنالوجی کا معاملہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ذہن و تصورات کی دنیا میں بھی ارتقا ہوتا ہے۔ ٹکنالوجی میں ہونے والا ارتقا بھی فکر کی دنیا میں ہونے والے ارتقا کا بالواسطہ ثبوت ہے۔
دوسرا نکتہ: اسلام ایک عملی دین ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو بے جا مشقت میں مبتلا نہیں کرتا،اور نہ غیر عملی قسم کی (idealistic )تعلیمات دیتا ہے۔ اس کے اپنے آدرش (ideals) بہت اونچے ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، جن میں فیصلے دوسروں کے طرز عمل کو مدنظر رکھ کر لیے جاتے ہیں اور لیے جانے چاہییں۔ یہ عملیت اسلام کا حسن ہے۔ مثال کے طور پر جنگ کے دوران بھی پیڑ پودے کاٹنے کی ممانعت ہے، — لیکن — جنگی ضرورت کے تحت ایسا کیا جاسکتا ہے؛ جنگ میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں، اور راہبوں کو مارنے کی ممانعت ہے، — لیکن اگر وہ خود حملہ آور ہوجائیں تو ان پر بھی تلوار اٹھائی جائے گی؛ حرام مہینوں میں قتال منع ہے، — لیکن — اگر دشمن اس حرمت کا پاس نہ رکھے تو قتال کیا جائے گا؛ حدود حرم میں قتال منع ہے، — لیکن — دشمن اگر آمادہ جنگ ہو تو حرم میں بھی قتال ہوگا۔ یہ صرف چند کا ذکر تھا ورنہ بین الاقوامی تعلقات پر منطبق ہونے والی قرآن و سنت کی بہت سی تعلیمات ہیں، جہاں اپنے طرزِ عمل کے لیے سامنے والے کے طرز عمل کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے۔
ذرا آگے بڑھ کر ہمارے بہت سے فقہا اور مفکرین نے کہا ہے کہ جزیہ، ذمی، جنگی قیدیوں، لونڈی اور غلام وغیرہ کے سلسلے میں فقہ اسلامی کے بہت سے احکام (خصوصاً وہ جو اگلے وقتوں میں ذرا regressive معلوم ہوں) وقت کے قوانین کی روشنی میں طے پاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اسلام کا مطمح نظر تاجروں کی حوصلہ افزائی اور تجارت کا فروغ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ’آزادانہ تجارت‘ (FreeTrade) کا تصور اسلامی تعلیمات سے زیادہ میل کھاتا ہے، لیکن حضرت عمرؓ نے دیگر ممالک میں مسلم تاجروں پر محصول لگائے جانے کے جواب میں، بلاد اسلامیہ میں آنے والے غیر مسلم تجار پر بھی محصول عائد کیا۔ یہ اللّٰہ کے دین کا حسن ہے اور بالغ نظری ہے ہمارے فقہا کی، جنھیں اللّٰہ نے دین کی سمجھ عطا کی کہ ہمارے دین میں مثالیت پسندی اور حقیقت پسندی کا ایک حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔
تیسرا نکتہ: ہمارے فقہ کی کتابوں میں دو قسم کی فتوحات کا تذکرہ ہے۔ بذریعہ صلح اور بزورِ قوت۔ صلح کی صورت میں ظاہر ہے کہ مقبوضہ آبادی، ان کے اموال و جایداد، اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ اور بزور قوت فتح پانے کی صورت میں یہ وقت کے اولوالامر کی صوابدید پر ہوگا کہ وقت اور حالات کے تناظر میں چاہے تو سختی کا رویہ اختیار کرے اور چاہے نرمی اور احسان کا۔ اسلامی تاریخ میں کم ہی ایسا ہوا جب سختی کے رویے کو اختیار کیا گیا۔ عام طور پر عفو و درگزر اور نرمی و احسان کی مثالیں ہی ملتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سختی ناجائز اور غیر قانونی ہے۔ یوں ایک قانونی مسئلے میں منتخب اور یک طرفہ مثالیں جذباتی انداز میں پیش کرکے مسجد آیا صوفیہ کی بازیافت پر سوالات اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ یاد رہے سیرت میں فتح مکہ ہی نہیں طائف، حنین، بنونضیر اور بنوقریظہ بھی آتے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے امام ابویوسف کی کتاب الخراج ہے، جس میں تفصیل سے فتح کی دونوں قسموں پر بحث کی ہے اور مثالیں پیش کی گئی ہیں۔
ان بنیادی نکات کی وضاحت اس لیے ضروری ہے، تاکہ بے جا مثالیت پسندی کے بجائے ہم اپنے ماضی اور اسلاف کے ساتھ انصاف کرسکیں اور حال میں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔
اب آئیے ۱۴۵۳ء کے قسطنطنیہ چلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب عثمانی فوجیں شہر میں داخل ہوئیں تو قتل عام ہوا۔ اس سلسلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ اس ’قتل عام‘ سے کیا مراد ہے؟ دراصل دشمن کے شہر کو جب بزور قوت فتح کیا جاتا تھا، تو ان کا زور توڑ دینے کے لیے شہر میں قتال کیا جاتا تھا۔ جس دشمن نے آخر تک مزاحمت کی ہو، اس کی طرف سے شہر میں گھستے ہی غافل ہو جانا یقیناً دانش مندی نہ تھی۔ یہ سوچنا سادہ لوحی ہوگی کہ فوجوں کی مزاحمت صرف شہر کے صدر دروازے پر ہوگی، حالانکہ ہاری ہوئی فوج کے بے ترتیب حصے اور جوشیلے نوجوان ہر گلی کوچے میں مزاحمت کرتے تھے۔ ایسے میں ایک بے ضرر شہری اور دشمن فوج کے سپاہی میں امتیاز مشکل تھا۔ چنانچہ مسلم افواج کی کوشش یہ ہوتی تھی بلکہ باقاعدہ اعلان کرتے تھے کہ ’’لوگ گھروں میں دروازہ بند کرلیں وگرنہ انھیں دشمن کا سپاہی سمجھا جائے گا‘‘۔ اسے آپ چاہیں تو موجودہ دور میں فسادات کے دوران کرفیو اور شوٹ ایٹ سائٹ سے یک گونہ تشبیہ دے کر بات سمجھنے کی کوشش کرسکتے ہیں۔
یہی وجہ تھی کہ خود حضرت محمدصلی اللہ علیہ وسلم نے عین فتح مکہ کے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ جو ابوسفیان کے گھر، حکیم بن حزام کے گھر، کعبے میں، یا اپنے گھر کا دروازہ بند کرکے رہے اسے امان ہے۔ بھلا بتائیے سڑک پر چلنے والے ایک عام شہری کو امان کیوں حاصل نہیں تھی؟ کیونکہ اس وقت تک اسلامی افواج نے شہر پر مکمل تسلط حاصل کرکے، نظم و نسق اپنے ہاتھوں میں لے کر امن و امان قائم نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی شہر کا کنٹرول ہاتھ آیا لوگوں کو مکمل امن عطا ہوا۔ قسطنطنیہ میں جس ’قتل عام‘ کا ذکر ہوتا ہے، اگر اس کی نوعیت یہ تھی تو پھر یہ ناگزیر تھا۔ اگر اس کے علاوہ کچھ تھی تو اسے بے احتیاطی کہیے یا جواں سال سلطان کے نظم کی کمزوری —، یقیناً اس کا جواز نہیں پیش کیا جائے گا، لیکن ایسی بے احتیاطی کی وجہ سے پوری فتح کو متہم نہیں کیا جائے گا۔
میری اپنی راے میں قتال کی نوعیت وہ تھی جس کا ذکر دشمن کا زور توڑنے اور شہر پر تسلط حاصل کرنے کے ضمن میں کیا گیا۔ چنانچہ عزیر احمد لکھتے ہیں کہ شہر میں داخلے کے بعد عثمانی فوج نے’’فتح کے ابتدائی جوش میں قتل عام شروع کردیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ جوش کسی قدر ٹھنڈا ہوا اور نیز یہ دیکھ کر کہ شہر والوں کی طرف سے مزاحمت نہیں ہوئی، انھوں نے اپنی تلواریں نیام میں کرلیں‘‘(دولت عثمانیہ، جلد اول)۔ یعنی جب مزاحمت نہیں ہوئی (یا ہونی بند ہوگئی) تو عثمانی تلواریں بھی نیام میں چلی گئیں۔ عزیر احمد ایورسلے کو نقل کرتے ہیں جو ۱۲۰۴ء کے بھیانک صلیبی مظالم کا تذکرہ کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح کی افواج کے بارے میں لکھتا ہے کہ شہر میں’’داخلے کے ابتدائی چند گھنٹوں کے بعد اس موقع پر کوئی قتل عام نہیں ہوا، آتش زنی بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ سلطان نے گرجاؤں اور دوسری عمارتوں کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہا‘‘۔
اس کے بعد کیا ہوا؟ مورخ اکبر شاہ نجیب آبادی لکھتے ہیں،’’قسطنطنیہ کے باشندوں کو سلطان فاتح نے امن و امان عطا کیا، جو لوگ اپنے مکانوں اور جایدادوں پر قابض رہےاور بخوشی اطاعت قبول کی ان کو اور ان کے اموال کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ عیسائیوں کے معبدوں اور گرجوں کو (بجز آیا صوفیہ کے) علیٰ حالہ قائم اور عیسائیوں کے تصرف میں رکھا۔ قسطنطنیہ کے بشپ اعظم کو سلطان نے بلا کر خوش خبری سنائی کہ آپ بدستور یونانی چرچ کے پیشوا رہیں گے۔ آپ کے مذہبی اختیارات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ سلطان محمد خاں فاتح نے خود یونانی چرچ کی سرپرستی قبول کی اور بشپ اعظم اور پادریوں کو وہ اختیارات حاصل ہوگئے، جو عیسائی سلطنت میں بھی ان کو حاصل نہ تھے۔ عیسائیوں کو کامل مذہبی آزادی عطا کی گئی۔ گرجوں کے مصارف اور چرچ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی جاگیریں عطا کیں۔ جنگی اسیروں کو، جو فتح مند فوج نے گرفتار کیے تھے سلطان فاتح نے خود اپنے سپاہیوں سے خرید کر آزاد کیا اور ان کو شہر قسطنطنیہ کے ایک خاص محلہ میں آباد کیا۔‘‘(تاریخ اسلام، جلد سوم)
اختصار کے ساتھ کہیں تو سلطان محمد فاتح نے دشمن پر فتح پاکر ان کے ساتھ قانونی نہیں بلکہ احسان کا معاملہ فرمایا۔ لیکن بہرحال ایک آیا صوفیہ کے معاملے میں یہ روش اختیار نہیں کی۔ ویسے تو اس بات کا الگ جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ قانون کی رو سے جب انھیں پورے شہر پر تسلط کا اختیار تھا اور انھوں نے اس قانونی حق کو استعمال نہ کرتے ہوئے ہر معاملے میں، بجز ایک کے، احسان کی روش اختیار کی تو کون سا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اور آیا صوفیہ کے استثنا کی جو سمجھ،سمجھ میں آتی ہیں وہ درج ذیل ہیں:
آیا صوفیہ کوئی عام چرچ نہیں بلکہ ایک کیتھڈرل تھا۔ کیتھڈرل مرکزی چرچ کو کہتے ہیں اور دیگر چرچ اس مرکزی چرچ کے تابع ہوتے ہیں۔ ایم جے ہگنس اور ایف نکس بازنطینی چرچ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اسے سمجھنے کے لیے ایک مسیحی جہانی ریاست (Christian World State) کے تصور کو سمجھنا ہوگا کیونکہ سلطنت کی توسیع پسندانہ اور سامراجی پالیسیوں کے نفاذ میں چرچ ایک مرکزی آلہ کار تھا۔ بادشاہوں کی تاجپوشی آیا صوفیہ میں بطریق کے ہاتھوں ہوتی تھی۔ یہ چرچ (بطور ایک عبادت گاہ نہیں ایک ادارہ) کی طاقت ہی تھی کہ بسااوقات بادشاہ اور بطریق کے درمیان بھی قوت و اقتدار کی جنگ چھڑ جاتی تھی۔ مارک کارٹ رائٹ بتاتے ہیں کہ صرف بطریق نہیں بلکہ مقامی بشپ بھی سیاسی قوت و اقتدار کے مالک تھے۔ وہ بڑے بڑے قصبوں میں بادشاہ اور بطریق کے نمایندوں کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ ان کے پاس بے شمار دولت ہوا کرتی تھی۔ دولت و طاقت اور روحانی اثر و رسوخ کی بدولت انھوں نے ایک طرح سے متوازی اقتدار قائم کررکھا تھا۔ اور ڈاکٹر عمیر انس بھائی کے الفاظ میں:’’آیا صوفیہ کی حیثیت سبھی تاریخی روایات کے مطابق محض مذہبی عمارت کی نہ تھی بلکہ ایک سیاسی اور عسکری ہیڈکوارٹر کی بھی تھی، اس لیے اس کے ساتھ مذہبی عمارتوں والا سلوک کیا جانا ممکن نہیں تھا۔ مزید یہ کہ اس زمانے کی صلیبی جنگیں چرچ کے ذریعے ہی انجام دی جا رہی تھیں اور پوپ حضرات ہی جنگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، لہٰذا پوپ کی اور ان کے مراکز کی حیثیت ’’عام عبادت گاہوں، مدرسوں یا خانقاہوں جیسی نہ تھی‘‘۔
پھر کیتھڈرل سے بہت سے توہمات وابستہ تھیں۔ ایڈورڈ گبن جیسے مؤرخ نے ان توہمات کا مذاق اڑایا ہے کہ کس طرح چرچ میں موجود لوگ آخر تک ایک فرشتے کے انتظار میں تھے لیکن فرشتے کو نہ آنا تھا، وہ نہ آیا (The Decline and Fall of the Roman Empire، جلد۶)۔ اس سے بالواسطہ طور پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کیسی ہی جھوٹی بشارتوں کی بنیاد پر لیکن کیتھڈرل سے بالکل آخری وقت تک سلطان کی افواج کی مزاحمت ہوئی تھی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قانونی حق رکھنے کے باوجود سلطان نے اس جنگی رہنمائی کے مرکز کو نشانہ بنانے کا حق استعمال نہیں کیا۔
اس لیے ایمان داری سے دیکھا جائے تو آیا صوفیہ کی حیثیت دہلی کی جامع مسجد جیسی نہیں بلکہ لال قلعہ کی تھی۔ ایک نئی مفتوحہ سرزمین پر قوت و اقتدار کے ایسے اہم مرکز پر اگر ایک فاتح نے اپنے قبضے کو برقرار رکھا بلکہ مزید احسان کا رویہ اختیار کرکے اسے وقف کردیا، تو اس پر اعتراضات بلاجواز نظر آتے ہیں۔
۱۴۵۳ء سے لے کر ۱۹۳۱ء تک، جب اتاترک کی ایما پر مسجد پر تالے ڈال دیے گئے، مسجد آیا صوفیہ میں نمازیں ادا ہوتی رہیں۔ ۱۹۳۴ء میں سیکولر ترک کابینہ نے آیا صوفیہ کو مسجد سے ایک عجائب گھر میں تبدیل کردیا۔ یہ ایک عدالتی نہیں بلکہ آمرانہ فیصلہ تھا کیونکہ ترکی میں کابینہ کی حیثیت ایک اعلیٰ ترین انتظامی ادارے کی رہی ہے۔ اس غیر ضروری، غیر معقول، اور غیر قانونی فیصلے پر عشروں تک عمل ہوتا رہا۔ اس دوران مسجد کی بازیافت کی کوششیں لگاتار ہوتی رہیں۔ بالآخر جولائی ۲۰۲۰ء میں کونسل آف اسٹیٹ نے، جسے ترکی کی اعلیٰ ترین انتظامی عدالت کی حیثیت حاصل ہے، ۱۹۳۴ء کے فیصلے کو غیر قانونی ٹھیرایا اور یوں مسجد کے مسجد بننے کی راہیں ہموار ہوئیں۔ فیصلے کی قانونی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ صرف اس فیصلے کو پڑھ لیا جائے تو بہت سے اعتراضات آپ سے آپ ختم ہوجائیں۔ کچھ اہم نکات درج ذیل ہیں:
۱- آیا صوفیہ کو مسجد سے عجائب گھر بنانا سلطان محمد فاتح کی وصیت اور قانونِ وقف کی خلاف ورزی تھی۔
۲- سلطان کے ’وقف‘ کی حیثیت غیرمنقولہ (non-transferable) ہے۔
۳- ریاست ’وقف‘ جایدادوں کے امین (custodian) کی حیثیت رکھتی ہے، اسے اس نوعیت کے تصرفات کی اجازت نہیں ہے۔
ناواقفیت کے نتیجے میں ایک اعتراض یہ بھی کیا جارہا ہے کہ ’’آیا صوفیہ کو عجائب گھر سے مسجد بنانے کا فیصلہ یونیسکو کے Protection of World Cultural and Natural Heritage کنونشن کے خلاف ورزی ہے‘‘۔ اس بات پر عدالت نے پہلے ہی غور کر لیا تھا، چنانچہ فیصلے میں کہا گیا کہ:
۴- مسجد سلطان احمد کی طرح ایسی بہت سی heritage sites ہیں، جو بطور مسجد استعمال ہورہی ہیں۔ یونیسکو کے کنونشن میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کی وجہ سے آیا صوفیہ کا استعمال اسلامی قانون کے مطابق نہ کیا جاسکے۔
میں نے اس فیصلے پر (جس پر اعتراض کرنے والے تعصب کی تہمت بھی لگا سکتے ہیں) اکتفا نہیں کیا، بلکہ یونیسکو کے اس کنونشن کا حرف بہ حرف مطالعہ کیا اور عدالت کے اس تبصرے کو قرین انصاف پایا۔ حتیٰ کہ یونیسکو نے اپنے جس بیان میں اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اس میں بھی اس فیصلے کو کنونشن کے خلاف ورزی نہیں قرار دیا ہے۔ اس بیان میں صرف اتنا لکھا ہے کہ: ’اس فیصلے کے نتیجے میں اگر عمارت تک عام لوگوں کی رسائی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا عمارت کے ڈھانچے میں کوئی بنیادی تبدیلی کی جاتی ہے تو یہ کنونشن کے خلاف ورزی ہوگی‘۔ اب، جب کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ زائرین پر کوئی روک ٹوک نہ ہوگی اور یہ کہ کوئی ٹکٹ بھی نہیں لگے گا تو اس سے رسائی کے بڑھنے ہی کا امکان نظر آتا ہے گھٹنے کا نہیں!
خلاصۂ کلام یہ کہ آیا صوفیہ کی زمانہ ماقبل تاریخ کی عبادت گاہ سے لے کر، ایک چرچ اور مختلف عیسائی فرقوں کے کیتھڈرل، مسجد اور عجائب گھر تک مختلف حیثیتیں رہی ہیں۔ اور یہ کہ قانون کی کوئی بھی تعریف متعین کرلی جائے، اس کی مسجد والی حیثیت کو غیر قانونی نہیں ٹھیرایا جاسکتا۔
بحث سوچنے سمجھنے والے زندہ معاشرے کا ایک لازمی خاصہ ہے۔ صحت مند بحثیں ایک صحت مند معاشرے کی علامت ہیں اور بیمار بحثیں بیمار معاشرے کی۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کسی معاشرے کی ذہنی سطح، علمی مزاج، فکری پختگی، نظریاتی افق، تنقیدی سوچ، باہمی رواداری اور اخلاقی قوت کو جانچنا مقصود ہو تو اس بات کا مطالعہ کافی ہوگا کہ وہاں بحثوں کے موضوع کیا ہیں اور یہ بحثیں کیسے کی جاتی ہیں؟
بیمار بحث کی بات کریں تو اس کی دوسری سب سے بڑی علامت شخصیت اور ذاتیات پر اتر آنا ہے۔ یہ اتنی معقول اور واضح سی علامت ہے کہ، عمل ہو نہ ہو، اس کی طرف عام طور پر توجہ ہو ہی جاتی ہے۔ توجہ مریضانہ بحث کی پہلی بڑی علامت کی طرف نہیں جاتی اور وہ یہ ہے کہ نہ دعویٰ سمجھا جائے، نہ جواب دعویٰ سمجھا جائے اور بحث میں چھلانگ لگادی جائے۔ ایسے میں کئی مرتبہ بڑی مضحکہ خیز صورتِ حال سامنے آتی ہے۔ کس دلیل سے کس دعوے کی تصدیق ہورہی ہے، کس حد تک ہورہی ہے؟ یہ سمجھنا بھی کامیاب مباحثے کے لیے ناگزیر ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ فیس بک اور چائے خانوں پہ ہونے والی آدھی سے زیادہ بحثیں صرف ایک دوسرے کے دعوے اور اس کے حدود اربعہ کو سمجھ لینے سے ختم ہوجائیں گی۔
قضیہ آیا صوفیہ پر جو بحث چھڑی ہے، اس میں علمی و تحقیقی باتوں سے لے کر جذباتی اور مناظراتی مواعظ کی بھرمار رہی۔ صحیح اور غلط دعوے کیے گئے، اور دونوں طرف سے صحیح اور غلط دلیلوں کا تبادلہ ہوا۔
تاہم، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس صحیح دعوے کی تائید میں بے وجہ کمزو دلائل بھی پیش کیے گئے۔ ان میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ اللّٰہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے ۳۶۰بتوں کو توڑ کر اسے مسجد بنایا تھا۔ چونکہ کعبہ اول روز سے توحید کا عالمی مرکز بنایا گیا تھا اور سمت مخالف کا یہ دعویٰ نہ تھا کہ کسی مسجد کو اگر بت خانہ یا کلیسا بنالیا جائے تو بھی اسے دوبارہ مسجد بنانا غلط ہے۔ اس لیے یہ بات، جو کہ بجائے خود صحیح ہے، بطور دلیل یہاں بے محل ہے۔ دوسری جانب سے یروشلم کی فتح کے وقت جو بے مثال اسوۂ فاروقی سامنے آیا تھا، اسے پیش کیا گیا کہ انھوں نے کلیسا سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا یہاں تک کہ وہاں نماز بھی نہ پڑھی۔ یہ صحیح بات بھی یہاں بطور دلیل بے محل ہے کیونکہ اول تو یروشلم بذریعہ صلح فتح ہوا تھا۔جملہ معترضہ کے طور پر عرض ہے کہ احسان کے اس رویے کے لیے کوئی دور کی کوڑی لانے کی ضرورت نہیں۔ قسطنطنیہ ہی میں آیا صوفیہ کے علاوہ دیگر معابد کے ساتھ سلطان محمد فاتحؒ نے یہی رویہ اختیار کیا اور انھیں ان کے حال پر برقرار رکھا۔ بات ہورہی تھی کہ اسلامی تاریخ سے کوئی ایسی مثال پیش کی جاتی (اور لاتعداد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں) کہ بزورِ قوت فتح کے باوجود معابد کو ان کے حال پر باقی رکھا گیا تو بھی یہ مسجد آیا صوفیہ کے خلاف کوئی طاقت ور دلیل نہ ہوتی۔ ایسا اس لیے کیونکہ فریق اول کا یہ دعویٰ ہی نہ تھا کہ مفتوحہ علاقوں کی ساری عبادت گاہوں کو ضرور بالضرور ہی مسجد بنالینا چاہیے۔
ایک مومن ہر حال میں اعتدال و توازن کی راہ اختیار کرتا ہے۔ دوران بحث وہ غلطیاں کرسکتا ہے لیکن جان بوجھ کر کسی باطل دلیل کا سہارا نہیں لے سکتا۔ لیکن اللّٰہ معاف کرے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دورانِ بحث الزامی تقابل کی یہ عجیب و غریب منطق بھی پیش کی گئی کہ آیا صوفیہ پر ترک عدلیہ کے فیصلے کی حمایت کا مطلب بابری مسجد پر ہندستانی عدلیہ کے فیصلے کی حمایت ہے۔ کیا یہ بالکل وہی بات نہ ہوئی کہ اگر آپ ویجیٹیرین نہیں ہیں مرغی، بکری اور بھینس کا گوشت کھاتے ہیں تو کہا جائےخنزیر کا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ بات کوئی خنزیر کھانے والا ناواقف انسان کرے تو ایک بار اسے سمجھایا بھی جائے، لیکن حلال و حرام اور صحیح و غلط کے تصورات سے واقف شخص کرے تو سواے ماتم کے اور کیا کیا جاسکتا ہے؟ چنانچہ ایک آزاد ملک میں ایک عبادت گاہ میں شر انگیزی، پھر وہاں عبادت کے سلسلے کو حکومت کے زور پر روک دینا، پھر اکثریتی قوم کو اقلیت کے خلاف بھڑکا کر فتنہ و فساد کا بازار گرم کردینا، اور پھر حکومت و عدالت کی یقین دہانیوں کے باوجود اس عبادت گاہ کا ظالمانہ طور پر انہدام۔ بعد ازاں عدالت عظمیٰ کا اپنے فیصلے میں بار بار یہ کہنا کہ معاملے کو عقیدے کی نہیں ثبوتوں کی روشنی میں حل کیا جائے گا، یہ تسلیم کرنا کہ شہید کی جانے والی عبادت گاہ کسی دوسری عبادت گاہ کو توڑ کر نہیں بنی تھی، یہ بھی ماننا کہ عبادت گاہ میں عبادت رضاکارانہ طور پر ترک نہیں کی گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عبادت گاہ کی بے حرمتی اور اس کا انہدام ناجائز، فتنہ انگیز اور’’قانون کی بدترین خلاف ورزی تھی“۔ لیکن اس سب کے بعد فیصلہ اُس عبادت گاہ کے خلاف سنانا کسی طرح قرین انصاف نہ تھا۔ بابری مسجد کے برعکس ان میں سے کوئی بھی بات قضیہ آیا صوفیہ پر صادق نہیں آتی۔ { FR 751 }
اس پوری بحث کا بڑا مذموم پہلو یہ تھا کہ بہتوں نے کلیسا کی وکالت کرتے کرتے سلطان محمد فاتحؒ کی شان میں گستاخی کا رویہ اپنانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ حالانکہ سلطان کی شخصیت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق تھی کہ،’’تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرکے رہو گے، وہ امیر بھی کیا خوب ہوگا اور وہ فوج بھی کیا خوب ہوگی‘‘(مسند احمد)۔ آپؐ کی اس پیشینگوئی کا یقیناً یہ مطلب نہیں کہ سلطان معصوم عن الخطا تھے، لیکن یہ مطلب ضرور ہے کہ وہ ایک عظیم فاتح اور ایک عظیم سلطان تھے، جن سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے اور سیکھا جانا چاہیے۔ اے کاش کہ اس محسنِ قسطنطنیہ کے حقیقی و فرضی عیوب کی ٹوہ میں پڑنے والے ان کی درخشاں زندگی سے سبق حاصل کرتے۔ اس ضمن میں فی الحال بالکل سرسری طور پر کچھ باتیں درج ذیل ہیں:
سلطان بطور فاتح کچھ ایسا مشہور ہوئے کہ ان کی علمی استعداد کی طرف عموماً دھیان نہیں جاتا۔ لیکن واضح رہے کہ وہ اعلیٰ ذہنی و علمی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ انھیں ترکی کے علاوہ عربی، فارسی، لاطینی، عبرانی، اور یونانی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ مطالعہ اور علمی گفتگو کا ذوق رکھتے تھے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ ادب، فلسفہ، اور تاریخ بالخصوص سلاطین و سالاروں کے تذکرے اور فنون جنگ سے متعلق ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا۔ سلطان کا ذاتی کتب خانہ بھی بہت بڑا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک علمی شہر سے سونے اور چاندی کے بدلے سلطان نے خراج میں کتابیں وصول کی تھیں۔ سلطان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عملی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی و علمی اُفق بھی وسیع ہو۔
قسطنطنیہ پر کئی 'ناکام چڑھائیاں ہوچکی تھیں۔ یہ ایک مشکل مہم تھی لیکن سلطان اس سے نہ گھبرائے بلکہ اللّٰہ پر توکل کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ اپنے عمل سے انھوں نے ہمیں مشکل مہمات سے نہ گھبرانے، ٹال مٹول نہ کرنے اور عزم و حوصلہ سے آگے بڑھنے کا سبق دیا۔
اس مہم کے لیے سلطان کچھ یونہی الل ٹپ انداز سے نہیں نکلے بلکہ باقاعدہ ایک طویل منصوبہ بنایا اور اس پر عمل درآمد کیا۔ اس منصوبے کے تحت انھوں نے متعدد شورشوں کو فرو کرکے اس بڑی مہم کے لیے خود کو یکسو کرلیا۔ کئی محاذوں پر صلح اور رشتہ داریاں قائم کرکے انھیں محفوظ کیا۔ کچھ فوجوں کو ایسے چنندہ علاقوں اور شاہراہوں پر مامور فرمایا، جہاں سے وہ قسطنطنیہ کی مدد کو آنے والے عساکر، رسد اور دیگر امداد کا راستہ روک سکیں۔ سلطان نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ بنایا۔ اس قلعے میں جدید ترین اسلحہ جات اور سامان حرب و ضرب کا ذخیرہ کیا۔ اسی طرح ایک بڑا بحری بیڑہ تیار کیا اور آبنائے باسفورس کی نقل و حرکت پر عملاً اپنا تسلط قائم کرلیا۔ ان تمام اقدامات کے ذریعے سلطان محمد فاتحؒ نے ہمیں توکل کے معنی سمجھائے اور بتایا کہ ایک طویل اور صبر آزما مہم درپیش ہو تو اس کی ہمہ پہلو منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے۔
شہر قسطنطنیہ کی اونچی فصیلیں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان دیواروں نے کل ۲۱ محاصروں میں شہر کی دشمنوں سے حفاظت کی تھی۔ سلطان نے ان دیواروں پر کامیاب حملے کے لیے خصوصی توپیں تیار کروائیں اور اس کے لیے ایک عیسائی انجینئر کی خدمات حاصل کیں۔ یوں انھوں نے ہمیں علم و صلاحیت کی قدر اور حکمت جہاں کہیں ہو اس سے استفادے کا عملی سبق دیا۔
محاصرے کے دوران جب معاملہ تقریباً بندگلی میں (stalemate ) پر پہنچ چکا تھا، بلکہ ایک بحری جھڑپ میں عثمانی بیڑے کو ہی ہزیمت اٹھانی پڑی تھی کیونکہ قسطنطنیہ کے جہاز بہت اونچے اور بڑے تھے جہاں سے عثمانی جہازوں پر آگ اور پتھر برسانا آسان تھا۔ سلطان، غور و فکر کے بعد، اس نتیجے پر پہنچے کہ گہرے پانی میں ان طاقت ور اور بڑے ڈیل ڈول والے جہازوں سے مقابلہ دشوار ہے، لیکن بندرگاہ کے بالائی حصے (گولڈن ہارن) میں جہاں پانی کم اور اتھلا ہے، وہاں چھوٹے اور سبک رفتار جہاز کارآمد اور بڑے قد و قامت والے جہاز بے کار ثابت ہوں گے۔ سلطان کے پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ اس حصے میں فصیل کی اونچائی اور خندق کی گہرائی بہ نسبت کم تھی لہٰذا لشکر اسلام کا بحری بیڑا اگر یہاں پہنچ جائے تو شہر پر کرارا حملہ کیا جاسکتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بندرگاہ کے اس حصے تک پہنچنے کے لیے جس بحری راستے کو اختیار کرنا پڑتا، اس پر بازنطینی بیڑے کا سخت پہرہ تھا۔ علاوہ ازیں سمندر کی جانب بندرگاہ کے دہانے پر مضبوط آہنی زنجیریں کچھ اس طرح باندھی گئی تھیں کہ کوئی جہاز بندرگاہ میں داخل نہ ہوسکتا تھا (بازنطینی جہازوں کے دخول کے لیے ان زنجیروں کو نیچے کردیا جاتا تھا)۔ اب صورتِ حال یہ تھی کہ بازنطینی بحری بیڑے سے کھلے سمندر میں تصادم مناسب نہیں تھا اور اس طاقت ور بیڑے اور زنجیر کی وجہ سے گولڈن ہارن پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔
سلطان نے یہ دیکھ کر ناممکن کو ممکن بنانے کی ٹھانی۔ اس نے کچھ ایسا طے کیا جس کا دشمن کو وہم و گمان بھی نہیں گزرا ہوگا۔ سلطان نے عثمانی بیڑے کو دشمن کے بحری بیڑے سے بچاکر بندرگاہ کے بالائی حصے تک پہنچانے کے لیے طے کیا کہ بحری نہیں بلکہ خشکی کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ خشکی پر کشتیاں چلانا سننے میں دیوانے کا خواب معلوم ہوتا ہے لیکن یہی سلطان کی جنگی حکمت عملی قرار پائی۔ انھوں نے ۷سے ۱۵ کلومیٹر لمبے ناہموار پہاڑی راستے پر لکڑی کے تختے بچھوائے، چربی اور تیل سے ان تختوں کو خوب چکنا کروایا، اور راتوں رات ۷۰،۸۰ کشتیوں کو ان تختوں پر کھنچوا کر بندرگاہ میں اتار دیا۔ دشمن کی توجہ خشکی پر چلتی ہوئی ان کشتیوں کی طرف نہ ہوسکے، اس کے لیے عثمانی توپوں نے اُس رات جم کر گولہ باری کی۔ یوں صبح سویرے جب عثمانی بیڑا آہنی زنجیروں کے علی الرغم اور بغیر بازنطینی بیڑے سے متصادم ہوئے گولڈن ہارن میں آموجود ہوا، تو دشمن کے حوصلے پست ہوگئے اور فتح کی راہ ہموار ہوگئی۔ سلطان کی اس جنگی حکمت عملی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اور دشمن کی کمزوری اور طاقت کو جاننا، اپنی کمزوری کو اپنی طاقت اور دشمن کی طاقت کو اس کی کمزوری میں بدل دینا فتح کے لیے ناگزیر ہے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ کشتیوں کو خشکی پہ چلانے کی اس غیرروایتی حکمت عملی (out of the box strategy) کی وجہ سے میدان اسلامی افواج کے ہاتھ رہا۔ اس سے ہمیں ابتدائی جھٹکوں سے ناامید نہ ہونے، نئی سوچ اور نئی تدبیر اختیار کرنے اور نئے تجربات کرنے کا شاندار درس ملتا ہے۔
فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے مفتوح شہریوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا رویہ اختیار کیا۔ انھوں نے شہر چھوڑ کر بھاگ جانے والے عیسائیوں کو دوبارہ اپنے وطن لوٹ آنے اور اپنے پیشوں اور روزگار سے بے جھجک منسلک ہوجانے کی دعوت دی۔ رعایا کو مکمل مذہبی آزادی عطا کی۔ یونانی آرتھوڈوکس بطریق کو اپنے مذہبی عہدے پر برقرار رکھا، اسے مذہبی معاملات میں مکمل آزادی دی۔ درکار مالی عطیات اور مستقل مالی اعانت دی، اور کلیسا کی سرپرستی خود قبول کی، مذہبی عہدے داروں کے ٹیکس معاف کردیے۔ پرسنل لا کی آزادی کے علاوہ مسیحیوں کو اپنے مقدمات اپنے قوانین کے مطابق فیصل کرنے کی سہولت بخشی۔ ان عدالتوں کے احکام کا نفاذ ریاست کے ذمے تھا۔ ان عدالتوں کو قید اور سزاے موت تک دینے کے اختیارات حاصل تھے۔ عزیر احمد اپنی کتاب دولت عثمانیہ میں ایورسلے کی شہادت نقل کرتے ہیں کہ سلطان کی یہ’عظیم الشان رواداری‘دراصل’مسیحی یورپین سیاسی اخلاقیات سے بہت آگے تھی“۔ تھامس آرنلڈ نے بھی اپنی کتاب The Spread of Islam میں سلطان کا تذکرہ بڑے ادب و احترام سے کیا ہے۔ اور مفتوح آبادی کے ساتھ اس کے سلوک کو دل جیتنے والا سلوک قرار دیا ہے، جس کے بعد یونانی عوام ہر قسم کے عیسائی تسلط پر مسلمانوں کی حکومت کو ترجیح دینے لگے تھے۔
فتح قسطنطنیہ کے وقت سلطان محمد فاتحؒ کی عمر محض۲۳ سال تھی۔ جوانی کی اس عمر میں سلطنت کو سنبھالا دینا، دقیقہ رسی اور باریک بینی کے ساتھ منصوبہ بنانا اور اس پر عمل درآمد کرانا، نامساعد حالات سے نہ گھبرانا بلکہ نئی نئی راہیں نکالنا، بازنطینی سلطنت سے پنجہ آزمائی کرنا اور اسے شکست فاش دے دینا، سلطان کا تاریخ ساز کارنامہ ہے۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی عملی شہادت ہے کہ بڑے کارناموں کا تعلق بڑی عمر سے نہیں بلکہ بڑے عزائم سے ہوتا ہے۔
۱- ہمیں تنقید برائے تنقید سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں اپنی تنقید کے عملی عواقب پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اسی مسئلے میں مسجد کا چرچ ہونا نہ صرف عدل کے خلاف ہوتا بلکہ ناقابلِ عمل اور نئے فتنوں کے دروازے کھلنے پر منتج ہوتا۔ ایسا فیصلہ جو قانون کے بھی خلاف ہو اور نظم و نسق کے بھی، بھلا کیونکر کیا جاتا؟ پھر انسان کو اپنے دلائل کے منطقی انجام سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ جس دلیل سے عیسائیوں کے کسی مطالبے کے بغیر چرچ عیسائیوں کے سپرد کردینا قرین انصاف تھا۔ اسی دلیل سے آیا صوفیہ کا چرچ سے پہلے والے کسی دوسرے مذاہب کے معبد بحال ہونا بھلا عدل کا تقاضا کیوں نہیں تھا؟
۲-اس بحث کے دوران فقہ اسلامی کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور پیدا کی بھی گئیں۔ مثلاً یہ یک رخی دلیل دی گئی کہ سیرت سے فتح مکہ کا ماڈل ملتا ہے جہاں مفتوحین کی جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اسی سیرت پاکؐ میں اور پھر خلفاے راشدینؓ کی سیرت میں مال غنیمت لیے جانے، بتکدوں اور کلیساؤں کے ڈھائے جانے، جنگ کے قابل افراد کو تہہ تیغ کیے جانے، اور غلام بنالیے جانے کے واقعات بھی، بہت بہت ہی کم سہی مگر، موجود ہیں۔ یہ وہی باتیں ہیں جن کو فقہ سے منسوب کرکے کچھ ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی جیسے فقہ اسلامی قرآن و سنت سے یکسر آزاد کوئی علم ہو۔
کیا ہی اچھا ہو کہ اس موقع پر ہمارے نوجوان فقہ کا ایک تعارف حاصل کریں۔ ایک فقیہ اپنے زمانے کے مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح حل تلاش کرتا ہے؟ فقہی علوم کے ارتقا پر اس سوال کی روشنی میں غور کریں کہ فقہ کی پرانی کتابوں میں درج کچھ احکامات کیوں آج ہمیں عجیب نظر آتے ہیں۔ آپ اگر فقہ کا ایک آسان لیکن بھرپور تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر محمود احمد غازی کی محاضرات فقہ کا مطالعہ ضرور کریں، تاکہ اسلاف کے اس عظیم الشان علمی کارنامے کی اہمیت و افادیت سے آشنا ہوں، ان کی علمی میراث کے بارے میں مبنی بر انصاف رائے قائم کرسکیں، اور اسے آگے بڑھانے کے بارے میں سوچیں نہ کہ اسے رد کردینے کے۔ اسی طرح بین الاقوامی قانون کے سلسلے میں فقہاے اسلام کی کاوشوں کا مطالعہ ہو تو شاید یہ اس بحث کا سب سے سود مند نتیجہ ثابت ہو۔ حد تو یہ ہے کہ مدارس میں بھی اب یہ کتابیں شاید ہی پڑھائی جاتی ہوں۔ نقدو تحقیق سے دل چسپی رکھنے والے نوجوانوں کے لیے ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ وہ امام ابویوسف کی کتاب الخراج اور امام محمد الشیبانی کی السیر الصغیرکا مطالعہ ضرور کرلیں۔ جو باتیں کھٹکیں ان پر ٹھیر کر دلائل کی روشنی میں غور کریں، اس تعلق سے بزرگوں سے استفسار بھی کریں۔ امید کی جاتی ہے کہ جو لوگ اس وقت کنفیوژن کے شاکی ہیں، انھیں اس مطالعے کے نتیجے میں شرح صدر حاصل ہوگا اور وہ شریعت کی حکمت و وسعت کی کنہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے، جو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے الفاظ میں درج ذیل ہے،’’خود شریعت نے اس بات کی گنجایش رکھی ہے کہ بعض احکام میں ایک سے زائد آراء ہوں۔ ایسا اس لیے ہے کہ شریعت زمان و مکان سے ماوراء ہے۔ ممکن ہے کہ ایک تعبیر بعض خاص حالات میں زیادہ برمحل ہو اور دوسری تعبیر دوسرے حالات میں زیادہ موزوں ثابت ہو‘‘۔
۳- یہ بات ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے لیکن ذہنوں میں اس کا ہر آن استحضار ضروری ہے کہ شریعت کا ماخذ احکام الٰہی ہیں۔ ہم انسان، زمان و مکان کی قیود میں جکڑا ہوا ایک ناتواں اور فانی وجود رکھتے ہیں۔ اور اللّٰہ کی ذات لافانی، زمان و مکان کی قیود سے ماورا، اور علم حقیقی و لازوال حکمت کا سرچشمہ ہے۔ لہٰذا ہم احکام کے مصالح پر تو غور کریں، لیکن کوئی چیز ہماری عقل کے چوکھٹے میں نہ سمائے تو اسے رد کرنے سے احتراز کریں۔ مولانا امین احسن اصلاحیؒ فرماتے ہیں:’’خدا کی ہربات کے اندر نہایت گہری حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن ان تمام حکمتوں اور مصلحتوں سے جب تک اللّٰہ تعالی ہی واقف نہ کرے، نہ ان سے جنات واقف ہو سکتے ہیں، نہ فرشتے اور نہ انسان۔ اللّٰہ تعالیٰ کے کاموں کے بارے میں صحیح روش انسان کے لیے یہ ہے کہ ان کی حکمتیں معلوم کرنے کی کوشش تو برابر کرتا رہے، لیکن اگر کسی چیز کی حکمت اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ہدفِ اعتراض و مخالفت نہ بنالے بلکہ یہ حسن ظن رکھے کہ اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی لیکن اپنے علم کی کمی کے سبب سے وہ اس حکمت کو سمجھ نہیں سکا ہے۔ رہے وہ لوگ جو اپنے نہایت قلیل اور محدود علم کو خدا کے علم اور اس کی حکمتوں کے ناپنے کا پیمانہ بنا بیٹھے ہیں، تو وہ اسی قسم کی خودسری اور انانیت میں مبتلا ہوجاتے ہیں، جس قسم کی خود سری اور انانیت میں ابلیس مبتلا ہوگیا۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے ایمان و معرفت کے راستے کھلتے نہیں بلکہ جو راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی بند ہو جایا کرتے ہیں۔‘‘(تدبر قرآن، جلد اول، ۱۷۳)
۴-تاریخ کے سلسلے میں ہمارا رویہ اعتدال و توازن پر مبنی ہونا چاہیے۔ اسے رد کردینا اور اس سے سبق حاصل نہ کرنے کا رجحان خطرناک ہے۔ احساسِ کمتری میں مبتلا ہوکر سیاق و سباق کو یکسر فراموش کرکے اسلاف پر تنقید کرنا بھی صحت مند طرزِ عمل نہیں ہے۔ دوسری طرف انسانوں کی اس تاریخ کو فرشتوں کی تاریخ سمجھنا بھی سادہ لوحی ہے اور اس پر فخر کرتے ہوئے حال اور مستقبل کو فراموش کرجانا تو حماقت کی انتہا ہے۔ تاریخ کے سلسلے میں معتدل رویہ یہ ہے کہ ہم اپنے روشن و زریں ماضی کا اعتراف کریں۔ ہماری چودہ سو سالہ تاریخ، بلند حوصلہ انسانوں کی تاریخ ہے، جو بحیثیت مجموعی قرآن و سنت سے فیض یافتہ تھے۔ ان کی بلند حوصلگی اور قرآن و سنت کی پاسداری کی وجہ سے تاریخ ان کے تاریخ ساز اور معجزہ نما کارناموں سے عبارت ہے، وہیں چونکہ وہ انسان تھے اسی لیے ان کی کمزوریاں بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ معتدل طرزِ فکر و عمل یہ ہے کہ خوبیوں کا اعتراف ہو، ان کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہو تاکہ نئی نسل احساس کمتری کے خول سے باہر نکلے، اسے تحریک اور جذبہ اور قابلِ تقلید ہیرو ملیں۔ اسی طرح خامیوں سے واقفیت بھی ضروری ہے تاکہ تاریخ کی تنقیدی سمجھ پیدا ہو اور ہیرو ورشپ کی قباحتوں سے بچا جاسکے۔ بس خیال اس بات کا ضروری ہے کہ تنقید کرتے وقت بھی اعتدال اور حسن ظن کا دامن نہ چھوٹے، بدگمانی اور کردار کشی سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے، اور کوتاہیوں کی وجوہ تلاش کی جائیں تاکہ ٹھوکر لگنے کے اسباب بھی پتا چلیں اور ماضی کی کمزوریوں کی تلاش لعن طعن سے اوپر اٹھ کر مستقبل کی تعمیر کی ایک سرگرمی بن جائے۔
۵-یہ اصول ہر ملک کی طرح ترکی پر بھی صادق آتا ہے کہ دور حاضر کے حالات کو سمجھنے کے لیے ماضی قریب کی تاریخ کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ بیسویں صدی میں ترکی کس طرح جنگ عظیم اول کی ہزیمت، معاہدہ سیورس، سقوط خلافت اور سیکولر استعمار سے گزرا ہے، اسے جانے بغیر ترک سیاست اور وہاں کے اسلام پسندوں پر تبصرے لایعنی ہیں۔ یہ اچھا موقع تھا جب ہم کچھ اور نہیں تو کم از کم بیسویں صدی میں اللّٰہ کے دین کے لیے ترکوں کی جدوجہد کا مطالعہ کرتے۔ یہ وہ روشن تاریخ ہے جس میں حلیم پاشا، بدیع الزماں سعید نورسی اور نجم الدین اربکان وغیرہ مختلف افکار اور مختلف حکمت عملیوں کے ساتھ اپنی جدوجہد میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس تاریخ میں بھی ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔
سیّد منور حسن کا دنیا سے رخصت ہونا ہم سب کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت سے کسی کو مفر نہیں۔ ۲۶جون سے آج تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ پیارے منور بھائی کا خیال دل و دماغ سے اوجھل ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، اور انھیں جنّت کے اعلیٰ مقامات پر اَبدی زندگی سے سرفراز فرمائے،آمین!
حقیقت یہ ہے کہ منور بھائی، تحریک ِ اسلامی کا قیمتی سرمایہ اور دورِ حاضر میں اسلام کی ایک قیمتی متاع تھے۔ مجھے ان کے ساتھ ۶۰سال بہت قریب اور ہرحیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا، یعنی: ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، تحریک کے ایک کارکن اور ساتھی کی حیثیت سے، میرے ساتھ علمی کام کرنے والے ایک معاون کی حیثیت سے، اور میرے امیر کی حیثیت سے۔ الحمدللہ، ہرحیثیت سے ہمارا تعلق احترام، محبت اور تعاون کا رہا ہے۔ انھیں ہرحیثیت میں ایک بہت اچھا انسان اور ایک بڑا سچا مسلمان اور تحریک اسلامی کا ایک مخلص اور بہترین خادم پایا۔ بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط تر بنانے، مقصد کی لگن میں یکسو ہونے، اور شہادتِ حق کے راستے پر ثبات و استقامت سے جدوجہد میں اپنے آپ کو گھلادینے کی منزل پر جاپہنچے تھے۔ اسی طرح جہاں دنیا کو اسلام کے رنگ میں ڈھالنے کا جذبہ، کوشش اور تڑپ تھی، وہیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کنارہ کشی، سادگی، اخلاص، للہیت، قناعت اور درویشی ان کی زندگی کے امتیازی پہلو تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمیں منور بھائی کی زندگی میں سلف کی زندگی کی ایک جھلک نظر آتی تھی۔
۱۹۶۰ء میں جب وہ عزیزی آصف صدیقی کی دعوتی مساعی کے نتیجے میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوئے، اسی وقت سے میرا اُن سے قریبی تعلق رہا۔ شروع میں ایک زیرتربیت ساتھی اور اجتماعی مطالعے میں شریک کی حیثیت سے ربط قائم ہوا۔ ۱۹۶۲ء میں جب محترم چودھری غلام محمد مرحوم کے ایما اور داعی تحریک مولانا سیّد ابوالاعلیٰ مودودی کی سرپرستی میں کراچی میں اسلامک ریسرچ اکیڈمی قائم کی گئی تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ناظم تھے۔ اس وقت انھوں نے ایم اے سوشیالوجی کیا تھا۔ تب اپنے نوجوان ساتھیوں کی جو پہلی ٹیم بطور اسسٹنٹ میں نے بنائی، اس میں وہ شامل تھے۔ اکتوبر۱۹۶۴ء میں وہ شیخ محبوب علی بھائی کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے اور نظامت اعلیٰ سے فارغ ہوتے ہی جماعت اسلامی کے رکن بنے اور کراچی جماعت کے نظم کو اپنی خدمات پیش کردیں۔ اسی دوران ۱۹۶۸ء میں مَیں برطانیہ چلا گیا تو اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے سیکرٹری کی حیثیت سے انھوں نے اس علمی و تحقیقی ادارے کا نظم سنبھالا۔ انگریزی ماہنامے The Critarion اور پھر Universal Message کے مدیر رہے۔ایک مدت تک کراچی جماعت کے قیم اور پھر کراچی جماعت کے امیر بنے۔ ازاں بعد ۱۹۹۲ء میں جماعت اسلامی پاکستان کے قیم بنے۔ ۲۰۰۹ء میں امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب ہوئے اور پھر امارت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے بعد ۲۰۱۴ء میں دوبارہ اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی میں آخری لمحات تک علمی اور اجتماعی خدمات سرانجام دیتے رہے۔
منور بھائی کو میری اور برادرم ڈاکٹر انیس احمد کی طرح مولانا مودودیؒ کی یہ محبت حاصل رہی کہ وہ ہم کو پیار سے خورشیدمیاں، انیس میاں اور منور میاں کہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد نذیر احمد قریشی صاحب کی طرح منوربھائی کے والد محترم سیّد اخلاق حسن صاحب بھی مولانا کے قیام دہلی کے زمانے کے احباب میں سے تھے اور آخری وقت تک ان کے گہرے ذاتی تعلقات رہے۔
منور بھائی کی زندگی کا سب سے غالب پہلو مقصدیت ہے۔ جس پیغام اور دعوت کو انھوں نے شعور کے ساتھ قبول کیا، پھر زندگی بھر اس پر وہ یکسو ہوگئے۔ جس چیز کو انھوں نے حق سمجھ کر اپنی زندگی کا مقصد بنالیا، آخر دم تک اس سےوفاداری کا حق ادا کیا، اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے، اس کے لیے قربانی دی اور ایسی سعادت کی زندگی کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ تج دیا۔
دوسری قابلِ رشک خوبی اعلیٰ درجے کا نظم و ضبط (ڈسپلن) تھا۔ ان کی زندگی میں جو بے پناہ نظم پایاجاتا تھا، اس کی مثال سوائے چند لوگوں کے، مَیں کہیںاور نہیں دیکھ سکا۔ ان میں اپنے تمام کاموں کو مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دینے کی صلاحیت پائی جاتی تھی۔ وہ ایک ایک لمحہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سوچتے، پروگرام بناتے اور پھر اس پر عمل درآمد کرتے تھے۔ یعنی منصوبہ سازی، جائزہ، نفاذ اور تنظیمی ڈھانچے کی تیاری۔
مجھے اس بات کا بہت دُکھ ہے کہ آج تحریک میں علمی ذوق کم ہورہا ہے اور مطالعہ تو اس سے بھی کم ہے۔ دوسری طرف منور بھائی کو دیکھتا ہوں تو گو انھوں نے لکھا کم ہے، لیکن ان کا مطالعہ وسیع تھا۔ ان کی تقریر میں گہرائی اور جذبہ تھا۔ گفتگو میں علمی وژن، حاضردماغی اور دلیل تھی۔ وہ تحریک کے مسائل و معاملات پر مسلسل غوروفکر کرتے تھے کہ یہی ہمارا شعار ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔
منور بھائی ایک غیرمعمولی مقرر تھے۔ فطری خطابت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا تھا۔ تقریر میں وہ سحر باندھ دیتے تھے۔ برجستگی اور مزاح سے، بڑے نپے تلے جملوں اور کم الفاظ میں بڑی بات کہنا ان کا طرئہ امتیازتھا۔ بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ وہ بڑے خوش الحان اور خوش گلو بھی تھے۔ کلامِ اقبال پڑھنے اور سنانے کا شان دار ذوق رکھتے تھے۔
مقصدیت، قیادت، اَن تھک جدوجہد اور محنت کے ساتھ ساتھ نماز سے تعلق میں عشق کی کیفیت کا مظہر تھے۔ عبادت میں خشوع و خضوع کی جو چاشنی میں نے ان کے لڑکپن سے ان میں دیکھی، وہ مثالی تھی۔ کراچی میں ان کوایک ایک مسجد کا پتا تھا کہ کس مسجد میں کس وقت نماز ہوتی تھی؟ اگر کسی ایک مسجد میں جماعت سے نماز چھوٹ جاتی تھی تو دوسری مسجد میں جاکر باجماعت پڑھتے تھے۔ اس پہلو سے منور بھائی اس دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کی ایک اچھی مثال تھے۔
قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلہِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۱۶۲ۙ لَا شَرِيْكَ لَہٗ۰ۚ (الانعام ۶:۱۶۲-۱۶۳) کہو، میری نماز، میرے تمام مراسمِ عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ ربّ العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔
تحریک کی قیادت کے دوران ایک طرف انھوں نے بحیثیت امیر اپنی راے کا برملا اظہار کیا، تو وہاں دوسری طرف شوریٰ اور عاملہ نے جو بات طے کردی، انھوں نے پوری وفاداری کے ساتھ اس پر عمل کیا ۔ اپنی امارت کے دوران دعوت الی اللہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت دینے کے ساتھ، طاغوت کی شیطنت کو بے نقاب کرنے میں لمحہ بھر غافل نہ رہے۔
اسی طرح منوربھائی تحریک اسلامی کے تمام طبقات خصوصاً علماے کرام، اساتذہ، صحافتی برادری، ادیبوں،دانش وروں ،مزدور تنظیموں اور یونینوں سےربط اور رہنمائی کے لیے ہروقت مستعد رہتے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان انھیں حددرجہ محبوب تھے، جن کی تربیت اور حوصلہ افزائی کے لیے دامے، درمے اور سخنے، وہ ان کے ہم قدم رہتے۔ پھر ہزاروں کارکنوں سے بالکل ذاتی سطح پر خط، ملاقات اور پیغام کے ذریعے رابطہ رکھ کر انھیں مقصد ِ زندگی سے جڑے رہنے کے لیے اُبھارتے رہتے تھے۔ یہ فرائض، ان کی منصبی ذمہ داریوں کا حصہ نہ تھے، لیکن ان کے جذبے کا عملی مظہر تھے۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کو ایک مجاہد فی سبیل اللہ پایا۔ مجھے یقین ہے کہ ان شاء اللہ ان کا شمار، اللہ کے ان خوش نصیب بندوں میں ہوگا، جن کے لیے قرآن نے فرمایا ہے:
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاہَدُوا اللہَ عَلَيْہِ فَمِنْہُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَہٗ وَمِنْہُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ۰ۡۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا۲۳ۙ (احزاب ۳۳:۲۳)ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنھوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کردکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کرچکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انھوں نے اپنے رویّے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔
اللہ تعالیٰ ان کی تمام مساعی اور قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی بشری لغزشوں سے درگزر فرمائے، انھیں کروٹ کروٹ جنّت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ انھوں نے اُمت مسلمہ کے لیے، تحریک اسلامی کے لیے اور دعوتِ حق سے وابستہ افراد کی زندگیوں کو مسلسل جدوجہد کے جذبے سے سرشار کرنے کے لیے ایک روشن مثال قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی نیک اور اچھی روایات کا احترام کرنے اور اس روش پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ ہمیں دینِ حق پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ کرے۔ دعوتِ دین کی تحریک میں، ملک میں اور اُمت اسلامیہ میں، ان کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوگیا ہے، اللہ تعالیٰ اس خلا کو پُر کرنے کا سامان کردے، آمین!
ہمیشہ کی طرح اُس روز بھی صبح اپنے وقت پر طلوع ہوئی تھی۔ ابھی سویرا تھا، اس لیے زیادہ تر لوگ اپنے اپنے گھروں کی حصار میں تھے ، کاروبار زندگی کی شروعات بھی مدہم تھی۔ یکایک شمالی کشمیر کے ہنگامہ خیز قصبہ سوپور کے محلہ ماڈل ٹاؤن کی فضا میں ایک ایسا الم ناک ارتعاش ہوا، جس سے پوراعلاقہ لرز اُٹھا۔ پلک جھپکتے ہی سکوتِ صبح کا سماں غارت ہوا۔ فائرنگ کے شور سے لوگ سہم گئے، تشویش کی لہریں اورفکر مندی کی موجیں ہر شخص کو نیم جان کرگئیں۔ نیم فوجی دستوں اور پولیس کے ساتھ بندوق بردار مقامیوں کی مڈبھیڑاپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، عام کشمیری ایسی خون ریزیوں سے مانوس ہیں۔ کسی بستی میں مسلح جھڑپ ہونا لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک ہی پیغام لاتی ہے کہ ’’جائے وقوعہ میں اب کسی کی کوئی خیر نہیں‘‘۔ عمومی حالات میں وادی کشمیر کی کسی بستی، بازار ، شہر یا دیہات میں بندوقوں کی گڑ گڑاہٹ اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے پتا چلتا ہے کہ مسلح فورسز اور عسکریت پسندوں کے بیچ جھڑپ چھڑگئی ہے اور ہر جھڑپ اپنے پیچھے ہلاکتوں اور تباہ کاریوں کی ایک بھیانک کہانی ضرور چھوڑ کر جائے گی۔ دو طرفہ گولی باری چاہے سرحد پر ہو یا کسی میدانی علاقے میں ، ہر حال میں یہ عوام الناس کے لیے اپنے ساتھ شامتیں، قیامتیں اور میتیں ہی لاتی ہیں ۔
ماڈل ٹاؤن سوپور میں ۳۰ جون ۲۰۲۰ء کو یہی درد ناک کہانی دہرائی گئی۔ یہاں کے رہایشیوں کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ اُن کے گھر کے آنگن میں ایک ایسا المیہ وقوع پذیر ہونے جارہا ہے، جس سے انسانیت کا کلیجہ پھٹ جائے گا، آدمیت کی چیخیں نکل جائیں گی، آنسوؤں کا سیل رواں اُمڈ آئے گا ، غم واَلم کی گرم بازاری ہو گی اور سوگواریت کی سیاہی چھا جائے گی۔ چشم فلک نے ماڈل ٹاؤن میں صبح قریب سات بجے کشمیر کی خونیں تاریخ کا ایک اور لہولہاں باب رقم ہوتے دیکھا ۔ ایک درد انگیز کہانی،ایک الم ناک منظر ، ایک ناقابل یقین المیہ کہ جس سے پوری وادی سوگواری کی دُھند میں ڈوب گئی ۔
میڈیا کی تفصیلات کے مطابق بستی میں عسکریت پسندوں نے ایک مقامی مسجد کے اندرسے فورسز کی گشتی پارٹی پر گھات لگاکر حملہ کیا ۔ حملے میں سنٹرل ریزو پولیس کا ایک اہل کار موقع پر ہلاک ہوا، جب کہ تین اہل کار زخمی ہوئے ۔ ابھی جھڑپ جاری تھی کہ جاے وقوعہ سے مصطفیٰ آباد ایچ ایم ٹی سری نگر کے بشیر احمد خان نامی ایک ۶۵ سالہ ٹھیکے دار کا گزر ہو ا۔ وہ اپنے نجی کام سے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ اُن کے ہمراہ فرنٹ سیٹ پر اُن کا تین سالہ پوتا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ بشیراحمد کے بارے میں سرکاری طور دعویٰ کیا گیا کہ موصوف کراس فائرنگ کی نذر ہو کر ہلاک ہو گئے۔ ابھی یہ خون ریزجھڑپ جاری تھی کہ اس کی خبریں اور تصویریں، سوشل میڈیا کے کاندھوں پر برق رفتاری کے ساتھ سفر کرتی ہوئی منٹوں میں پورے عالم میں پہنچ گئیں اور انھیں پتاچلاکہ سوپور میں کون سی نئی قیامت بپا ہوئی ہے ۔
بشیر احمد خان متعدد گولیاں لگنے سے برسر موقع شہادت کی خونیں قباپہن کر دنیا چھوڑ گئے۔ اس الم ناک واقعے کے بارے میں سرکاری طور کہا گیا کہ ماڈل ٹاؤن سوپور میں سی آر پی ایف کی گشتی پارٹی پر جنگجوؤں نے اچانک دھاوا بولا۔ گشتی پارٹی نے پوزیشن سنبھالی اور دوطرفہ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا،جس کی زد میں آکر ایک سویلین بھی جان بحق ہوا ۔ ٹی وی چینلوں پر جھڑپ کی خبر میں یہ بات نمایاں طور پر فوٹیج کے ذریعے اُجاگر کی گئی کہ’’ زبردست فائرنگ کے باوجود نیم فوجی جوانوں نے جان کی پروا نہ کرکے تین برس کے معصوم بچے کو بچا لیا، جو انسانیت کی ایک اعلیٰ مثال ہے‘‘۔ مگر مارے گئے شہری کے اہل خانہ نے سانحے کے بارے میں اس موقف کومسترد کر تے ہوئے فورسز پر الزام عائد کیا کہ بشیر احمد خان صاحب کو گاڑی سے اُتارا گیا اور پھر اُن کے سینے میں گولیاں پیوست کی گئیں۔ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدے دار نے اس الزام کی سختی سے تردید کی۔ اپنے ردعمل میں نیشنل کانفرنس اور سیاسی جماعتوں نے سوپور سانحہ کی بابت سرکاری موقف کو نہ صحیح مانا اور نہ غلط کہا، بلکہ گھسی پٹی روایت کی گردان کرتے ہوئے حکومت سے اس کی تحقیقات کر نے کا مطالبہ کیا۔ آج تک کشمیر میں ایسے درجنوں سانحات کی سرکاری انکوائریاں بٹھائی گئیں، مگر نہ کبھی اُن کی رپورٹیں منظر عام پر لائی گئیں اور نہ کسی مجرم کی نشان دہی کر کے اسے عدالت کے کٹہرے سے کوئی سزاسنائی گئی ؎
اذیت ، مصیبت ، ملامت ، بلائیں
ترے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا
بظاہر سوپور المیے کا نفس مضمون اتنا ہی کچھ ہے، لیکن جو چیز حساس دل انسانوں کے زاویۂ نگاہ سے انسانیت کے منہ پر زبردست طمانچہ رسید کرتی ہے، وہ شہید بشیر احمد کے معصوم پوتےکی وہ دل خراش تصویریں ہیں، جنھیں کسی نامعلوم شخص نے کھینچا اور انھیں سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ ان تصاویر نے کشمیری عوام کو اُسی طرح خون کے آنسو رُلا دیا جیسے کئی سال قبل شام کے اُس معصوم مہاجر بچے کی ساحل سمندر پر اوندھے منہ پڑی لاش سے عالم عرب اشک بار ہوا تھا، اور وہ تصویر شامی مہاجرین کی اَن کہی بپتا کا استعارہ بن گئی تھی ۔ سوپور جھڑپ کے متاثرہ کشمیری بچے کی منہ بولتی تصویریں بزبان حال بتاتی ہیں کہ اِدھر گولیوں سے چھلنی اس کے دادا کی بے گور و کفن لاش سڑک پر پڑی ہے ، اُدھر اس کا پھول جیسا پوتا اپنے مرے ہوئے دادا کی چھاتی پر بیٹھاہے، شاید اس کو گہری نیند سے جگانے کے لیے ۔ رنج وغم اس بچے کے چہرے سے جھلک رہاہے ۔ وہ یہ بات تو جانتا ہی نہیں کہ اس کی معصوم دنیا لمحے بھر میں لٹ چکی ہے ۔ معصوم وکم سن بچہ اپنے دادا کی ابدی جدائی کی حقیقت سے بھی ناآشنا ہے۔ موت کیا ہے، زندگی کیاہے؟ یہ باریکیاں اس کے پلے نہیں پڑسکتیں ۔ بس یہ صرف سہما ہوا سا بچہ ہے، جو خوف کے عالم میں لہو لہو منظر دیکھ کر بھی اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے ، بھیڑ میں تنہا ہے، بے دست وپا ہے، اور وہ جو اس کو سینے سے لگا کر سہلاتا، اس کا درد وکرب کم کر تا، وہ تو زمین پر بے حس وحرکت پڑا ہے۔ ناقابلِ فہم خونی منظر سے نڈھال بچے کی ہچکیاں اور سسکیاں بند کر نے کے لیے پولیس نے اُسے چاکلیٹ اور ٹافیوں سے بہلایا، مگر وہ تھا کہ آنسو بہاتا رہا۔
وادی کشمیر کے بارے میں بھولے سے کبھی ایک بار بھی یہ دل خوش کن خبر نہیں آتی کہ آج یہاں کوئی ناخوش گوار واقعہ رُونما نہیں ہوا ۔ ارباب سیاست اور اہل سلطنت جو چاہیں کہیں، مگر عملی دنیا کی ٹھوس حقیقت یہ ہے کہ کشمیر اور امن حسب سابق اجتماعِ ضدین ہیں۔ یہاں روز وردی پوشوں اور عسکریت پسندوں کے درمیان مسلح جھڑپیں اور آتش و آہن کی برساتیں نئی زخم زخم کہانیوں کو جنم دیتی ہیں۔ یہاں لاشیں گرتی ہیں ، یہاں جنازے اُٹھتے ہیں ، یہاں ماتم ہوتے ہیں، یہاں نالہ وفغاں، آہ وبکا اور چیخ پکار ایک عام چیز ہے ۔ ایسے میں انسانی حقوق نامساعد حالات کے بھینٹ نہ چڑھ جائیں یہ سوچنا بھی محال ہے ۔ یہ تلخ حقیقت کبھی سوپور جیسے المیوں کا رُوپ دھارتی ہے اور چندبرس پہلے وقوع پذیر کھٹوعہ کی آصفہ کی دلدوز کہانی کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے۔
تصویر کا ایک رُخ یہ ہے کہ گذشتہ ۳۰سال سے وادی گلپوش میں ’آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ‘ (’افسپا‘) نافذالعمل ہے۔ اس کے نفاذ کی سفاکی اور خون آشامی کے چھینٹے اور دھبے آج کشمیر کے چپے چپے پر بتمام وکمال پائے جاتے ہیں۔ ایسے حالات سے روز روز سامنا کرتے ہوئے عام کشمیریوں کے لیے یہ تمام ناقابل تصور قیامتیں معمولاتِ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں ۔ لوگوں میں یہ ناگفتہ بہ حالات دیکھنے ، سننے اور سہنے کی عادت سی پڑگئی ہے ۔ گذشتہ ۳۰ سال سے کشمیری معاشرہ انھی کے درمیان غیر یقینی زندگی جیتے ہوئے شادی غمی سمیت تعلیمی ، معاشی اور سماجی مشاغل سرانجام دیتا آرہا ہے۔
تصویر کا دوسرا رُخ یہ بتاتا ہے کہ یہاں کی بالا دست سیاسی اور اقتداری قوتیں ماہ وسال سے جنت بے نظیر میں لامتناہی خوں بار سلسلہ روکنے اور امن کی بہاریں لوٹانے کے بلند بانگ دعوے کرتی رہیں۔ ’افسپا‘ کو واپس لینے کے وعدے بھی ہوئے، تعمیر وترقی اور خوش حالی کے دعوے بھی کیے گئے۔ ان سب بہلاوں کے درمیان تاریخ نے وادی میں کئی کروٹیں بدلتی اور بہت ساری چیزیں بنتے بگڑتے دیکھیں مگر جو چیز دیکھنے کی حسرت رہی وہ یہ کہ یہاں مکمل اور پاےدار امن کبھی قائم نہ ہوا۔ عظیم تر خودمختاری کا وعدہ ، واجپائی کی لاہور بس یاترا، انسانیت، کشمیریت اورجمہوریت کا نعرہ ، نوازشریف کا امن اعلامیہ، مشرف کا چار نکاتی فارمولا، ظفراللہ خان جمالی کی جنگ بندی ، سہ رُکنی مصالحتی کمیٹی کاقیام، من موہن سنگھ کی گول میز کانفرنسیں، آٹھ ورکنگ گروپوں کی تشکیل، ’گولی سے نہ گالی سے ،مسئلے کاحل کشمیری گلے لگانے میں‘ جیسا جاذب نظر نعرہ اور پھر دفعہ ۳۷۰ اور ۳۵اے کی تنسیخ، غیر ریاستی باشندوں میں ڈومسائل اسناد کی تقسیم وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ نے ہربار نمایاں اور طاقت ور لوگوں کی زبانی دل کے کانوں سے یہ دعوے سنے کہ اب کی بار کشمیر میں امن و اَمان کی ہریالیاں ہوں گی ‘ تعمیرو ترقی کی پھلواریاں مہکیں گی، مگر واے ناکامی نہ نامساعد حالات کا محور آج تک بدلا، نہ امن وآشتی کاسورج کبھی طلوع ہوا۔اس کے برعکس حسب سابق سلسلہ روز وشب کی گردش میں خون ریزیاں کشمیر یوں کا مقدر بنی رہیں۔ آج تک گردش لیل ونہار کی اسی آتشیں فضا میں کشمیر کی تین دہائیاں بھسم ہو گئیں۔ لاتعداد پیر و جوان، خواتین ، بچے ، ابدی نیند سوگئے ، تباہیاں نوشتۂ دیوار بن گئیں۔ آتش زنیاں اور آبرو ریزیاں اتنی بے حساب گویا یہ انسانیت کے خلاف جرائم ہی نہیں رہے۔ عقوبت خانے اور زندان آباد ہوئے ، تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں ، معاشی سرگرمیاں مفقود ہوئیں ، بے روزگاری کے نئے نئے ریکارڈ قائم ہوئے۔اورنامساعد حالات کا یہ بدترین سلسلہ آج بھی ارضِ کشمیر میں شدومد سے جاری ہے۔
امرِواقعہ یہ ہے کہ بے انتہا بربادیوں کے باوجود آج کی تاریخ میں کشمیر میں امن جاگتے کا سپنا ہے۔ کوئی کشمیری یقین اور وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اگلا لمحہ اُس کی زندگی میں کس عنوان سے نیا بھونچال ثابت ہوگا ، کون سی نئی بربادیاں اس کی تقدیر میں رقم ہوں گی اور انسانی حقوق کی کثیرالاطراف پامالیاں کس کس مہیب شکل میں سامنے آئیں گی؟ اسی سلسلے کی ایک کڑی ماڈل ٹاؤن سوپور کا وہ بدترین المیہ ہے جو شمالی کشمیر کے ہنگامہ خیز قصبہ سوپور میں وقوع پذیر ہوا ۔ قبل ازیں جنوبی کشمیر کے قصبہ بجبہاڑہ میں پیش آئے المیے میں بھی ایک آٹھ سالہ بچہ کام آیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر میں امن اور انصاف کا سورج طلوع ہونا آخری کشمیری کے زندہ درگور ہونے تک مؤخر رہے گا یا کوئی ایسا ٹھوس لائحہ عمل بھی ترتیب پائے گا، جو امن اورانسانیت کا پرچم بن کر بہشت ارضی میں لہرائے؟
۵؍اگست ۲۰۲۰ءکو بھارتی وزیر داخلہ امیت شا نے ایک طرح سے ’غیرآئینی سرجیکل اسٹرائیک‘ کرکے بھارتی آئین کی دفعہ ۳۷۰، اور دفعہ ۳۵-اے کالعدم کرکے جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کرنے کا تو اعلان کیا، مگر اس سے بھارت کو یا کشمیری عوام کو کیا حاصل ہوا؟ اس کا کوئی خاطرخواہ جواب آج ایک برس گزرنے کے باوجود بھارتی حکومت کو سوجھ نہیں رہا ہے۔ خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے علاوہ ریاست کو تقسیم کرکے لداخ کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنایا گیا اور بقیہ خطے، یعنی جموں اور کشمیرکو بھی براہِ راست نئی دہلی کے انتظام میں دیا گیا۔
اب پورے ایک سال کے بعد اس غیرآئینی حملے کی افادیت اور ’کامیابیوں‘ کی جو دستاویز بھارتی حکومت نے جاری کی ہے، اس کے مطابق ’’کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کے نتیجے میں حوائج ضروریہ کے لیے باہر نکلنے پر پابندی میں سو فی صد کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس طرح ایک سال کے دوران سو فی صد اوپن ڈیفی کیشن فری بنایا گیا ہے۔
۵؍اگست کو اٹھائے گئے اقدامات کا مقصد کشمیر میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانا ، سڑکوں کو سونے سے مزین کرنا اور بھارت کے تئیں عوام میں نرم گوشہ پیدا کروانا بتایا گیا تھا، مگر مودی حکومت کے مذکورہ اوّلین اور شرمناک ’کارنامے‘ پر تبصرہ کرتے ہوئے سینیر صحافی شاستری راما چندرن کا کہنا ہے: جب خطے میں ہر روز فوجی مقابلوں میں لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، تو رفع حاجت کے لیے کون باہر نکلے گا؟ اس کے علاوہ جو باہر آنا بھی چاہتے ہیں، ان پر تشدد کرکے ایسی حالت کر دی گئی ہے ، کہ وہ رفع حاجت کے قابل ہی نہیں رہ گئے اور جب سال بھر لاک ڈاؤن میں رہنے کے بعد پیٹ خالی ہو ، تو رفع حاجت کیسے ہو؟
شاید مودی یا امیت شا کو دہلی سے کولکتہ تک ریل گاڑی میں سفر کرنا کبھی نصیب نہیں ہوا۔ رات دہلی سے جب ٹرین چل کرعلی الصبح پٹنہ یا بہار کے دوسرے شہر گیا پہنچتی ہے ، تو اسٹیشن سے متصل اور دیگر علاقوں میں نظارہ نہایت قابلِ نفرت ہوتا ہے ۔سخت گرمی کے باوجود مسافر فوراً کواڑ گرا لیتے ہیں۔ کیونکہ لمبی لائن میں ایک خلقت پٹڑی پر پانی کا لوٹا لیے مصروف دکھائی دیتی ہے، اور آپس میں ملکی و غیر ملکی حالات پر تبادلہ خیالات بھی کرتی نظر آتی ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ امیت شا کشمیر میں تعینات پوری نو لاکھ فوج کو بہار بھیج کر اس کو اوپن ڈیفی کیشن فری بناکر، ریلوے پٹریوں کو غلاظت سے بچنے کا موقع فراہم کرواتے۔
گذشتہ ایک سال سے کشمیریوں نے بھی مودی حکومت کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا ہے۔ جب اس ’غیرآئینی اسٹرائیک‘ سے کشمیریوں کے جسم سے ان کے کپڑے چھین لیے گئے، تو کشمیر کے ایک لیڈر شاہ فیصل کے مطابق مودی حکومت کو یقین تھا کہ اس کے خلاف عوامی بغاوت برپا ہوگی اور اس کے نتیجے میں ۱۰ہزار افراد ہلاک کرکے تحریک کو کچل دیا جائے گا۔ مگر کشمیریوں کی پُراسرار خامشی اور لیڈر شپ کی عدم موجودگی کے باوجود عام آدمی کی سوچ اور ردعمل دیکھ کر نئی دہلی میں اربابِ اقتدار کا کلیجہ منہ کو آرہا ہے۔ ان کو یقین تھا کہ کچھ عرصہ تک سوگ و ماتم کی کیفیت کے بعد حالات معمول پر آجائیں گے۔ مگر بھارت نواز نیشنل کانفرنس اور پیپلز کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی صدمے کی کیفیت سے باہر نہیں آرہے ہیں۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کی کس منہ سے اپنے ووٹروں کا سامنا کریں۔
بھارت نے جب اگست میں کشمیر میں تاریخ کے طویل ترین لاک ڈاؤن نافذ کیا تو، لوگ لقمے لقمے کے محتاج ہونے لگے۔ دنیا نے زبانی ہمدردی کے سوا کچھ نہیں کیا، تو ہر کشمیری کے زبان پر تھا کہ یااللہ! اس لاک ڈاؤن کا مزا ساری دُنیا کو بھی چکھا دے۔ جنوری ۲۰۲۰ء میں جب بھارت میں مقیم یورپی یونین کے سفیروں کی ایک ٹیم کو کشمیر لے جایا گیا، تو ان کو کوّر کرنے کے لیے اکنامک ٹائمزکے معروف صحافی اروند مشرا بھی سرینگر پہنچ گئے تھے۔ وہ سیکورٹی حصار میں تھے۔ انھوں نے افسران سے اپنے ایک ساتھی بلال احمدڈارکے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ بلال ماس کمیونی کیشن کی تعلیم کے دوران ان کا ہم جماعت تھا۔ مشرا کا کہنا ہے کہ جب وہ بلال کے گھر کی گلی سے گزر رہا تھا کہ کھڑکی سے ایک خاتون کی آواز آئی:’’اروند بھائی، آپ بلال کے دوست ہو دلی والے، میں نفیسہ عمر ہوں،بلال کی پھوپھی کی بیٹی‘‘۔ مشرا کا بیان ہے کہ نفیسہ کی باتیں سن کر وہ کئی رات سو نہ سکا۔ اس لڑکی نے پوچھا: کیا باہر کی دنیا میں کسی کو اندازہ ہے کہ سات مہینے سے جہاںکرفیو ہو، گھرسے نکلنا تو دُور جھانکنا بھی مشکل ہو، چپے چپے پر فوج تعینات ہو،انٹر نیٹ، موبائل، لینڈ لائن فون تک بند ہو، گھروں سے بچے،جوان اور بوڑھے ہزاروں بے قصوروں کی گرفتاریاں ہوئی ہوں، سکول، کالج، دفتر سب بندہوں، کسی نے سوچا کہ آخر لوگ کیسے سانس لیتے ہوںگے؟‘‘
مشرا کے مطابق بس پانچ منٹ میں اس خاتون نے حالا ت کا ایسا نقشہ کھنچا کہ یہ الفاظ دہلی میں کئی ماہ تک میرے ذہن پر دستک دیتے رہے۔ نفیسہ نے مزید کہا کہ: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ـ ’’کیسے لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، بیماروں کا کیا ہو رہا ہے؟ آدھی سے زیادہ آبادی ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں کی شکار ہوچکی ہے،بچے خوف زدہ ہیں،مستقبل اندھیرے میں ہے‘‘۔ـ نفیسہ نے روتے ہوئے کہا کہ ’’ظلم وستم کی انتہا ہے،روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے، پوری دنیا خاموش تماشادیکھ رہی ہے، ہم نے سب سہہ لیا اور خوب سہہ رہے ہیں۔لیکن اس وقت دل تڑپتا ہے جب بھارت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ان کے ساتھ یہی ہوناچاہیے تھا۔ لیکن میں نے ان لوگوں یا کسی کے لیے بھی کبھی بدعا نہیں کی، بس ایک دعا ضرور کی ہے تاکہ پوری دنیاکوہمارا کچھ تو احساس ہو۔ اروند بھائی، آپ دیکھنا میری دعا بہت جلد قبول ہوگی‘‘ ۔
اروند مشرا نے جب دعا کی شکل کے بارے میں پوچھا، تو اس کے بقول نفیسہ نے پھوٹ پھوٹ کرروتے ہوئے کہا: ’’اے اللہ جو ہم پر گزری ہے کسی پر نہ گزرے، بس مولا تو کچھ ایسا کردینا اور اتنا کردیناکہ پوری دنیاکچھ دنوں کے لیے اپنے گھروں میں قید ہوکر رہنے پر مجبور ہوجائے، سب کچھ بندہوجائے ، رُک جائے!شاید دنیا کو یہ احساس ہوسکے کہ ہم کیسے جی رہے ہیں؟‘‘ کورونا وائرس کے بعد جب پوری دنیا لاک ڈاؤن کی زد میں آگئی ، جو ابھی تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے، مشرا کے مطابق نفیسہ کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں: ’’اروند بھائی آپ دیکھنا میری دعا بہت جلد قبول ہوگی‘‘۔
کشمیر کا معاملہ بہت ہی سادہ اور آسان ہے، جس کے مطابق ایک قوم کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کو حق خود ارادیت کا موقع دیا جائے گا اوراُس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اعلان کسی بند کمرے میں نہیں بلکہ اقوام عالم اس کی گواہ ہیں۔ اقوا م متحدہ میں اس سے متعلق ۱۸قراردادیں موجود ہیں۔ پچھلے ۷۳ سال سے ایک قوم چیخ پکار کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنی راے کا اظہار کر رہی ہے۔ حصولِ آزادی کے اظہارکے لیے جس جس طریقے کوبھی استعمال میں لایا جاسکتا ہے کشمیری قوم نے ہر اس طریقے کو آزما یا لیکن ایک خو نخوار ظالم جو بدمستی میں کسی بھی زبان کو سمجھنے سے عاری ہے،وہ صرف مار دھاڑ،ظلم و ستم کرنے کے ہنر سے آشنا ہے۔سیاسی پلیٹ فارم ہویا عوامی احتجاج ، ہڑتال ہو یا عسکری میدان اہالیانِ کشمیر نے ہر میدان میں بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ بھارتی ایوانوں اور دنیا کے نام نہاد امن کے ٹھیکے داروں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ وہ حقیقت سے آشنا ہوں، لیکن بدقسمتی سے اقوام عالم اس سچائی سے ہمیشہ آنکھیں چُراتی نظر آئیں۔ جس سے بھارت کو بھی حوصلہ ملا کہ طاقت کے سہارے کشمیریوں کی امنگوں اور حصولِ آزادی کی خاطر کوششوں کو دبائے۔ بھارتی حدود میں اگر کہیں کوئی بھی اس ظلم وجبر کو عیاں کرنے کی کوشش کرے تو اس کو یا تو پابند سلاسل کیا جاتا ہے یا کسی دوسرے طریقے سے خوف ودہشت کا شکار بنایا جاتا ہے۔
کشمیر کے شب وروز کے احوال کو قلم بند کیا جائے تو ایک ایسا ڈراؤنا خاکہ تیار ہوتاہے، جسے دیکھ کر انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ جدید دور میں کسی بستی کے حال و احوال ہیں۔ مسائل اور چیلنجوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ، ایک قوم کو ایک تیزخونیں سیلابی ریلے کے ساتھ بہائے لیے جارہا ہے۔ وہ قوم ایک بے بس، کمزور اور لاچار انسانوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جس کے تمام اختیارات ایک ظالم کے حوالے ہیں۔اس قوم کے بازاروں ، قصبوں ، گلی کوچوں یہاں تک کہ خلوت گاہوں تک پر اُسی کا قبضہ ہے۔ وہ جب چاہے اس کے کھیت جلادے ، جب چاہے اس کے گھر بارود سے برباد کردے یا انسانی زندگی ہی کا خاتمہ کر ڈالے۔ یہ سب اس کی مرضی پر منحصر ہے کیونکہ وہ کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں ہے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد نہ وہ دہشت گرد کہلاتا ہے اور نہ مجرموں اور ڈاکوؤں ہی کی فہرست میں شمار کیا جاتاہے۔
اس سب ظلم وتشدد کے مارے انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ قابل بیان نہیں بلکہ اس کا انجام یہی نظر آتا ہے کہ وہ گُھٹ گُھٹ کے اپنے آنسو پی جانے کے ہنر سے آشنا ہو۔ بنیادی طور پر جن حالات سے اُسے ہر روز سابقہ پیش آتا ہے، وہ اُس میں یہ صلاحیت پیدا کرنے کا تقاضا کرتے ہیں کہ اُسے کسی کا مرنا، کسی کے ساتھ ظلم ،کسی بے کس کی آہ وفغان ، کسی معصوم کی سسکیاں اور خود اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و جبر، اُس کے اعصاب کو متاثر نہ کرسکیں، اُسے جذباتی نہ بناسکیں اور اُس میں کسی طرح کا ہیجان پیدا نہ کریں۔ اگر اُس میں یہ تمام’ صلاحیتیں‘ پیدا ہوجائیں تو عین ممکن ہے کہ ایسا انسان کشمیر میں اچھی طرح سے زندگی گزار سکتا ہے اور یہ بھی اسی وقت تک ہے، جب کہ وہ خود اس تصادم کی نذر ہوکر جان نہ کھو دے۔ اگر بات کو مزید وضاحت سے بیان کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ ایک ’عام انسان‘ ایسے ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس میں ’بے حسی‘ کی ایسی ’صلاحیت‘ پیدا نہ ہو کہ والد ہونے کے ناطے وہ’ اپنے عزیز ترین بیٹے کے ساتھ بازار جائے اور وہاں سے اپنے بیٹے کی لاش اپنے ہاتھوں میں اُٹھا کر چپ چاپ لے آئے‘۔ اور بچہ ہونے کی صورت میں ’اس معصوم میں یہ’صلاحیت‘ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بزرگ والد کی چھلنی لاش کو دیکھ کر دل برداشتہ نہ ہو۔ وہ آہ تک نہ کرے اور اپنے آنسو پی جانے کے ہنر سے آشنا ہو۔ وہ گولیوں کی بوچھاڑ میں ذرا بھی نہ ڈرے اور اپنے دل کو دلاسہ دینے کے لیے کافی ہو۔
بھارتی حکومت اپنی ریاستی دہشت گردی کو ’مذہبی جنگ‘ کا رنگ دینا چاہتی ہے، تاکہ وہ عالمی سطح پر اس تمام صورت حال کا جواز پیش کر سکے۔تائید حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حدتک کے جرم کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے: آصفہ جان کا تعلق کٹھوہ کے بکروال خاندان سے تھا۔ آٹھ سالہ معصوم بچی کومندر کے تہہ خانے میں لے جاکر چارروز تک مسلسل جنسی زیادتی کا شکار بنایا گیا اور اس کے بعد پتھر مار مار کر جاں بحق کر دی گئی۔ اس درندگی کا ارتکاب کرنے والوں کے حق میں ’ہندو ایکتا منچ ‘ نامی تنظیم نے ترنگا بردار جلوس نکالے، جس کی پشت پناہی بی جے پی کر رہی تھی۔
اگر چہ اہل کشمیر ایک عرصے سے انھی حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور بے مثال قربانیوں کے سہارے تحریکِ مزاحمت کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ہرآنے والے دن کے ساتھ ظلم و تشدد میں ریکاڑ توڑ اضافہ ہو رہا ہے۔اس خوف و دہشت میں جہاں ایک فرد کی ہر چیز داؤ پر لگی ہوئی ہو، اس کے لیے ان حالات میں آزادی کی بات کرنا آسان کام نہیں ہے۔لیکن حصولِ آزادی کی تڑپ ہر کشمیری کے لیے اُس بچھڑے ہوئے بچے کی مانند ہے، جو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہر مشکل کو عبور کرنے کے لیے تیار ہو۔
اگر چہ بھارت میں الیکشن جیتنے کے لیے ’پاکستان سے دشمنی‘ ایک لازمی عنصر کے طور پر استعمال ہورہی ہے، وہیں بھارتی جنتا پارٹی کےمنشور کا یہ ایک حصہ تھا کہ کشمیر کو مکمل طور پر ’ہندو راشٹر‘ میں شامل کرنا۔ پچھلے سات سال سے اسی منشور پر شد ومد سے کام جاری ہے۔ جس کی وجہ سے اہالیانِ کشمیر میں سخت خوف وہراس پھیل چکا ہے اور اپنے مستقبل کے حوالے سے ان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ غیریقینی بڑھتی جارہی ہے۔
۵؍اگست ۲۰۱۹ءکے بعد کشمیر کے حالات میں مزید ابتری دیکھنے میں آئی۔ ہر دین پسند کو مجرم تصور کیا گیا اور ہر دین پسند جماعت کا دائرہ تنگ کیا گیا جس میں جماعت اسلامی سرفہرست ہے کہ اُس کو ممنوعہ جماعت قرار دے کر اس کے وابستگان کو پابند سلاسل کیا گیا۔خوف و ہراس کے سایے پورے جموں و کشمیر کی ریاست پر دراز کیے گئے۔ جموں و کشمیر کے انضمام میں حائل کچھ رکاوٹوں کو ختم کرنے لیے لیے آئینی طور پر دفعہ۳۵ اے اوردفعہ۳۷۰ کو بھی منسوخ کیا گیا۔ اس کے بعد پورے خطے کا راج دہلی حکومت نے پورے طریقے سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اور اب کشمیر کی آبادی کو تبدیل کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔اگر یہی صورت حال جاری رہی تو پھر وہ ہوسکتا ہے جس طرح کہ: ایک وقت میں فلسطین دنیا کا ایک ملک تھا اور آج دنیا کے نقشے میں فلسطین موجود نہیں ہے لیکن اسرائیل دنیا کے ممالک میں شمار کیا جاتاہے۔بھارتی عزائم اسی طرح سے بالکل واضح ہیں کہ وہ کشمیر کو دنیا کے نقشے سے غائب کرنا چاہتے ہیں۔ اس منصوبے پرعمل درآمد کے لیے سابق بھارتی فوجیوں اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں کو کشمیر میں بسانے کا عمل شروع ہوچکا ہے۔
حالات کی اس ابتر صورت حال نے پورے خطے کے رہنے والے افرادکو ایک الجھن میں ڈال دیا ہے۔اگر چہ ایک طرف پہلے ہی مشکلات میں گھرے انسانوں کا زندہ رہنا مشکل ہوچکا تھا، وہیں اب مستقبل کے اس ڈراؤنے منصوبے نے ان کی ذہنی الجھن میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اہلِ کشمیر پہلے اپنی آزادی کی محرومی سے مارے جارہے تھے اور اب اپنے گھر بار اور زمین جایداد سے محروم ہونے جارہے ہیں۔ان المناک حالات نے اگر چہ خطے میں رہنے والے لوگوں کو بھی ’تنگ آمد بجنگ آمد ‘کے مصداق جنگ کے لیے تیار کیا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ خالی ہاتھوں سے بکتر بند گاڑیوں سے نہیں لڑا جاسکتا۔ اس ذہنی تناؤ کی صورت حال نے اہلِ کشمیر کو بے بسی اور مجبوری کی تصویر بنادیا ہے۔ بلاشبہہ ایک انسان کی زندگی میں کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، جن کو حل کرنا اور زندگی کو آگے بڑھانا ایک معمول کا طریقہ ہے، لیکن اہالیانِ کشمیر کی زندگیوں کا سب سے بڑا مسئلہ، مسئلہ کشمیر ہے، جس کو حل کرتے کرتے ان کی تین نسلیں ختم ہوگئی ہیں، لیکن مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے۔
اس ساری صورت حال کے بعد زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام وہ مشورہ کرتا ہے، جو کسی دانش وَر کی زبان سے یوں ادا ہوتا ہے کہ ’’کشمیریوں کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے۔بندوق نہیں آواز بلند کرنی چاہیے، عسکریت نہیں ، عوامی احتجاج کرنا چاہیے‘‘۔ یا کبھی یہ بھی سننے کو ملتاہے کہ ’’یہ جہاد نہیں وطنیت کی جنگ ہے‘‘۔نرم گرم بستر پرآرام فرما کر ایسی باتیں کہی جاسکتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے حضرات بھارت کے سفاکانہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہونے کے باوجودبڑی آسانی سے ایسے مشورے داغ دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ خالی ہاتھوں سے ایک طاقت ور مکار دشمن کا مشکل مقابلہ دیکھنا ہو تو اس کا مشاہدہ ہر روز کشمیر کی سرزمین پردیکھنے کوملتا ہے۔
اگرچہ جموں و کشمیر اور فلسطین کے خطے جغرافیائی اعتبار سے کوسوں دور ہیں، مگر تاریخ کے پہیے نے ان کو ایک دوسرے کے قریب لاکر کھڑا کر دیا ہے۔ دونوں خطے تقریباً ایک ساتھ ۴۸-۱۹۴۷ء میں دنیا کے نقشہ پر متنازعہ علاقوں کے طور پر سامنے آئے ۔کئی جنگوں کے باعث بھی بنے اور پچھلے سات عشروں سے نہ صرف امن عالم کے لیے خطرہ ہیں، بلکہ ان کی محکومی مسلم دنیا کے لیے ناسور بنی ہوئی ہے۔
بھارت نے ۵؍اگست ۲۰۱۹ء کو جس طرح یک طرفہ کارروائی کرکے ریاست جموں و کشمیر کے دو ٹکڑے کرکے اس کی نیم داخلی خود مختاری کو کالعدم کردیا، کچھ اسی طرح اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی یکم جولائی ۲۰۲۰ء کو فلسطین کے مغربی کنارہ کے ۳۰فی صد علاقے کو اسرائیل میں ضم کرنے کا عزم کیے بیٹھے تھے۔ فی الحال انھوں نے اس منصوبے کو التوا میں رکھا ہے، کیوںکہ بھارت کے برعکس اسرائیل میں ان کو فوج ، اپوزیشن اور بیرون ملک آباد یہودیوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ناروے کے شہر اوسلو میں ۱۹۹۳ء اور ۱۹۹۵ء میں اسرائیلی اور فلسطینی قیادت کے درمیان طے پائے گئے سمجھوتے میں، ایک فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیاتھا۔ جس سے ۱۶لاکھ کی آبادی کو دو خطوں مشرق میں غزہ اور اُردن کی سرحد سے متصل مغربی کنارہ میں تقسیم کیا گیا تھا۔ نسبتاً وسیع مغربی کنارے کا انتظام ’الفتح‘ کی قیادت میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن (PLO) کے پاس ہے، وہیں غزہ میں اسلامک گروپ حماس بر سرِ اقتدار ہے۔
جس طرح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ۲۰۱۴ء اور۲۰۱۹ءکے انتخابات میں کشمیر کی آئینی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے اور علیحدہ شہریت کا قانون ختم کرنے کے نام پر ہندو قوم پرستوں کو لام بند کرکے ووٹ بٹورے، بالکل اسی طرح اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے بھی یہودی انتہاپسند طبقے کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فلسطینی علاقوں کو ضم کرنے کا شوشہ چھوڑا۔ جس علاقے کو وہ اسرائیل میں ضم کروانا چاہتے ہیں، وہاں ۶۵ہزار فلسطینی اور ۱۱ہزار یہودی آباد ہیں۔ ’اوسلو معاہدے‘ کی رُو سے مغربی کنارے کو تین حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ ایریا سی میں مغربی کنارے کا ۶۰فی صد علاقہ آتا ہے۔ اس میں تین لاکھ فلسطینی آباد ہیں اور یہی علاقہ اسرائیل کی نظروں میں کھٹکتا ہے۔
اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے اس جوئے کا مثبت پہلو یہ نکلاہے کہ اسرائیلی سیاست میں فلسطین کو ایک بار پھر مرکزیت حاصل ہوئی ہے۔ عرصے سے اسرائیلی سیاسی جماعتیں مسئلۂ فلسطین پر بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھیں۔ بھارت کی کشمیر پر یلغار کے برعکس نیتن یاہو کے پلان پر اسرائیل کے اندر خاصی مزاحمت ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ مزاحمت تو اسرائیلی فوج کی طرف سے ہے۔ گذشتہ دنوں ۲۷۰سابق فوجی جرنیلوں، بشمول اسرائیلی خفیہ اداروں، موساد، شین بیٹ کے افسرا ن نے ایک مشترکہ خط میں نیتن یاہو کو اس پلان سے باز رہنے کی تلقین کی۔ ان کو خدشہ ہے کہ اس قدم سے کہیں محمود عباس کی زیر قیادت فلسطینی اتھارٹی تحلیل نہ ہوجائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو فوج کا ایک بڑا حصہ اس کو کنٹرول کرنے میں مصروف رہے گا، اور یوں زیادہ تر وقت امن و امان کی بحالی کے لیے ڈیوٹیاں دینے سے اس کی جنگی کارکردگی متاثر ہوگی۔
اہم باخبر ذرائع نے راقم کو بتایا کہ اس حوالے سے امریکی انتظامیہ میں بھی گھمسان کا رَن پڑا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے داماد ااور مشیر جیرالڈ کوشنر اور اسرائیل میں امریکی سفیر ڈیوڈ فریڈمین کے درمیان اس مسئلے پر خاصے اختلافات پیدا ہوگئے ہیں۔ کوشنر جس نے ٹرمپ کا مڈل ایسٹ پلان، یعنی ’ڈیل آف دی سنچری‘ ترتیب دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے فلسطینی علاقوں کو ضم کرنے کے فیصلے سے امریکی پلان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
اس سال جنوری میں جب صدر ٹرمپ ، نیتن یاہو کی معیت میں وائٹ ہاؤس میں اپنے پلان کو ریلیز کر رہے تھے، تو یہی مطلب لیا گیا تھا کہ اس پلان کو عرب ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ حال ہی میں امریکا کی طاقت ور یہودی لابی نے اپنا ایک اعلیٰ سطحی وفد ان ممالک کے دورے پر بھیجا تھا، جہاں ان کو واضح طور پر بتایا گیا کہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کے پلان کے بعد وہ ٹرمپ کے پلان کی حمایت نہیں کر سکیں گے۔ انھی ذرائع نے راقم کو بتایا کہ کوشنر فی الحال خلیجی ممالک کی ناراضی مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ حال ہی میں امریکا میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف ال عتیبہ کا ایک مضمون اسرائیل کے ایک کثیر الاشاعت عبرانی روزنامے میں شائع ہوا، جس کی سرخی ہی یہ تھی کہ ’’تعلقات کو معمول پر لانے اور فلسطینی علاقوں کو ضم کرنے کی پالیسی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی ‘‘۔مگر امریکی سفیر فریڈمین کے مطابق یہ عرب ممالک کی وقتی اُچھل کود ہے اور خطّے میں اپنی اقتصادیات اور سلامتی کے لیے ان کو اسرائیل کی اشدضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل ، جہاں کبھی پانی اور تیل کا فقدان ہوا کرتا تھا، اب خطے میں عرب ممالک کو پیچھے چھوڑ کر انرجی کا مرکز بننے والا ہے۔ پینے کے پانی کے لیے اردن کا اسرائیل پر انحصار ہے ۔ اس وقت مصر کو اسرائیل سے ۸۵لین کیوبک میٹر گیس فراہم ہورہی ہے، جس سے اسرائیل سالانہ۵؍ارب اور ۱۹کروڑ ڈالر کماتا ہے۔ فریڈ مین نے باور کرایا ہے کہ اگر ٹرمپ امریکی صدارتی انتخابات میں شکست سے دوچار ہوجاتے ہیں، تو ڈیموکریٹس کسی بھی صورت میں فلسطینی علاقوں کو ضم کرنے کے پلان کی حمایت نہیں کریں گے۔
دنیا بھر میں رہنے والے یہودی تارکین وطن ، جو ایک طرح سے اسرائیل کے بطورِ بازو کام کرتے ہیں، نیتن یاہو کے اس پلان میں خطرات دیکھتے ہیں۔ اسرائیل میں جہاں اس وقت ۶۷ لاکھ یہودی رہتے ہیں، وہاں ۵۴ لاکھ امریکا کے شہری ہیں۔ یہودی تارکین وطن امریکا میں ڈیموکریٹس اور یورپی ممالک کے رد عمل سے خائف ہیں۔ کئی یورپی ممالک نے فلسطینی علاقوں کو ضم کرنے کی صورت میں اسرائیل کے خلاف پابندیا ں لگانے کی دھمکی دی ہے اور کئی یورپی پارلیمنٹوں نے اس کی منظوری بھی دی ہے۔ چونکہ ’اوسلو معاہدے‘ کے پیچھے پورپی ممالک کی کاوشیں کار فرما تھیں اور اس میں دو ریاستی فارمولا کو تسلیم کیا گیا تھا، اس لیے یورپی ممالک اس کو دفن ہونا نہیں دینا چاہتے ہیں۔ تاہم، اسرائیل کو یقین ہے کہ یورپی ممالک شاید ہی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا پاسکیں گے۔ اس صورت میں ان کوبراہِ راست امریکا سے ٹکر لینی پڑے گی۔ امریکا کی ۲۷ریاستوں نے ایسے قوانین پاس کیے ہیں، جن کی رُو سے اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ کی مہم چلانے والے اداروںو ممالک کے خلاف کارروائی ہوسکتی ہے۔ نیتن یاہو کے انتخابی حریف ریڈ اینڈ وائٹ پارٹی کے قائد بنی غانز جو اَب اقتدار میں ان کے حلیف ہیں، فلسطینی علاقوں کو ضم کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ حکومت بناتے وقت طے پائے گئے معاہدے کی رُو سے نیتن یاہو کو اگلے سال وزیر اعظم کی کرسی بنی غانز کے لیے خالی کرنی پڑے گی۔
جس طرح انتہا پسند ہندوں کو مودی کی شکل میں اپنا نجات دہندہ نظر آتا ہے ، اسی طرح انتہا پسندوں یہودیوں کے لیے بھی نیتن یاہو ایک عطیہ ہیں۔ فلسطینی علاقوں کو ضم کرنے کے پلان پر بات چیت کرنے کے لیے حال ہی میں جب ایک امریکی یہودی وفد نیتن یاہو سے ملاقات کرنے ان کے دفتر پہنچا، اور اس کے مضمرات پر ان کو آگاہ کروا رہا تھا، تو انھوں نے اپنے میز کی دراز سے ایک منقش بکس نکالا ۔ اس میں۵۰۰ قبل مسیح زمانے کا ایک سکہ تھا، جو ان کے بقول مسجد اقصیٰ سے متصل کھدائی کے دوران اسرائیلی محکمہ آثار قدیمہ کو ملا ہے اور اس پر عبرانی میں نیتن یاہو کھدا ہو ا تھا۔ اس سے انھوں نے یہ فال نکالی ہے کہ یہودیوں کو اعلیٰ مقام دلوانے اور اسرائیل کو مضبوط و مستحکم کروانے کی ذمہ داری ان پر خدا کی طرف سے عائد کی گئی ہے۔ مگر اسرائیل میں احتسابی عمل شاید بھارت سے زیادہ مضبوط ہے اور وہاں اپوزیشن اور دیگر ادارے حکومت کے ساتھ ٹکر لینے کی پوزیشن میں ہیں۔
اس کے علاوہ تمام تر جارحانہ کارروائیوں کے باوجود یہودیوںکو ادراک تو ہوگیا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر نہیں ہیں۔ اس کا اندازہ تو ۱۹۷۳ءکی جنگ مصر کے وقت ہو گیا تھا،مگر ۲۰۰۶ء میں جنگ لبنان اور ۲۰۱۴ء میں غزہ کی جنگ کے بعد یہ بات اور شدت کے ساتھ محسوس کی جارہی ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے یہودی اور اسرائیل کے مقتدر طبقے چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تاریخ کا پہیہ کوئی اور رخ اختیار کرے، اسرائیل کی سرحدوں کا تعین کرکے، پڑوسی ممالک سے اس کا وجود تسلیم کرایا جائے۔ اسرائیل کی فوج اور دنیا بھر کے یہودیوں نے جس طرح نیتن یاہو کے پلان کے مضمرات کا ایک معروضی انداز میں جائزہ لیا ہے، وہ بھارت کے لیے بھی ایک سبق ہے، جہاں کے اداروں کے لیے کشمیر ی عوام کے حقوق سلب کرنا اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کو حب الوطنی ا ور بھارتی نیشنلزم ثابت کرنے کاپہلا اور آخری ذریعہ بنا ہوا ہے۔
جموں و کشمیرکے مسلمانوں کی غلامی کو مضبوط کرنے میں کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ کا بھی اہم کردار تھا، جنھوں نے ریاست جموں و کشمیر کے مسلمانوں کا مستقبل، پنڈت جواہر لال نہرو اور انڈین نیشنل کانگریس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس ’خدمت‘ کے صلے میں کبھی اقتدار میں رہے اور کبھی اقتدار سے بے دخل ہوئے۔ وہی نہیں، پھر ان کی دوسری اور تیسری نسل بھی برابر اسی کھیل کا حصہ رہی۔ تاہم، اب شیخ عبداللہ صاحب کے بیٹے ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی کہہ اُٹھے ہیں کہ ’’ہم نے کانگریس پر اعتبار کرکے غلطی کی تھی‘‘۔ یہاں شیخ عبداللہ کی خود نوشت آتش چنار سے یہ عبرت آموز حصہ پیش کیا جارہا ہے۔ اس عبرت نامےمیں اُن لوگوں کے سوچنے سمجھنے کا سامان موجود ہے، جو ہندو لیڈروں کی ذہنیت کو سمجھنے کے بجاے، اس صورتِ حال کو چند مسلمانوں کا واہمہ قراردیتے ہیں۔ (ادارہ)
۱۹۳۵ء میں جناب محمد علی جناح سرینگر سیروتفریح کے لیے تشریف لائے، تو وہ ایک ہندستان گیر شخصیت کے مالک بن چکے تھے، اور اُن کے سیاسی امتیاز کے ساتھ اُن کی قانون دانی کا لوہا بھی سبھی مان چکے تھے۔ وہ شیوپورہ میں ایک ہاؤس بوٹ میں مقیم تھے۔ اُنھی دنوں چیف جسٹس سربرجور دلال کی عدالت میں ایک مقدمہ، متنازعہ نکاح سے متعلق زیرسماعت تھا۔ مقدمہ کافی مشکل تھا۔ مَیں اور مرزا محمدافضل بیگ، جناح صاحب سے اُن کے ہاؤس بوٹ میں ملے، تاکہ اُنھیں اس مقدمے کا وکالت نامہ لینے پر مائل کرسکیں۔ یہ میری جناح صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔
اُسی زمانے میں عید میلاد النبیؐ کا جلسہ شاہی مسجد میں ہونے والا تھا۔ ہم نے اُنھیں ایک نشست کی صدارت پیش کی، جو اُنھوں نے قبول فرمائی، اور صدارتی تقریر انگریزی زبان میں فرمائی۔ جناح صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ’’ریاست [جموں و کشمیر] میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت کی وجہ سے مسلمانوں کے لیڈروں کا فرض ہے کہ وہ نہ صرف غیرمسلموں کی تالیف ِ قلوب کریں بلکہ ان کو سیاسی گاڑی کا ایک پہیہ سمجھ کر اپنے ساتھ چلائیں‘‘۔ اُدھر ہندستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی روزبروز بڑھتی جارہی تھی اور جناح، مسلمانوں کو [ہندوؤں سے] برگشتہ خاطر کرنے میں کامیاب ہورہے تھے۔ ۱۹۳۵ء میں برٹش انڈیا ایکٹ کے تحت جو انتخابات مختلف صوبوں میں ہوئے، اس میں بھی مسلم لیگ نے پہلی بار قابلِ لحاظ کامیابی حاصل کی تھی۔ صوبہ جات متحدہ آگرہ واودھ، یعنی یوپی میں مسلم لیگ اور کانگریس کےدرمیان ایک انتخابی سمجھوتا ہوا تھا۔ جب نتیجہ ظاہر ہوا تو کانگریس نے ایک بڑی اکثریت کے ساتھ انتخابات جیت لیے۔ اس لیے اُس کو حکومت بنانے کے لیے دوسری جماعتوں کے تعاون حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اپنی کامیابی کے زعم میں کانگریس نے وزارت میں مسلم لیگ کے شامل ہونے پر کڑی شرطیں عائد کیں، جن کے ماننے سے مسلم لیگ نے انکار کیا، اور وزارت میں شامل نہ ہوئی۔ اگر کانگریس فراخ دلی اور تدبر سے کام لیتی تو شاید آج ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن جواہر لال کی بے جا ضد کی وجہ سے ایسا نہ ہوسکا۔
مسلم لیگی لیڈروں کو کانگریس پرکوئی بھروسا نہ رہا۔ چنانچہ ہندو مسلم تلخی اور بڑھ گئی۔ ہندستان میں سیاسی سرگرمیاں تیز سے تیز تر ہونے لگیں۔ عام مسلمانوں کا رجحان واضح طور پر مسلم لیگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔
ہم کشمیر میں ’فرقہ وارانہ سیاست‘ کے اس دور کو خیرباد کہہ چکے تھے۔ اگرچہ جموں کے چودھری غلام عباس نے مسلم کانفرنس کی احیاے نو کا بیڑا اُٹھایا۔ غالباً اُنھوں نے ہی حیدرآباد کے مشہور سیاسی رہنما [نواب] بہادر یارجنگ کو کشمیر آکر مسلم کانفرنس کے اجلاس سے خطاب کرنے کی دعوت دی۔ نواب صاحب اُردو زبان کے ایک انتہائی طاقت ور خطیب تھے اور حیدرآباد کی ’مجلس اتحاد المسلمین‘ کے سربراہ۔ وہ کشمیر تو پہنچ گئے، لیکن جب وہ مسلم کانفرنس کے اجلاس سے خطاب کرنے والے تھے تو حکومت نے اُنھیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کشمیر چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اُنھیں تعمیل کرتے ہی بنی۔ یہ صورت ہرگز پسندیدہ نہ تھی اور ہم کسی طرح اِس کے روادار نہیں تھے، لیکن بہادر یارصاحب نے اس کارروائی کا سارا الزام مجھ پر عائد کر دیا۔حالانکہ ہمیں اس معاملے سے دورکا سروکار بھی نہیں تھا۔ بہرحال، کچھ اُن بیانات کی وجہ سے، جو مَیں مسلم لیگ کی سیاست کے خلاف دیتا رہتا تھا، مسلم لیگ اور نیشنل کانفرنس کے درمیان غلط فہمیوں کی خلیج وسیع ہوتی جارہی تھی۔ میری ہرگز یہ مرضی نہیں تھی کہ [ہماری] جماعتوں کے درمیان آویزش کا ماحول قائم ہو۔ میں نے اسی مقصد سے جناح صاحب کے نام ایک خیرسگالی کا مکتوب روانہ کیا تھا۔ جناح صاحب نے اس کے جواب میں مجھےدہلی آنے اور ملاقات کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ میں اُن سے ملنے کے لیے دہلی گیا۔ اس وقت بخشی غلام محمد بھی میرے ساتھ تھے۔جناح صاحب نے ہمیں شرفِ ملاقات بخشا اور یہ ملاقات دوگھنٹے تک جاری رہی۔ اُن دنوں وہ اپنی قیام گاہ اورنگ زیب روڈ میں مقیم تھے۔
میں نے جناح صاحب کے سامنے تحریک ِ کشمیر کی تفصیل بیان کی، اور عرض کی کہ ’’ریاست جموں و کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے، جس میں ۸۵ فی صد مسلمان رہتے ہیں۔ بنابریں معاملات کے متعلق اُن کا نظریہ ایک اکثریت کا ہی ہوسکتا ہے، اقلیت کا نہیں‘‘۔
دوسری بات میں نے یہ کہی کہ ’’تجربے نے ہم پر یہ ثابت کردیا ہے کہ بنیادی مسئلہ مختلف مذاہب کی ٹکر کا نہیں ہے بلکہ سماج میں مختلف طبقوں کی اقتصادی نابرابری ہے۔ ایک طرف استحصال کرنے والے ہیں اور دوسری طرف وہ جن کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری لڑائی شخصیات سے نہیں بلکہ ایک نظام سے ہے۔ اس میں ہندو اور مسلمان کی تمیز کرنا کوتاہ اندیشی ہوگی۔ جن اصلاحات کا ہم کشمیر میں مطالبہ کر رہے ہیں، اُن سے سب مذاہب کے پیرو مستفید ہوں گے۔ اس لیے یہ مقاصد ایک مشترکہ جدوجہد سے ہی پورے ہوسکتے ہیں‘‘۔
میں نے اُن سے یہ بھی کہا کہ ’’اگر صرف مذہب کی بنیاد پر ہندستان میں مملکتوں کی بنیاد ڈالنا قبول کیا جائے [گا] تو ہندستان ٹکڑے ٹکڑے ہوکر رہ جائے گا‘‘۔ اور عرض کی: ’’ہندستان کی مسلم اقلیت کم از کم تین حصوں میں بٹ جائے گی اور اس کی آواز کی تاثیر گم ہوکر رہ جائے گی‘‘۔
جناح صاحب میری باتیں سنتے رہے۔ اُن کے چہرے کے اُتارچڑھاؤ سے لگتا تھا کہ وہ اُن باتوں سے خوش نہیں ہوئے، لیکن حق یہ ہے کہ اُنھوں نے کمالِ صبر سے میری ساری گفتگو سنی اور آخرکار ایک مر د بزرگ کی طرح فہمایش کے انداز میں کہنے لگے:
میں نے اپنے بال سفید کیے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ ہندو پراعتبارنہیں کیا جاسکتا۔ یہ کبھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے۔ میں نے زندگی بھر اُن کو اپنانے کی کوشش کی۔ لیکن مجھے اُن کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہوسکی ۔ وقت آئے گا، جب آپ کومیری بات یاد آئے گی اور آپ افسوس کریں گے۔
جناح صاحب نے مزید کہا:
آپ ایک ایسی قوم پر کیسے اعتبار کرسکتے ہیں، جو آپ کےہاتھوں سے پانی پینا تک پاپ سمجھتی رہی ہے۔ اُن کے سماج میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہ آپ کو ملیچھ سمجھتے ہیں۔
اُنھوںنے اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا کہ’’ایک بار بمبئی میں مَیں اپنی بیوی کے ساتھ میز پردوپہر کا کھانا کھارہا تھا کہ نوکر ایک ملاقاتی کا کارڈ اندر لایا۔ یہ مشہور ہندو لیڈر پنڈت مدن موہن مالوی کا تھا۔ میں کھانے کی میز سے اُٹھ کر گیا اور انھیں اندر لے آیا۔ جب وہ میز پر بیٹھ گئے تو میں نے اُنھیں کھانے میں شمولیت کی دعوت دی۔ مالوی جی نے یہ کہہ کر انکار کیا ’’آپ جانتے ہیں کہ میں مذہبی وجوہ کی بناپر آپ کے ساتھ ایک میز پر کھانا نہیں کھاسکتا‘‘۔ جناح صاحب بولے کہ میں نے جواب دیا:’’ آپ ساتھ ہی دوسری میز لگا کر کچھ کھایئے‘‘۔ مگر مالوی جی نے کہا: ’’یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیوںکہ نیچے مشترکہ قالین بچھی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے چھوت آسکتی ہے‘‘۔ جناح صاحب نےکہا کہ اس پر میں نے قالین ہٹوا دیا اور مالوی جی کی خدمت میں میوے اور دودھ پیش کیا‘‘۔ جناح صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ’’جس قوم کے برگزیدہ لیڈروں کا یہ حال ہو، وہ آپ کو کیسے جینے دیں گے؟‘‘(آتش چنار، ص ۳۰۴-۳۱۰)
مارچ ۲۰۲۰ء میں وزیراعظم پاکستان کے ہاتھوں ’یکساں قومی نصاب‘ کی منظوری کے اب چار ماہ بعد ’نیشنل کریکولم کونسل‘ (NCC) سے منظوری کا ڈراما رچانے کے لیے۲۲جولائی کو اسلام آباد میں اجلاس منعقد کیا گیا۔ کہا یہ گیا کہ درمیانی عرصے میں نصاب کی نوک پلک سنواری جاتی رہی ہے۔ اس سے پہلے ۱۶ جولائی کو بقول وزارتِ وفاقی تعلیم ماہرین کا اجلاس بلایا گیا جس میں میڈیم آف انسٹرکشن، یعنی ذریعۂ تعلیم کا فیصلہ لینا تھا۔ وفاقی وزارتِ تعلیم نے اس مقصد کے لیے جو نقشۂ کار دیا وہ یہ تھا کہ پری اسکول (قبل اسکول) سے ہی ذریعۂ تعلیم انگریزی ہوگا، تاہم اسلامیات کا مضمون اُردو میں پڑھایا جائے گا۔ نیز اسلامیات کے سوا باقی تمام مضامین کی درسی کتب بھی انگریزی میں ہوں گی۔
۱۶مارچ کے اجلاس میں ۲۷ شرکانے انگریزی بطور ذریعۂ تعلیم کی مخالفت کی صرف بیکن ہاؤس اسکولز کے نمایندے اور جناب جاوید جبار نے انگریزی بطور ذریعۂ تعلیم کی حمایت کی۔ غالب اکثریت کی مخالف راےآنے کی وجہ سے ذمہ داران نے کوئی فیصلہ کیے بغیر اجلاس یہ کہتے ہوئے ختم کردیا کہ اس مقصد کے لیے مزید مشاورتی اجلاس بلائے جائیں گے۔ لیکن مزید کوئی اجلاس بلانے کے بجاے ۲۲ جولائی کو’یکساں قومی نصاب‘ کی ’قومی نصابی کونسل‘ (NCC) کا ذریعۂ تعلیم کے فیصلے کے لیے اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں ۲۵ لوگ ذاتی طور پر اجلاس میں شریک ہوئے اور باقی اراکین آن لائن سہولت کے ساتھ اجلاس میں شامل تھے۔
اس اجلاس کے حوالے سے وفاقی وزارتِ تعلیم نے یہ چالاکی دکھائی کہ وفاق ہاے مدارس دینیہ کے نمایندوں کو بہت تاخیر سے اطلاع دی گئی۔ انھیں نہ کوئی ایجنڈا بھیجا گیا اور نہ اجلاس کاکوئی ورکنگ پیپر۔مزید یہ کہ آن لائن زوم کے ذریعے شرکت کے لیے بعض اراکین کو لنک بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ لیکن دینی اداروں کے تمام نمایندوں نے لنک کی معلومات حاصل کرکے اجلاس میں شرکت ممکن بنالی۔۲۲ جولائی کے اجلاس میں بھی دل چسپ صورتِ حال رہی۔ مفتی منیب الرحمٰن صاحب نے احتجاج ریکارڈ کرایا کہ انھیں نہ بروقت اطلاع دی گئی، نہ ایجنڈا فراہم کیا گیا اور نہ زیرغور نصاب کا مسودہ دیا گیا۔ اس لیے وہ بے مقصد شرکت پسند نہیں کرتے ، لہٰذا انھیں نصابی مسودات فراہم کیے جائیں اور جائزے کے لیے ایک ماہ دیاجائے تو وہ نصاب پر غور کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اجلاس سے الگ ہوگئے، جب کہ مولانا حنیف جالندھری صاحب، علامہ افضل حیدر صاحب اور ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب نے بھرپور استدلال سے شرکت کی اور شکوہ بیان کیا۔
باقی شرکا میں سے سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیرکے وزراے تعلیم یا سیکرٹری تعلیم نے کہا کہ اٹھارھویں آئینی ترمیم کے بعد نصاب سازی صوبوں کااختیار ہے۔ تاہم، وفاق کے اچھے کام کو وہ زیرغور لاسکتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ صوبے کی کابینہ نے کرنا ہے۔ نیز صوبے اپنا نصاب اور درسی کتب تیار کررہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیرتعلیم نے کہاکہ وفاق مہربانی کرکے اپنے نصاب میں کشمیر کا بھی کہیں ذکر کردے تو اس کی مہربانی ہوگی۔خیبرپختونخوا کے وزیرتعلیم نے کہا کہ ہمیں توبتایا گیا تھاکہ نصاب کی منظوری کا یہ آخری اجلاس ہے لیکن شرکاے اجلاس کی تنقیدی آرا سننے کے بعد معلوم ہورہا ہے کہ یکساں قومی نصاب کے سلسلے میں یہ تو ابھی پہلا اجلاس ہے۔
شرکاے اجلاس میں سے اکثریت اگرچہ سیکولر، لبرل خیالات کی حامی اور وفاقی وزیرتعلیم کی پسندیدہ شخصیات تھیں لیکن ان کے تبصرے بھی کام کے حق میں نظر نہیں آرہے تھے۔ وفاقی وزیرتعلیم جناب شفقت محمودکا کہنا یہ تھا کہ ہم نیشنل کریکولم کونسل کے اراکین کی راے اور تبصروں کی روشنی میں نصاب کی ٹیوننگ اور پالشنگ کریں گے۔ نتیجہ یہ کہ پھر ۱۶جولائی والے اجلاس کی طرح صورت پیدا ہوئی اور کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور وزیرتعلیم نے اجلاس یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ مشاورت جاری رہے گی۔
مذکورہ بالا دو اجلاسوں کی مختصر رُوداد دینے کا مقصد یہ ہے کہ وزارتِ وفاقی تعلیم جو ’ایک قوم، ایک نصاب‘ کا ڈھول پیٹ رہی تھی اس کے غبارے سے ہوا نکلتی نظر آرہی ہے اور قومی سطح پر یہ جو مثبت تاثر اُبھر رہا تھا کہ یکساں قومی نصاب کا دیرینہ قومی خواب تعبیر کے قریب ہے، اب یہ خواب بکھرتا نظر آرہا ہے جس کی وجوہ درج ذیل ہیں:
۱- وزارتِ وفاقی تعلیم کےارباب بست و کشاد کا واضح جھکاؤ سیکولر لبرل لابی کی طرف ہے، جب کہ قوم کا مجموعی مزاج اسلامی نظریۂ حیات سے سرشار ہے۔ نیشنل کریکولم کونسل میں وزیرتعلیم نے اپنی پسند کے لبرل سیکولر لوگ پورے دھڑلے کے ساتھ شامل کیے ہیں۔ اگر نیشنل کریکولم کونسل کےارکان کی فہرست پر نظر ڈالی جائے توچاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بربناے عہدہ نمایندوں کے علاوہ ۱۱ مرد حضرات اور ۱۰خواتین اراکین ہیں۔ سب نامزد افراد کی وابستگی لبرل سیکولر سوچ سے ہے۔دینی مدارس کے پانچ وفاقوں کے نمایندے البتہ علماے کرام ہیں جو کہ ایک مجبوری تھی لیکن ان نمایندوں کو اسلامیات کے نصاب کے علاوہ کہیں کردار ادا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔
۲- سنگل نیشنل کریکولم کےعنوان سے جو نصاب تیارکیا گیا ہے وہ ارکان نیشنل کریکولم کونسل تک کو مہیا نہیں کیا گیا تھا۔
۳- نصاب کے جائزے کے لیے ضروری ہے کہ ان ضروریات کی فہرست دی جائے جو عصرحاضر میں نرسر ی سے بارھویں جماعت تک ہمارے طلبہ کی نصابی ضروریات کے طور پر وفاقی وزارتِ تعلیم نے ترتیب دی ہیں تاکہ ان ضروریات کی روشنی میں نصابِ تعلیم کی مناسبت کاجائزہ لیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وزارت نے ضروریات پر مبنی ایسی کوئی فہرست نہیں بنائی۔
۴- نرسری سے بارھویں تک پورے نصاب میں سے ایک طالب علم نے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے جو نصاب میں نظر آنا چاہیے۔ گریڈوں یاجماعتوں کی تقسیم ہم اپنی انتظامی سہولت کے لیے کرتے ہیں۔ اس وقت صرف نرسری سے پانچویں جماعت تک کا نصاب دیا جارہا ہے۔ اس سے ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اس کا مڈل جماعتوں اور ثانوی جماعتوں کے نصاب کے ساتھ عمودی ربط موجود ہے اور کسی قسم کا خلا نہیں ہے۔
۵- پانچ سال سے ۱۶ سال کی عمر کی تعلیم قانون کے مطابق ہمارے ملک میں لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے اس دورانیے میں طالب علم کو بالغ زندگی کامیابی سے گزارنے کے لیے تمام معلومات ، تمام مہارتیں اور ضروری اخلاق و کردار اور رویے، رسمی اور غیررسمی تعلیم کے ذریعے مل جائیں۔ خصوصاً آئین کے آرٹیکل ۳۱ کی روشنی میں ۱۶سال کی عمر تک تعلیم حاصل کرکے ہمارے طلبہ و طالبات اس قابل ہوجائیں کہ وہ قرآن و سنت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ محض پری اسکول سے پانچویں جماعت تک کا نصاب دیکھ کر تو یہ معلوم نہیں ہوسکتا کہ مذکورہ نصاب لازمی تعلیم کے دورانیہ کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں۔
۶- سکول سطح کانصابِ تعلیم ایک تسلسل کا تقاضا کرتا ہے جس میں ربط، توازن، تسلسل، وسعت اور گہرائی کا بدرجۂ اتم خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے پوری دنیا کی یہ روایت ہے کہ نصاب جب بھی تیار ہوگا وہ پری سکول سے ثانوی /اعلیٰ ثانوی درجے تک ایک ہی وقت میں تیار ہوگا۔ البتہ اس کے نفاذ کے لیے درجہ وار ترتیب لگائی جاتی ہے۔ ٹکڑوں میں جب نصاب تیار ہوگا اس میں اُفقی اور عمودی ربط اور توازن کی کمزوری لازماً رہے گی۔ وفاقی وزارتِ تعلیم اجزا میں نصاب سازی کرکے تعلیمی دنیا کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی کاارتکاب کررہی ہے۔
۷- ماہرین کی طرف سے یہ اعتراض شدومد سے اُٹھایا جارہا ہے کہ مذکورہ نصاب جو نظریۂ پاکستان، اسلامی نظریۂ حیات اور دستورِ پاکستان کی تعلیم سے متعلق آرٹیکلز کی روشنی میں تیار ہونا تھا، وہ سیکولر، لبرل اقدار کی روشنی میں تشکیل دیا گیا ہے۔ نصاب کی بنیادی اسلامی اقدار، یعنی توحید، رسالت، عبادت اور آخرت،اور معاملات و اخلاقیات کی ذیلی اقدار ہونا چاہیے تھیں، لیکن ان کی بنیاد سیکولر اساسی اقدار پر رکھی گئی ہے جو ناقابلِ قبول ہے۔
۸- رہ گئی بات میڈیم آف انسٹرکشن (ذریعۂ تعلیم) کی تو ۱۶ جولائی کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایک دو کو چھوڑ کر سب نے انگریزی کی مخالفت کی اور سفارش کی کہ پری اسکول سے آخر تک اسکول کی تعلیم اُردو یا علاقائی زبان میں ہونی چاہیے۔ تقریباً متفقہ مخالفت آنے پر وزارتِ تعلیم کے ذمہ داران نے کوئی فیصلہ کیے بغیر میٹنگ ختم کردی۔ ماہرین کی آرا کی روشنی میں اور قومی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے پری اسکول سے ثانوی سطح تک تمام مضامین اُردو یا علاقائی زبان میں پڑھانے کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔
۹- تعلیم اب صوبائی معاملہ ہے۔ وزارتِ وفاقی تعلیم کس اختیار اور قانون کے تحت سنگل نیشنل کریکولم اورسنگل ٹیکسٹ بکس تمام صوبوں میں نافذ کرے گی، جب کہ صوبوں کے اپنے کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈز اور صوبائی اسمبلیوں سے پاس کردہ اپنے قانون موجود ہیں، نیز پرائیویٹ سیکٹر کے اشرافیہ کے اسکولز جوبیرونی امتحانی بورڈز سے منسلک ہیں، کیڈٹ کالجز، آرمی پبلک سکولز، جو مقتدر طبقوں کےادارے ہیں وہ کب اور کس طرح سنگل نیشنل کریکولم کو قبول کریں گے؟ مذکورہ تمام اداروں میں نافذ کرائے بغیر اسے یکساں قومی نصاب کادرجہ کیسے حاصل ہوگا؟
۱۰- وزارتِ وفاقی تعلیم اور نیشنل کریکولم کونسل کے ذمہ دار افسروں نے وزیراعظم کے سامنے کارکردگی دکھانے کی خاطرعجلت میں یہ کیا ہے۔ امرواقعہ ہے کہ یہ سب کچھ ۲۰۰۶ء میں جنرل پرویز مشرف کے نصاب میں معمولی کمی بیشی کا تسلسل ہے، جسےاسلامی حلقوں نے مسترد کر دیا۔
۱۱- یہ غلط دعویٰ کیا جارہا ہے کہ اس نصاب کو پاکستان بھر کے ۷۰ماہرین نے تیار کیا ہے حالانکہ یہ ۲۰۰۶ء کے نصاب میں محض کچھ تبدیلیاں ہیں۔
۱۲- نیشنل کریکولم کونسل کے ذمہ داران نے تعلیمی عمل کے حقیقی اسٹیک ہولڈرز کو نظرانداز کرکے اپنے پسندیدہ نام نہاد ماہرین کو آگے رکھ کر شفافیت کی نفی کی ہے، اور پھر اس طرح رازداری سے کام لیا ہے جس سے شکوک و شبہات نے جنم لیاہے۔ اُن میں سے کسی کو اس دستاویز کا علم نہیں جن کے بچوں کا تعلیمی مستقبل اس سے وابستہ ہے یاجنھوں نے نصاب کے اس مسودے کو نافذ کرنا ہے، یعنی اساتذہ اور محکمہ ہاے تعلیم کے انتظامی ذمہ داران۔
۱۳- وفاقی وزیرتعلیم شفقت محمود نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہہ کر’’ سنگل نیشنل کریکولم صرف کور کریکولم (core curriculum) ہے۔ اگراسکول اور اسکولز سسٹمز اس نصاب میں اضافہ کرنا چاہیں گے تواُن کو اجازت ہوگی‘‘،یکساں قومی نصاب کے غبارے سے خود ہی ہوا نکال دی ہے۔ یہ وہ بدترین پسپائی ہے جو اشرافیہ کے تعلیمی اداروں کے انکار اور دباؤ کی وجہ سے کی گئی ہے۔
۱۴- پنجاب کے وزیرتعلیم ڈاکٹر مراد راس نے وضاحت کی ہے کہ یکساں قومی نصاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام اسکول صرف وفاق کاقومی نصاب ہی پڑھائیں گے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وفاق نے ایک نصابی فریم ورک دیا ہے جس کے اندررہ کر پڑھانا ہوگا، باقی ادارے اگر اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو اس کی ان کو آزادی ہوگی۔ نیز ایک ہی درسی کتاب بھی مطلوب نہیں ہے۔ ان وضاحتوں نے یکساں قومی نصاب کا تصور ختم کرکے رکھ دیاہے۔اصل ہدف یہ نظر آتا ہے کہ دینی مدارس میں مقتدر قوتوں کے دباؤں کے تحت سیکولر نصاب رائج کیا جائے اوران کا موجودہ دینی تشخص آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے۔ سرکاری ادارے تو شاید ہی مذکورہ نصاب نافذ کریںگے۔
۱۵- اگر حکومت یکساں قومی نصاب کے مسئلے پر سنجیدہ ہے تو اسے بیرونی امتحان پر پابندی اور بیرونی بورڈز کے تعلیمی سرٹیفکیٹس کی نامنظوری کی قانون سازی کرنی چاہیے جو ظاہر ہےممکن نہیں ہوگی کیونکہ ان اداروںاور ان بیرونی امتحانات سے منسلک سیاست دانوں، بیوروکریٹس، ججوں، جرنیلوں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے نونہالوں کا روشن مستقبل وابستہ ہے۔ اس طرح یکساں قومی نصاب صرف غریبوں پرہی نافذ ہوگا۔
۱۶- یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سنگل نیشنل کریکولم کا یہ سارا ڈھونگ حکومت کے سیکولر تعلیمی ایجنڈے کا حصہ ہے اور ہدف محض دینی ادارے ہیں۔ اس کے پیچھے امریکی کمیشن براے مذہبی آزادی اور دیگر مغربی قوتیں ہیں۔ ملک کی اندرونی سیکولر لابی ایک طرف تو نیشنل کریکولم کونسل میں غالب حیثیت بلکہ فیصلہ کن حیثیت میں موجود ہے اور دوسری طرف سیکولر، لبرل اور کرسچین این جی اوز کے پلیٹ فارم سے بعض معروف خواتین و حضرات متحرک ہیں۔ ان این جی اوز کی ۳مارچ۲۰۲۰ء کے سیمی نار جس کی صدارت جناب شفقت محمود نے کی اور پھر ۱۰جولائی ۲۰۲۰ء کا Webinar اور ان دونو ں اجلاسوں کی کارروائی سنگل نیشنل کریکولم کے لبرل سیکولر ایجنڈے کی حمایت میں نظر آتی ہے۔ اسی سیمی نار میں شرکا کے مطالبے پر جناب شفقت محمود نے وعدہ کیا تھا کہ ’’وہ سارا مواد نصاب سے خارج کردیا جائے گا جس پراقلیتوں کواعترض ہے‘‘۔
اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز صاحب نے اپنے ریمارس میں کہا کہ ہم جہاد، محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی کے ذکر کو نصاب سے خارج کردیں گے۔ ۱۰جولائی کے سیمی نار میں اسکول، کالج اور یونی ورسٹی کی سطح پر ترجمہ کے ساتھ قرآن کی تدریس کو ہدفِ تنقید بنایا گیا۔
اس عجیب و غریب صورتِ حال میں اصل نقصان قومی نظامِ تعلیم کا ہو رہا ہے جس کےلیے پارلیمنٹیرین، دانش وروں، عالموں اور استادوں کو اپنا فرضِ منصبی ادا کرتے ہوئے ایک جانب سیکولر یلغار کی مزاحمت کرنی چاہیے اور دوسری جانب مثبت طور پر اقدامات تجویز اور نافذ کرانے چاہییں۔
’ظن‘ کا مطلب ہے گمان، خیال،قیاس (Assumption, Conjecture, Supposition) ’علم‘ اور ’ظن‘ میں بہت نمایاں فرق ہے۔یہی فرق انسانی رویوں اور زندگی گزارنے کے انداز میں تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے۔
راہ سے ہٹنے (گمراہی) کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں: اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ ہُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ۱۱۶ (الانعام ۶:۱۱۶) ’’وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں‘‘۔
گمان کا مطلب علم کا فقدان ہے: مَا لَہُمْ بِہٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ۰ۚ (النساء ۴:۱۵۷) ’’ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے‘‘۔ اور اگر علم نہ ہو، تو صرف گمان کے بل پر حق تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے: وَمَا يَتَّبِـــعُ اَكْثَرُھُمْ اِلَّا ظَنًّا۰ۭ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَـيْــــًٔـا۰ۭ (یونس ۱۰:۳۶) ’’حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جارہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا‘‘۔
اسی طرح آخرت کے متعلق محض ظن کی موجودگی اور یقین کی غیرموجودگی سے زندگی کا پورا رویہ بدل جاتا ہے: مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَۃُ۰ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ۳۲ (الجاثیہ ۴۵:۳۲)’’ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے‘‘۔
یہ تو وہ امور ہیں جن پرہماری اُخروی سعادت و فلاح کا انحصار ہے۔ قرآن کے دیے ہوئے اصول عمومی اور زندگی بھر کے لیے ہیں ، جنھیں ہم مختلف معاملات پر منطبق کرسکتے ہیں۔
ظن کے بجائے علم تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟
۱-اگر وہ غیب، چھپی ہوئی چیز ہے تو قرآن ہمیں ایسا انداز عطا کرتا ہے، جس میں تصدیق کی بہت اہمیت ہے، یعنی سچ کو سچ کہنا اور اس تک پہنچنے کے لیے واضح بات یا ’تبیین‘ یا ’تفصیل‘۔ حق اور غیب کی معرفت کے لیے آیات دی گئیں، یعنی نشانیاں جو کہ قرآن کی آیات بھی ہیں، کائنات میں پھیلی اور انسان کے اپنے جسم میں پھیلی نشانیاں بھی ہیں۔ ان نشانیوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور ان پر تدبروتفکر کی دعوت دی گئی۔ پھر رسولؐ جن کی بات پر ہم ایمان لائے ہیں، ان کی صفات سامنے لائی گئیں کہ وہ صادق ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس لیے ان کی کہی ہوئی بات بالکل سچ ہے۔ پھر جو فرشتہ اس پیغام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تک لایا ،اس کے متعلق اطمینان دلایا گیا کہ وہ بھی امانت دار ہے۔
ایک عمومی بات سکھائی گئی کہ تمھیں علم نہیں تو اہلِ ذکر (اہل علم)سے پوچھ لو (النحل۱۶: ۴۳)۔ بات کی تحقیق کرکے واضح کرلو چاہے کوئی فاسق خبر لائے (الحجرات ۴۹:۶) یا کوئی میدان جنگ میں سلام کرے(النساء۴:۹۴)۔
۲- اگر وہ کوئی قول ہو تو اس کی صداقت کوکیسے پرکھا جائے؟ دنیا کی سب سے سچی کتاب جب مصحف کی شکل میں لکھی جانے لگی تو یہ کام حضرت زیدؓ بن ثابت کو دیا گیا، جو خود کاتب قرآن اور حافظِ قرآن تھے۔ ان کے ساتھ صحابۂ کرام ؓ کی ٹیم تھی جو کہ سب حفاظ قرآن تھے۔ سارے صحابۂ کرامؓ سے آیات جمع کی گئیں جو چھال،لکڑی،پتے، پتھر، ہڈی، کھال یا کپڑے پر لکھی ہوئی تھیں۔ یہ وہ اوراق تھے جو صحابۂ کرامؓ لکھتے جاتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد لے کرآتے۔ ہررمضان میں ’عرضہ‘ ہوتا۔ آپؐ تلاوت کرتے جاتے اور وہ اپنے حصوں کو دیکھ کر جانچتے۔کبھی آپؐ ان سے پڑھوا کر سنتے۔ ان سب کو منگوایا گیا ۔ ہر آیت کو مصحف میں لکھنے کے لیے یہ اصول بنایا گیا کہ وہ کم ازکم دو اصحابِ رسولؐ کے پاس لکھی ہوئی ہو اور اس کی دوشہادتیں ہوں۔ اس طرح قرآن کا باقاعدہ مصحف تیار ہوا۔
کسی کے ذریعے پہنچے ہوئے قول کو کیسے پرکھیں؟ احادیثِ نبویؐ کی تدوین کی محنت اور اصول قابلِ تحسین ہیں۔ محدثین نے ایک ایک حدیث کے راویوں کی سند جوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ۔ محدثین نے ہر حدیث کی سند کے ایک ایک راوی کے حالات زندگی جمع کرلیے۔ انھوں نے یہ بھی معلومات جمع کیں کہ ہر راوی کا کردار،سچائی ،دیانت اور حافظہ کیسا تھا؟ پھر کچھ عقل کے معیارات پر حدیث کو پرکھ کر اسے درج کیا گیا۔ ان معلومات کی بنیاد پر آج بھی کوئی شخص، ہرحدیث کو پرکھ سکتا ہے اور ظن کے بجائے علم کے درجے پر پہنچ سکتا ہے۔
۳- اگر وہ کسی چیز کی افادیت کے بارے میں کوئی نظریہ ہے تو اس کوپرکھنے کے لیے تجربہ کیا جاسکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک چیز استعمال کرائی جائے اور نتیجہ یہ نکالا جائے کہ یہ چیز کامیاب رہی۔ لیکن اس کا امکان ہے کہ استعمال کیے بغیر بھی نتائج ایسے ہی نکلتے۔ لہٰذا تجربے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک جیسے دو گروہ بنا کر ، ایک پر اس چیز کا انطباق کریں اور دوسرے پر نہ کریں اور پھر نتائج کا فرق دیکھیں۔ موازنہ اور مقابلہ کرنا بھی ہمیں قرآن نے سکھایا ہے جہاں الفاظ کی ضد ان کے ساتھ استعمال کی گئی ہے، مثلاً ہدایت اور گمراہی، نور اور ظلمات، اندھا اور بینا، سعادت اور شقاوت، صلاح اور فساد۔ آیات میں ’لا یستوی…‘ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہےکہ یہ دو چیزیں برابر نہیں ہیں۔ آیات میں آتا ہے : افمن کان… کمن کان…… جس کا مفہوم ہوتا ہے: ’ کیا جو ایسا ہے وہ اس جیسا ہوسکتا ہے جو ایسا نہیں ہے؟‘۔
مندرجہ بالا تذکیر سے کسی بات کو صحیح سمجھ کر قبول کرنے کے لیے، یا ظن کے درجے سے اُٹھ کر علم تک آنے کے لیے، یہ اصول سامنے آتے ہیں: اگر کسی کا قول سامنے آیا ہے تو ماننے سے پہلے دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے یا یہ قول کہاں سے شروع ہوا؟ اس کی دیانت کے ساتھ اس کا علم اور تجربہ کیسا ہے؟ بذاتِ خود وہ بات کیا ہے؟ اگر کوئی نظریہ ہے تو اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اس کی نشانیاں موجود ہیں اور کس درجے کی ہیں؟ اگر قابلِ تجربہ ہے تو کیا اس کو پرکھا گیا ہے؟
زندگی کے مختلف دائروں میں تجزیہ کرنا چاہیے کہ کون سے امور علوم ہیں اور کون سا رویہ محض ظن پر مبنی ہے۔ زیرِ تحریر سطور شعبۂ طب خصوصاً علاج سے متعلق ہیں۔
یہ بہت عام ہے کہ علاج یا بیماری کے سلسلے میں ایک بات مشہور ہوجاتی ہے جو کہ کسی کی ذاتی راے ہوتی ہے۔ پھر وہ لوگ اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس کی راے یا تجربہ ہے؟ اورنہ یہ معلوم ہوتا کہ یہ کتنے لوگوں کا تجربہ ہے اور جنھوں نے استعمال نہیں کیا ان کا تجربہ کیا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ وہ چیز مفید ہی ہو، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کا کوئی کردار ہی نہ ہو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس چیز کا کوئی بڑا نقصان ہو رہا ہو۔
بہرحال، بلا تحقیق و تجربہ کسی شے کو بطورِ علاج پیش کرنے اور قبول کرنے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ خصوصاً دورِ جدید میں جہاں دلائل، تحقیق اور تجربہ کے شواہد کے بغیر کسی بھی طریقِ علاج کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ شعبہ طب (میڈیسن) میں دواؤں کے عام اجرا سے پہلے تحقیق کا ایک انتہائی مربوط نظام رائج ہے۔اس نظام سے آگاہ کرنے سے پہلے بعض چیزوں کی وضاحت کی جارہی ہے۔
اس کو عرف عام میں ایلوپیتھی کہا جاتا ہے، مگر یہ نام اس کے نصاب کی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ اس کا نام پچھلی صدی میں کسی دوسرے طریق علاج نے ایلوپیتھی رکھا تھا جس کا مطلب تھا علاج کا مختلف طریقہ ۔ اس کے اپنے حلقوں میں اسے میڈیسن کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن شاید یہ بھی اس کا صحیح نام نہیں۔ کیوںکہ میڈیسن کے علاوہ بہت کچھ اس میں شامل ہے۔ اس کے متعلق عوام الناس میں پھیلے کچھ خیالات یہ ہیں: اس کی دوائیں مصنوعی اور فطرت سے دور ہیں، اس میں صرف علامات کا علاج ہے اصل مرض کا نہیں، اس میں اصل علاج جراحت یا چیر پھاڑ کر الگ کرنا ہے، اس میں حفاظتی تدابیر اور جسم کو مضبوط بنانے پر زور نہیں۔
اس کو اندر سے پرکھنے والے جانتے ہیں کہ اس طریقِ علاج میں یہ چیزیں شامل ہیں:
lجڑی بوٹیوں پر ریسرچ اور قدرتی چیزوں سے اخذکردہ بنائی گئی دوائیںl لیبارٹری میں بنائی گئی دوائیں اور تحقیق lفزیکل میڈیسن، یعنی ورزش اور posture کے متعلق ہدایات l گرم اور سرد سکائی، بھاپ جیسی چیزیں lداغنے lسرجری یا جراحت بحیثیت آخری انتخاب جو صدیوں سے ہورہا ہے،اور جس کے بانیوں میں الزھراوی شامل ہیں۔
غذائیت کے مباحث اورغذائی اجزا کی تفصیل بھی میڈیسن کی شاخ ہے: احتیاطی تدابیر معاشرتی سطح سے شروع ہو کر فرد کی سطح تک، جزئیات کے ساتھ،علامات کا علاج ، پیچیدگیوں کو روکنا، بیماری کی جڑ ختم کرنا۔اس میں بیماری کے اسباب (etiology) کے ساتھ بیماری کے حملے سے ہوشیار رہنے کے اسباب بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ انفیکشن کے سبب جرثومے کو بھی مارتا ہے اور اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی عمل کرتا ہے۔ کوئی کمی یا زیادتی ہو تو اس کے لیے بھی تدبیر کرتا ہے۔ جڑ بنیاد میں اس حد تک جاتا ہے کہ موروثی بنیاد (genes ) کی سطح پر اتر کر اس کی تحقیق اور اس کی انجینیرنگ کرتا ہے۔
ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ اہلِ مغرب کی ملکیت ہے یا دور جدید کا عطیہ ہے یا غیرمسلموں کی میراث ہے۔ یہ جرمنی اور چین سے شروع نہیں ہوا، اور نہ یہ صرف ایک دو صدی پرانا ہے۔ اس علم کو ترقی دینے والے یہ لوگ ہیں، جن سے مغربی دنیا نے استفادہ کیا ہے:انسانی جسم کی ساخت بیان کرنے والے:عبدالملک اصمعی(۸ویں صدی) اور علی بن ربان طَبَری (۹ویں صدی)۔ دورانِ خون، نظامِ تنفس بیان کرنے والے : ابن النفیس(۱۳ویں صدی)۔ ماہرچشم: ابن الھیثم (۱۰ویں صدی) اور علی ابن عیسیٰ۔ ماہر طب : بو علی سینا (۱۰ویں صدی، کتاب القانون فی الطب)، ابنِ رشد (۱۲ویں صدی، کتاب کلیات فی الطب)، فارابی (۱۰ویں صدی)،ابنِ زھر (۱۲ویں صدی)۔ ماہرِ ادویات : ابن البیطار (۱۳ویں صدی)۔ ماہرِ جراحت: ابو القاسم الزھراوی (۹ویں صدی)۔
براہِ کرم اس علم کو اسلام اور غیر اسلام کے موازنے کی نذر نہ کریں،نہ اس کو مشرق اور مغرب کے تقابل کا عنوان بنائیں۔ دنیا بھر کے سیکڑوں مسلمان ڈاکٹر اس نظام کا حصہ بھی ہیں اور اس کو پرکھتے بھی ہیں۔ اس میں کوئی غیر اسلامی عنصر ہوا تو ان شاء اللہ وہ امت کو خبردار کریں گے اور اس سے بچاؤ کی راہیں بھی نکالیں گے۔
اس میں تشخیص سرسری یا کسی ایک چیز پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ تشخیص کا پورا نظام ہے۔ جس میں جزئیات کے ساتھ مریض کی علامات کی تفصیل ، معائنہ اور لیبارٹری ٹسٹ شامل ہیں۔
یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اس میں دواؤں کو مضر اثرات کا خیال کیے بغیر دیا جاتا ہے یا دوائیں ہوتی ہی ایسی ہیں کہ ان کے مضر اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ بلاشبہہ ہر طریق علاج کی دواؤں کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں۔میڈیسن میں دواؤں کے مضر اثرات اور باہمی تعامل (interactions) تفصیل سے پڑھائے جاتے ہیں اور ہر دوا کے ڈبے کے ساتھ لکھے بھی جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر دوا کے مضر اثرات دیکھتے ہوئے ، فائدہ اور نقصان کی میزان پر پرکھ کر، اور مریض کو ضروری معلومات دے کر دوا دیں۔ پھر اس میں تحقیق، تجربات اور مشاہدات کا پورا نظام ہے اور اس سے گزر کر ہی کسی علاج کو عالمی سطح پر قبول کیا جاتا ہے۔
دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کا علم یہ احاطہ کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک خلیے اور اس کے مالیکیولز کی سطح پر کیا کرے گی اور ایک عضو اور پورے جسم پر مجموعی طور پر کیا اثر کرے گی؟
تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ پچھلے علوم اور فنون میں سے مفید چیزوں کو برقرار رکھتا ہے لیکن ان پر تکیہ نہیں کرتا اور اس کی آگے بڑھنے کی رفتار بہت تیز ہے۔ مشاہدات، تجربات، ایجادات، اور ان کے ساتھ اس کا علم شاخ در شاخ تقسیم ہوتا چلا جارہا ہے۔ ہرمیدان میں طبّی علم کو تخصص تک لے جاتا اور کُل علم کے ساتھ مربوط رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔
میڈیکل میں کوئی دوا یا علاج کب منظور ہوتا ہے؟ اس کے لیے تحقیقی مطالعہ ایک طریقے کے تحت ہوتا ہے۔ دو گروپ بنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو ایک چیز استعمال کرائی جاتی ہے اور دوسرے کو نہیں کرائی جاتی، مثلاً کوئی بھی دوایا جڑی بوٹی ۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ دونوں گروپس کے نتائج میں کیا اور کتنا فرق ہے؟ اس کو ’اتفاقی نظم کے تحت تجربہ‘ کہتے ہیں۔
دوسرے طریقے میں کچھ لوگ خود سے کوئی چیز مثلاً کوئی خاص غذا استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ استعمال نہیں کرتے ۔ اسے ’گروہی مطالعہ‘ کہا جاتا ہے۔
تیسرے طریقے میں جو لوگ صحت یاب ہوچکے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے کتنوں نے وہ چیز استعمال کی تھی اور کتنوں نے نہیں کی تھی؟ اور جو لوگ صحت یاب نہیں ہوسکے یا جن میں پیچیدگی ہوگئی ، ان میں سے بھی کتنوں نے وہ چیز استعمال کی تھی اور کتنوں نے نہیں کی تھی؟
ہر مرحلے پر اتفاقات اور غلطی کو بھی دُور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ کام ہوتا ہے۔ یہ مطالعے یا اسٹڈیز تحقیقی مجلّوں میں شائع ہوتی ہیں اور جب کسی چیز کے:۱- مفید ہونے یا۲- مضر ہونے یا ۳-کوئی بھی کردار نہ ہونے پر کئی تحقیقاتی مطالعے ہوجاتے ہیں تو ان سب مطالعوں کا مجموعی تجزیہ کیا جاتا ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ عالمی طور پر اس چیز کو قبول کیا جائے یا نہیں؟ جہاں دو راے کی گنجایش ہوتی ہے، اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اس نظام میں اس دلیل کا وزن بہت کم ہوتا ہے کہ یہ کسی کی ذاتی راے یا تجربہ یا مشاہدہ ہے۔ درحقیقت طبی ماہرین کے مجموعی مشاہدات، تجربات اورنتائج سے تقریباً ہر بیماری اور علامت کے لیے اصول، نتائج اور ادویات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔
دواؤں کے اثرات کے متعلق کوئی نتیجہ، اسی تحقیقی نظام سے گزرکر نکالا جاتا ہے۔موجودہ کووڈ۱۹ کی وبا میں کچھ علاج جیسے Remdesivir (وائرس کو مارنے والی دوا)، Tocilizumab (وائرس کے اثرات روکنے والی دوا)، plasma antibodies کو عالمی سطح پر اسی لیے تجویز نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اگرچہ ان کے کچھ ہی اچھے نتائج ملے ہیں لیکن ان پر کی جانے والے تحقیقاتی مطالعے یا تو ناکافی ہیں یا ان کے حق میں نتائج کا وزن اتنا زیادہ نہیں،یا ان کے دوسرے گروپ سے موازنے میں زیادہ وزن سامنے نہیں آسکا۔ اسی لیے کافی تحقیق اور نتائج مرتب ہونے سے پہلے ڈاکٹروں کا انھیں استعمال کرنا غلط ہے۔ اُمت مسلمہ کو دلیل، شہادت اور اس بنیاد پر چیزوں کو قبول کرنے کا ورثہ ملا ہے۔ مسلم اطباء کو اسی نوعیت پر کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔
میڈیسن میں تحقیقی نظام کے مقابلے میں یہ رویہ دیکھیں:
۱- ایک بات مشہور ہوگئی کہ پپیتے کے پتوں سے پلیٹ لیٹس بڑھتے ہیں (جس کی کوئی وجہ اس کے سوا سمجھ نہیں آئی کہ دونوں لفظ ’پ‘ سے شروع ہوتے ہیں)۔ نہ یہ معلوم ہوا کہ یہ کہنا کس نے شروع کیا؟ کس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ پتے استعمال کرکے دیکھے؟ نہ اس پر تحقیق ہوئی کہ جنھوں نے استعمال کیے ان میں اور جنھوں نے نہیں کیے ان میں کیا فرق رہا؟ درحقیقت ڈینگی بخار میں وائرس کی وجہ سے بخار ختم ہونے کے بعد پلیٹ لیٹس خود ہی جسم کے نظام کے تحت بڑھنا شروع ہوجاتے ہیں۔ اگر کوئی اور پیچیدگی شروع نہ ہوگئی ہو تو سب مریضوں کے پلیٹ لیٹس بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی بے سروپا باتوں کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔
۲- کچھ غذائی اجزا کے متعلق کہا جانے لگتا ہے کہ وہ کسی مخصوص بیماری کا علاج ہیں۔ بلاشبہہ وہ بہت مفید ہوں گی، مثلاً ادرک ، لہسن، لیموں ، وٹامنزکی گولیاں وغیرہ۔ ان سب سے عمومی صحت اور مدافعتی نظام توبہتر ہوسکتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی انفیکشن شروع ہونے کے بعد یہ ان کا علاج نہیں ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اس بیماری سے متعلقہ ہدایات پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح ورزش، سورج کی روشنی آپ کے لائف اسٹائل کا حصہ ہوں یا آپ ابھی اس کو اپنانے کا فیصلہ کرلیں، تو یہ مختلف بیماریوں سے بچنے میں ایک مددگار عنصر ہوسکتی ہے، لیکن ایک شدید تر بیماری کی موجودگی میں ورزش کرنےاور سویرے سویرے بھاگ دوڑ کرنے سے علاج نہیں ہوگا، اور کوئی ان پر انحصار بھی نہیں کرے گا۔
اس کے علاوہ جو چیزیں ویسے بھی ہمارے کھانوں کا عمومی حصہ ہیں اور ہر کھانے میں استعمال ہورہی ہوتی ہیں، ان کو بار بار علاج کے طور پر پیش کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح کبھی خواہ مخواہ کے پرہیز بتائے جاتے ہیں۔ ان میں اکثریت ایسے پرہیزوں کی ہوتی ہے کہ ان سے فائدے کے شواہد موجود نہیں ہوتے، موہوم سا گمان ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کے بعد فائدہ ہوا ہوگا اور اتنی ہی تعداد میں لوگوں کو فائدہ نہیں بھی ہوا ہوگا۔ اس لیے تحقیق اور تجربے کے بعد کوئی بات کہنا چاہیے۔
واضح رہے کہ تحقیق کے بعد اگر ثابت ہوچکا ہو کہ کسی بیماری کی وجہ ہی کچھ غذائی اجزا کی کمی ہے۔ اس میں ان اجزا کے سپلیمنٹ، ڈاکٹر خود ہی ان غذاؤں کے نام بتادیتے ہیں مثلاً خون کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، یا وٹامن ڈی اور وٹامن سی کی کمی ہے تو انھیں دُور کرنے کے لیے غذا بتائی جاتی ہے ۔ اگر کسی بیماری کا کسی غذائی جز سے بڑھنا سامنے آرہا ہو تو اس کا پرہیز بتایا جاتا ہے۔
۳- کچھ جڑی بوٹیوں کے متعلق یہ مشہور ہوجاتا ہے کہ وہ کسی بیماری کا علاج ہیں۔ ان کے متعلق یہ بات اگر اوپر بیان کردہ تحقیقی نظام کے بعد کہی گئی ہے تو ٹھیک ہوسکتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی راے تھی اور لوگوں نے سن کر بطور علاج شروع کردیا اور بیماری کے بعد صحت کے عمومی نظام کے تحت جو مریض ٹھیک ہوگئے ، انھیں دلیل کے طور پر پیش کیا تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔
میڈیسن کے نظام میں ہر چیز پر تجربے کیے جاتے ہیں۔جڑی بوٹیاں شروع سے ان کا اہم حصہ ہیں اور ان پر بھی اسی طرح تجربات کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ مفید پائی جاتی ہیں تو دوائیں ان سے بھی بنتی ہیں۔ ان میں دل کی دوائیں بھی ہیں، جلد پر لگانے کی، درد ، ملیریا، دمہ ،کینسر ، کولسٹرول کم کرنے کی ، دماغی امراض کی اور انٹی بایوٹک بھی۔
۴- اسی طرح دوسرے طریق علاج ہیں۔تعصب کسی چیز سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تحقیق کے بغیر کسی چیز کو علم کے طور پہ پیش نہیں کرنا چاہیے، اور تجربات کے بعد کوئی چیز مفید پائی گئی ہو تو اس کو قبول کرلینا چاہیے۔
یہ رویوں کا نام ہے، جو کسی میں بھی پائے جاسکتے ہیں۔ عام فرد بھی اگر مستند ڈاکٹر سے پوچھ کر کام کرتا ہے تو اپنی ذمہ داری پوری کردیتا ہے۔ اور اگر ڈاکٹر بھی انھی سنی سنائی چیزوں کو آگے بڑھاتا رہے جو درج بالا سطور میں درج کی گئیں تو اس کا رویہ ’علم‘ کا رویہ نہیں۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ میڈیسن کے مختلف اصل ماخذِ علم تک رسائی رکھے اور وہاں سے دلیل کی بنیاد پر علم حاصل کرے۔ اور اگر یہ نہیں کرسکتا تو کم ازکم سنی سنائی بات آگے کسی سے نہ کہے۔
ضمناً ایک بات جو کہ طریقِ علاج تو نہیں لیکن علاج سے ہی متعلق ہے۔ موجودہ عالمی وبا کے دوران شروع میں بلاتحقیق، یہ باتیں پھیلیں کہ کورونا ڈراما ہے، ہسپتال خالی پڑے ہیں، قبرستان میں مردے کم آرہے ہیں۔ پھر شاید انھی لوگوں نے یہ باتیں شروع کردیں کہ ڈاکٹر زہر کا انجکشن لگارہے ہیں، ڈاکٹر کورونا کا انجکشن لگارہے ہیں، ٹسٹنگ کٹ کے ذریعے کورونا پھیل رہا ہے، ٹسٹ کو خواہ مخواہ مثبت کردیتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر کورونا لکھنے کے پیسے ملتے ہیں، خالی تابوت دے کر کہتے ہیں کہ اس میں آپ کے مریض کی میت ہے۔ اصل لاشیں تو دوسرے ملکوں کو بیچ رہے ہیں۔
کوئی بات جس پر یقین کیا جاسکتا ہے ، وہ یہ تو ہوسکتی ہے کہ کسی مریض نے آکر بتایا کہ ہسپتال میں خیال رکھنے میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی، یا ہسپتال والوں نے، یا دکان داروں نے بہت زیادہ نرخ رکھے ہیں۔ لیکن اوپر جو باتیں درج کی گئیں، ان کو شروع کرنے والوں اور پھر آگے پہنچانے والوں کو قرآن و حدیث کے وہ احکام یاد رکھنا چاہییں جو بہتان لگانے، کوئی بات سن کر بلاتحقیق آگے بڑھانے کے متعلق ہیں۔ اور وہ نقصان الگ ہے جو اس صورت میں ظاہر ہوا کہ جن لوگوں کو طبی امداد سے فائدہ ہوسکتا تھا، وہ بھی ان باتوں پہ یقین کرکے یا تو جان سے گزر گئے یا زیادہ متاثر ہوئے۔
ایک عرصے سے پاکستان میں مختلف درجات میں، حکومتی سطح اور غیرحکومتی سطح پر اور ابلاغی اداروں پر، سیکولر جارحیت اور لبرل فسطائیت کے نقوش نمایاں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ۱۴جون ۲۰۲۰ء کو، پنجاب کے گورنر نے سرکاری یونی ورسٹیوں کے وائس چانسلروں کے اجلاس کے بعد یہ اعلان کیا کہ ’’ڈگری کے حصول کے لیے، طالب علم کوترجمے کےساتھ قرآن پڑھ کرسنانا ہوگا‘‘۔ اس اعلان کا قوم نے خیرمقدم کیا، لیکن ردعمل کے طورپر اخبارات میں اس اعلان کی مخالفت پرمبنی کالم تحریر کیےگئے۔ اس مناسبت سے دو تحریریں پیش کی جارہی ہیں۔ (ادارہ)
مفتی منیب الرحمٰن
ایک وقت تھا کہ جب پاکستان کے مسلمانوں میں دین اور دینی شعائر کے بارے میں بجاطور پر حسّاسیت زیادہ تھی۔ اپنی تمام ترشخصی اور عملی کوتاہیوں کے باوجود دین اوردینی مقدّسات کی بے حُرمتی برداشت نہیں کرتے تھے۔فوراً توانا ردِعمل آتا اور ایسی مذموم حرکات شروع ہی میں دم توڑ دیتیں۔ مُلحدین اور دین بیزار طبقات ہردور میں رہے ہیں۔ ماضی میں جب وہ دین کے بارے میں بے زاری کا اظہارکرتے تو کسی ’مولوی‘ کو نشانہ بناتے، کبھی مسجد اور مدرسے کو ہدفِ تنقید بناتے، الغرض براہِ راست نشانہ بنانے کی جسارت نہیں کرپاتے تھے۔ لیکن جب سے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل اور سوشل میڈیا کی مختلف صورتیں وجود میں آئی ہیں،قرآن، رسولؐ، اسلام اور مقدّساتِ دین پر براہِ راست حملے کیے جارہے ہیں۔ یہ ہمارے روزمرہ مشاہدے کی بات ہے کہ اگر حسّاس اداروں سے وابستہ شخصیات کے بارے سوشل میڈیا میں کوئی نازیبا بات کرے تو اُسے تلاش کرکے بھرپور گوشمالی کی جاتی ہے۔ لیکن یوں نظر آتا ہے کہ اب وطن عزیز کے ریاستی و حکومتی نظم میں دینی مقدّسات کا دفاع اور تحفظ شاید کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔
اشارے کنایے میں شراب کی ترغیب و تشویق اخباروں کے ادارتی صفحات میں آئے دن دی جاتی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب حلال و حرام اور دینی و سماجی اخلاقیات کی مناسبت سے اخباروں کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم سے بے زاری کا بھی برملا اظہار کیا جارہا ہے۔ گورنر پنجاب نے یہ اعلان کیا: ’’قرآنِ کریم کا ترجمہ پڑھے بغیریونی ورسٹیوں سے ڈگری نہیں ملے گی‘‘۔ حالانکہ تاحال یہ بات محض ایک اعلان ہے، اس کے پیچھے کوئی مؤثر قانون سازی نہیں ہے۔ لیکن اُردو اور انگریزی اخبارات کے بعض کالم نگاروں نے اس پر شدید احتجاج کیا ہے۔
سوال یہ ہے کہ ’’کیا یہ لوگ پاکستان کے دستور کو تسلیم کرتے ہیں؟‘‘
اگر جواب ’ہاں‘ میں ہے تو دستورِ پاکستان کے آرٹیکل ۲ میں لکھا ہے: ’’اسلام ریاست کا سرکاری مذہب ہوگا‘‘۔ آرٹیکل ۲-اے میں ہے: ’’قراردادِ مقاصد میں بیان کردہ اصول اور احکام کو دستور کا مستقل حصہ قراردیا جاتا ہے اور وہ بِحَسْبِہٖ مؤثر ہوں گے‘‘۔ قراردادِ مقاصد میں لکھا ہے: ’’چونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کُل کائنات کا بلاشرکت غیرے حاکمِ مطلق ہے اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اُس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنےکا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے‘‘۔
پھر دستورِ پاکستان میں یہ بھی لکھا ہے: ’’مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اوراجتماعی طورپر اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے تقاضوںکے مطابق بسر کرسکیں، جیساکہ قرآن و سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے‘‘۔
دستورِ پاکستان کے آرٹیکل ۳۱ کے تحت لکھا ہے:
۱- ’’پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اورانھیں سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، جن کی مدد سے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں۔
۲- پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت یہ کوشش کرے گی:
(الف) قرآنِ پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے لیے سہولت بہم پہنچانا، قرآن پاک کی صحیح اور من و عن طباعت و اشاعت کا اہتمام کرنا (ب) اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیاروں کی پابندی کو فروغ دینا، زکوٰۃ و عُشر، اوقاف اورمساجد کی باقاعدہ تنظیم کرنا‘‘۔
اس آرٹیکل میں قرآن و سنت کی تعلیمات، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی اور سہولتیں فراہم کرنے کو ریاست کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، جب کہ ہمارے سیکولر، لبرل اوردین بے زار دانش وروں کو قرآن کا ترجمہ پڑھانے کی بات اس طرح کھٹکی کہ جیسے قیامت نازل ہوگئی ہو۔
دستور کے آرٹیکل ۲۰۳(الف) میں ’وفاقی شرعی عدالت‘ کی تشکیل اور اس کےفرائض و اختیارات کے ذکر میں یہ درج ہے: ’’اس باب کے احکام دستور کے دیگر احکام پر غالب ہوں گے‘‘۔ یعنی اس امرکی تشریح کہ ملک میں پہلے سے نافذ العمل کوئی قانون یا نیا قانون جو منظوری کے مراحل میں ہے، آیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ یہ طے کرنے کا اختیار ’وفاقی شرعی عدالت‘ کے پاس ہے اور ان فرائض کی ادایگی میں دستور کی کوئی دفعہ یا قانون، اس کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے۔
آرٹیکل ۲۲۷ کا عنوان ہے: ’قرآن و سنت کے بارے میں احکام‘ اور درج ہے: ’’تمام موجودہ قوانین کو قرآن و سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا، جن کا اس حصے میں بطورِ اسلامی احکام حوالہ دیا گیا ہے اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو‘‘۔
دستورِ پاکستان کے اس آرٹیکل میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں: (الف) گذشتہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنا (ب) تمام نئے قوانین اسلام کے مطابق بنانا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عمل قرآن و سنت کو پڑھے اور جانے بغیر تکمیل پاسکتا ہے؟ جب کہ دستور کی رُو سے اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کی سفارشات پارلیمنٹ میں پیش ہونی ہیں اور پارلیمنٹ کو بحث کے بعد ان کی منظوری دینی ہے۔ لیکن اب ہمارے ’آزاد خیال‘ دانش وروں کے نزدیک ریاست و حکومت کے اُمور اور نظامِ تعلیم میں قرآن کے ترجمے کی بات کرنا بھی قابلِ گردن زدنی اور یہ ناقابلِ معافی جرم ہے، بلکہ قائداعظم کے پاکستان کی روح کو سلب کرنے کے ہم معنی ہے۔
گذشتہ صدی کے وسط سے ، اس کے اختتام تک سیاست اور سیاسی جماعتوں پر کسی حد تک نظریات کی ’تہمت‘ لگتی تھی۔ اُس دور کے عالمی سیاسی ماحول اور دو سوپر پاورز کی کش مکش کے تناظر میں رائٹسٹ اور لیفٹسٹ، یعنی دائیں بازو، بائیں بازو اور اسلام پسند کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی تھیں۔ کسی حد تک لوگ سیاسی نظریات کو جانتے بھی تھے اور نظریاتی وابستگیاں بھی رکھتے تھے۔ لیکن اب یہ سب باتیں قصۂ ماضی بن گئی ہیں۔ اب سیاست صرف مفاداتی، گروہی اور شخصیت پرستی تک محدود ہوکر رہ گئی ہے۔ سیاسی ’مزارعین‘ کو اپنے لیڈروں کی ناموس کے دفاع سے فرصت ملے تو دین کے دفاع کے لیے وہ وقت نکالیں۔ اس لیے اُن پر نظریاتی حساسیت کی ’تہمت‘ لگانا خود کو شرمسار کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن جب کوئی دستوری اساس، یعنی اسلام اورقرآن و سنت پرحملہ کرے تو دستورِ پاکستان کی رُو سے وفاقی و صوبائی کابینہ، پارلیمنٹ کے ارکان، اعلیٰ عدلیہ،سول اور مسلح اداروں کی اعلیٰ قیادت کی ذمے داری ہے کہ وہ اس کے آگے سدِراہ بنیں، کیوںکہ ان سب نے دستور سے وفاداری کا حلف اُٹھا رکھاہے۔
مگر یہی دکھائی دیتا ہے کہ دین اور دینی شعائر کے تحفظ کے فرض کی ادایگی کے لیے نہ وقت ہے اور نہ اس عہد کی کوئی اہمیت۔ ان سب کے سامنے اسلام کا جو حشر ہورہا ہے، کوئی دشمنِ اسلام بھی شاید ہی کرسکے۔ اس صورتِ حال کا مرثیہ ان الفاظ میں پڑھیے:
میں اگر سوختہ ساماں ہوں، تو یہ رُوزِ سیاہ
خود دکھایا ہے ، مرے گھر کے چراغاں نے مجھے
یعنی اسلام کو اگر زبان عطا کی جائے تو وہ برملا یہ فریاد کرے گا: آج جو ناکامیاں میرے کھاتے میں ہیں، میرے وقار و افتخار کا سارااثاثہ جو جل کر راکھ ہوچکا، اس کا گلہ مجھے کسی دشمن سے نہیں ہے۔ یہ انجام میرے گھر کے چراغاں نے مجھے دکھایا ہے۔ میرے ماننے والوں نے ’گھرپھونک، تماشا دیکھ‘ کا یہ منظر خود تخلیق کیا ہے۔ اس پر کسی اور کو الزام دینے کے بجاے انھیں خود کو ملامت کرنا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔
یہی حال ہماری صحافت کاہے ۔ کبھی اس پر نظریے کی چھاپ تھی، مگر اب نظریے سے اس کا دامن ’صاف‘ ہے۔ کسی زمانے میں نواب زادہ نصراللہ خان مرحوم نے ایک بڑے اخبار کے بارے میں کہا تھا: ’’وہ تو ایک ڈیپارٹمنٹل اسٹور ہے‘‘۔ مراد یہ کہ اُسے کسی نظریے سے کچھ بھی غرض نہیں ہے، ہرطرح کا مال اپنے شوروم میں سجارکھا ہے۔ گاہک آئےاور اپنی پسند کا مال اُٹھا لے۔ اسی طرح ہمارےہاں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلوں کی بہار تو آگئی ہے، لیکن نظریے سے عاری ہے۔ بس اتنا ہے کہ طاقت کے جس مرکز سے گرم ہوا آتی ہے، اس کے بارے میں یہ محتاط رہتے ہیں، باقی جس کے ساتھ جو کھلواڑ چاہے کریں، اور نان ایشو کو ہمالہ بناکر رونقیں لگائیں۔
یوں لگتا ہے کہ مذہبی،سیاسی ، سماجی، صحافتی، ادبی تنظیموں کے نزدیک قرآن و سنت کی ناموس کے تحفظ کا مسئلہ ثانوی ترجیح کے درجے میں چلا گیا ہے۔ آج تعلیم کو سیکولرائز کرنے کے لیے بھرپور کوششیں اور فیصلے کیے جارہے ہیں۔ لیکن ان پر کوئی قابلِ ذکر علمی، احتجاجی یا سیاسی کاوش دکھائی نہیں دیتی!
شاہ نواز فاروقی
پاکستان کے سیکولر عناصر کا اسلام پر حملہ کرنے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے، تو وہ اسلام پر براہِ راست حملے کی جرأت نہیں کرتے، بلکہ وہ علما، مولویوں، ملاؤں اور امریکی و بھارتی فوجیوں سے برسرِپیکار سرفروشوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی کچھ پرانی ہوچکی ہے۔ اب تو پاکستان میں سیکولر اور لبرل لکھنے والوں کی جرأت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ براہِ راست اسلام کو نشانہ بنانے کی ہمت کر رہے ہیں۔ اس سنگین حملے کا پس منظر یہ ہے کہ گورنر پنجاب نے بطور چانسلر، پنجاب کی یونی ورسٹیوں میں قرآنِ مجید کو ترجمے سے پڑھنا لازم قرار دے دیا ہے۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھے بغیر کسی کو ڈگری نہیں مل سکے گی۔ قرآن کو پنجاب کی یونی ورسٹیوں کے تعلیمی پروگرام کا لازمی حصہ بنانے کا عمل تین سیکولر کالم نگاروں کو اتنا بُرا لگا ہے کہ انھوں نے اس فیصلے پر اپنے اپنے انداز سے بھرپور وار کیا ہے۔
روزنامہ دنیا اور ’دنیا ٹیلی ویژن‘ سےوابستہ ایاز امیر کے الفاظ ملاحظہ کیجیے:
’’شاعر مشرق نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری جرمنی کی ہائیڈل برگ یونی ورسٹی سے حاصل کی۔ قائد اعظم نے بارایٹ لا ’لنکنز اِن ‘(برطانیہ) سے کیا۔ اپنی اپنی ڈگریاں حاصل کرنے سے پہلے نہ مفکر مسلمانانِ ہند اور نہ معمارِ پاکستان ہی پہ ایسی کوئی شرط عائد ہوئی کہ وہ قرآن پاک کی ناظرہ اور ترجمے کی مہارت حاصل کریں.... دونوں کی خوش قسمتی ہی سمجھی جانی چاہیے کہ وہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے عہد میں طالب علم نہ تھے۔ ورنہ ممکن ہے یوں کرنا پڑتا۔ شاعر مشرق کو تو شاید مشکل نہ پیش آتی، لیکن قائد اعظم، جن کی ساری تعلیم انگریزی میں تھی، کو تھوڑی بہت دِقّت ضرور ہوتی۔
’’قائد اعظم کے بغیر برصغیر میں ایک مسلم ریاست کا قیام ناممکن ہوتا، لیکن قائد اعظم نے اپنی درخشاں زندگی میں [ایسے] شوشوں کا سہارا کبھی نہ لیا.... اُن کی تمام تقاریر چھان ڈالیے، کوئی فضول کا نعرہ نہیں ملے گا۔ لیکن اُن کی وجہ سے بننے والے ملک کی جو پاکستانی قوم کہلاتی ہے، اُس کی تو زندگی ہی فقط نعروں اور شعبدے بازی پہ مبنی ہے۔جہاں سے شاعرِ مشرق اور معمارِ پاکستان فارغ التحصیل ہوئے، وہاں اگر یہ کہا جائے کہ ڈگریاں تب ملیں گی، جب آپ انجیل سے چند اوراق پڑھیں گے اور اُن کا مفہوم بیان کرسکیں گے تو قہقہہ ایسا اُٹھے گا کہ اُس کی گونج ساتویں آسمان تک پہنچ جائے، لیکن یہاں بغیر کسی چوں و چرا کے چھے سات یونی ورسٹیوں کے وائس چانسلروں [کے] اجلاس [میں] فیصلہ ہوتا ہے کہ کالج اور یونی ورسٹی کی ڈگریاں تب تک نہیں دی جائیں گی، جب تک طالب علم قرآن پاک کو بطور مضمون اختیار نہیں کریں گے‘‘(روزنامہ دنیا،۲۰ جون ۲۰۲۰ء)۔کالم نگارنے قرآن کی تعلیم کا جس طرح خاکہ اُڑایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
اسی طرح ’جنگ‘ اور ’جیو‘ گروپ کے انگریزی اخبار دی نیوز کے کالم نویس غازی صلاح الدین صاحب نے اپنے کالم (۲۱ جون ۲۰۲۰ء) میں قرآن کی تعلیم کا خاکہ اُڑاتے ہوئے لکھا:
یقین کریں یا نہ کریں پنجاب کے گورنر نے ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے صوبے بھر کی یونی ورسٹیوں میں قرآن کو اُردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازمی قرار دے دیا ہے۔ اس کے بغیر کسی کو ڈگری نہیں مل سکے گی۔
پھر روزنامہ پاکستان ٹائمز کے سابق ایڈیٹر اور اب انسانی حقوق کی تنظیموں میں سرگرمِ کار آئی اے رحمان صاحب نے انگریزی روزنامہ ڈان میں قرآن کی تعلیم پر حملے کے لیے جو کالم لکھا، اس کا متن تو رہا ایک طرف،خود عنوان ہی توہین آمیز ہے: Creeping Religiousity یعنی ’رینگتی ہوئی مذہبیت‘۔ موصوف نے لکھا:’’یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ ضیاء الحق اور اس کی جگہ لینے والوں نے چالیس سال تک معاشرے میں اپنی طرز کا اسلام مسلط کرنے کے بعد ایک قانون بناڈالا ہے، جس کے تحت نوجوانوں کو قرآن پڑھنے پر مائل کیا جائے گا۔ اسلام ایک رضا کارانہ مذہب ہے۔ پنجاب کی حکومت کو یہ خیال کہاں سے آیا کہ ان طلبہ کو سزا دی جائے گی جو قرآن نہیں پڑھیں گے۔ علما خود اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا پنجاب حکومت کا یہ اقدام ’دین میں کوئی جبر نہیں ہے‘ کے مذہبی اصول کے مطابق ہے؟‘‘ (ڈان، کراچی، ۲۵جون ۲۰۰۲ء)
اسی طرح پرویز ہود بھائی نےروزنامہ ڈان (۱۹جولائی ۲۰۲۰ء) میں یہ سنا دیا ہے کہ ’’ڈگری حاصل کرنے کے لیے قرآن سنانے کی پابندی تو انتہاپسند ضیاء الحق نے بھی نہیں لگائی تھی‘‘۔
ایازامیر یہ تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اقبال اور قائد اعظم جیسے جدید تعلیم یافتہ افراد کا قرآن یا اس کے علم سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ’’اقبال تو شاید قرآن پڑھ بھی لیتے مگر قائد اعظم کو تھوڑی بہت دقّت ضرور ہوتی‘‘۔ اطلاعاً عرض ہے کہ کالم نگار نے اقبال اور قائد اعظم کا جو تصور اپنے ذہن میں باندھا ہے، وہ ان کے ذہن کی پیداوار تو ہوسکتی ہے، مگرحقیقی زندگی میں ایسا نہیں تھا۔ دیکھیے، اقبال کو قرآن سے عشق تھا اور ان کی شاعری قرآن کی تعلیمات میں ڈوبی ہوئی شاعری ہے:
وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر
اُسی قرآں میں ہے اب ترکِ جہاں کی تعلیم
جس نے مومن کو بنایا مہ و پرویں کا امیر
خود بدلتے نہیں ، قرآں کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق
قرآن میں ہو غوطہ زن اے مردِ مسلماں
اللہ کرے تجھ کو عطا جدّتِ کردار
علّامہ محمد اقبال کے یہ اشعار بتا رہے ہیں کہ اقبال کے نزدیک ’’مسلمانوں کا عروج قرآن کو اختیار کرنے کی وجہ سے تھا اور مسلمانوں کا زوال قرآن کو ترک کردینے کی وجہ سے ہے‘‘۔ اقبال مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمھیں جدتِ کردار درکار ہے، تو قرآن میں ڈوب کر ہی یہ متاع گراں مایہ ہاتھ آسکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس اقبال کو قرآن سے اتنی محبت ہے وہ قرآن کو نہیں پڑھتا ہوگا؟
اقبال خود کو مولانا روم کا مرید کہتے تھے۔ انھوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ: ’’مولانا علم کا ایک سمندر ہیں اور میں اس سمندر کے ساحل پر پڑا ہوا ایک کوزہ‘‘۔ اور یہ بات کون نہیں جانتا کہ مولانا روم کی شاعری کو فارسی میں قرآن کی تعلیمات کا مظہر کہا گیا ہے۔ جنھوں نے اقبال کی شاعری کو سرسری طور پر پڑھا ہے انھیں معلوم ہے کہ اقبال کی پوری شاعری کی لغت مذہبی یا قرآنی ہے۔ ان حقائق کے باوجود یہ صاحب ’تاثر‘ دینا چاہتے ہیں کہ اقبال کی ساری دل چسپی جدید مغربی تعلیم سے تھی، قرآن سے انھیں کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ہرپڑھا لکھا شخص جانتا ہے کہ زندگی کے آخری زمانے میں اقبال کا یہ حال ہوگیا تھا کہ وہ قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور جب بھی انھیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ رہنمائی کے لیے قرآن اُٹھالیتے تھے۔
روزنامہ دنیا کے کالم نگار نے اقبال کو تو کچھ نہ کچھ ’مسلمان‘ مان بھی لیا، مگر قائد اعظم کو تو انھوں نے تقریباً ’اس کے برعکس ‘ بنا کر کھڑا کردیا کہ ایک ایسا آدمی، جس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوسکتا۔ پاکستان کے سیکولر اور لبرل عناصر کا خمیر، ناقص معلومات، جہالت، اسلام دشمنی اور انھی چیزوں پر فخر سے اُٹھا ہے۔ چنانچہ قائد اعظم کے سلسلے میں ایاز صاحب لاعلمی اور جہالت کا شکار ہیں۔ انھوں نے اپنے بچپن میں سیکولر شیاطین سے قائد اعظم کے بارے میں سبق لیا ہوگا کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، حالاں کہ تاریخی شہادتوں سے ثابت ہے کہ وہ تواتر سے قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھا کرتے تھے۔
قرآن کے ساتھ قائداعظم کے گہرے تعلق کو ثابت کرنے کے لیے ہم مذہبی اسکالروں کی سند بھی لاسکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ اس سلسلے میں برطانوی نژاد محقق خاتون سلینا کریم سے رجوع کیا جائے، جنھوں نے قائد اعظم پر ایک ضخیم کتابSecular Jinnah And Pakistan: What The Nation Doesn’t Know لکھی ہوئی ہے۔ چودہ ابواب پر مشتمل اس کتاب کے ایک پورے باب کا عنوان ہے: The Quran and Jinnah’s Speeches، یعنی قرآن اور جناح کی تقاریر۔ اس باب میں سلینا کریم صاحبہ نے سات موضوعات پر قائد اعظم کی تقاریر کے اقتباسات پیش کیے ہیں اور پھر وہ قرآنی آیات درج کی ہیں، جن سے قائد اعظم کے سات بیانات برآمد ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ کیجیے: Secular Jinnah and Pakistan (ص ۲۳۵ تا ص ۲۵۲ )۔ اس باب کے اختتام پر سلینا کریم اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں:
]ترجمہ]یہ مثالیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں کہ جناح کس پُرجوش طریقے سے قرآنی اصولوں کی لفظی اور معنوی اعتبار سے پاس داری کرتے تھے۔ وہ خاص طور پر قرآن کے اصول توحید کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔
مسٹر ایاز نے لکھا ہے کہ مغرب کی جن یونی ورسٹیوں سے اقبال اور قائد اعظم نے تعلیم حاصل کی، ان میں اگر کسی طالب علم کو انجیل کی آیات پڑھنے کے لیے کہا جاتا تو وہاں قہقہہ بلند ہوتا۔ مغرب کے بے خدا، لامذہب، رسالت اور وحی بیزار معاشرے میں ایسا ممکن ہے، لیکن کیا پاکستانی معاشرہ بھی خدا کا انکار کرتے ہوئے، اس کے تذکرے کے لیے استہزا کا راستہ اپناچکا ہے اور مذہب سے لاتعلق ہوچکا ہے؟ رسالت اور وحی کا منکر ہوچکا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر اخبارات اور ٹیلی ویژن کے یہ سیکولر اور لبرل عناصر پنجاب کی یونی ورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کا مذاق کیوں اُڑا رہے ہیں؟
دی نیوز کے غازی صاحب نے قرآن کی تعلیم پر اپنا مذکورہ پیراگراف Believe it or not کے الفاظ سے اس طرح لکھا ہے، جیسے ’ویٹی کن سٹی‘ میں نفاذ اسلام کردیا گیا ہو۔ انھیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں تعلیمی اداروں میں قرآن نہیں تو کیا بائبل اور گیتا پڑھائی جائے گی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پنجاب کی یونی ورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کے عزم پر غازی صاحب کا رنگ فق ہوگیا ہے؟
آئی اے رحمٰن صاحب نے تو دیدہ دلیری کامظاہرہ کرتےہوئے سرے سے قرآن کی تعلیم کو ’سزا‘ ہی بنادیا۔ پھرموصوف نے کج فہمی کے عالم میں قرآن کی آیت ’دین میں کوئی جبر نہیں‘ تک کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر ڈالا ہے۔ حالانکہ ’دین میں کوئی جبر نہیں‘ کا تعلق اس بات سے ہے کہ اسلام میں کسی غیر مسلم کو جبر کے تحت مشرف بہ اسلام نہیں کیا جاسکتا، جب کہ ایک اسلامی ریاست میں قرآن و سنت کی تعلیم کا نظم قائم کرنا جبر نہیں عین رحمت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان کے سیکولر طبقے، سیکولر اور لبرل تعلیم کو ’جزا‘ اور قرآن کی تعلیم کو ’سزا‘ تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ عناصر سرعام قرآن و سنت کے خلاف صف آرا ہیں، مگر نہ ریاست کو اس بات کی فکر ہے، اور نہ علما نے بڑے پیمانے پر اس کے مضمرات و نتائج پرغور فرمایا ہے۔
کشمیر کی تاریخ اور اس سے وابستہ تاریخی المیے پر بہت سی کتب شائع ہوئی ہیں، لیکن بعض کتب اپنی معلومات کی وسعت اور اسلوب کی شُستگی کے باعث پُراثر علمی شان رکھتی ہیں۔ اسی نوعیت کی ایک کتاب Kashmir: A Walk Through History ہے، جس کے مصنف خالدبشیر احمد کا تعلق وادیِ کشمیر سے ہے۔ موصوف تحقیق و تصنیف کے ساتھ اعلیٰ ادبی ذوق رکھتے ہیں۔ آپ کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے تاریخِ کشمیر پر ایک کتاب Kashmir: Exposing the Myth Behind the Narrative لکھ چکے ہیں۔
زیرتعارف کتاب میں انھوں نے کشمیر کی تاریخ کے چند بنیادی واقعات کو تحقیق کے بعد قلم بند کیا ہے۔ غیر ریاستی اور غیرمسلم مؤرخین کے حوالے سے کشمیر پر تاریخی حقائق پیش کیے ہیں۔ خاص طور پر ڈوگروں کے مظالم اور نیشنل کانفرنس کے قائدین کی دغابازیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔
پہلا باب ہے ’لاپتا مسجد‘ (The Missing Mosque)۔ سری نگر شہر کی ’تخت سلیمانی‘ نامی پہاڑی جس کو آج ’شنکر اچاریہ‘ پہاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پر ایک مسجد کے وجود کو تاریخی حوالوں اور دستاویزات سے ثابت کیا ہے۔ ڈوگرہ دور میں مسجد کے وجود کو ختم کرنے اور اس جگہ کو بھگوان شیو کے لیے وقف کرنےجیسی مذموم حرکت پر تحقیقی ثبوت دیے ہیں۔
دوسرا باب ہے ’یاترا کی تاریخ‘ (History of Pilgrimage) بتایا گیا ہے کہ امرناتھ یاترا کو سیاسی مقاصد کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ امرناتھ گپھا، سری نگر سے ۱۴۵کلومیٹر کی دُوری پر واقع ہے۔ اس گپھا میں پانی کے قطرے ٹپکنے سے برف کا ٹکڑا جم جاتا ہے، جس کو ہندو لوگ’شیولنگم‘ کہتے ہیں۔اس یاترا کو اب مذہبی کے بجائے سیاسی رنگ دے کر زیادہ سے زیادہ یاتریوں کو اس گپھا کے درشن کرائےجاتے ہیں۔ پہلے چندسو افراد پندرہ دنوں کے لیے یاترا پر آتے تھے۔ اب اس یاترا کی مدت دو ماہ تک پہنچا دی گئی ہے۔ پہلے چند ہزار یاتری جاتے تھے اور اب یاتریوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ یہ یاتری دریاے سندھ کے منبعے کو لاہی اور تھجو اسن گلیشیرز کے درمیان واقع امرناتھ گپھا کے درشن کرتے ہیں اور آبی وسائل کے ساتھ ساتھ جنگلات کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں اورپانی آلودہ ہورہا ہے۔ اس یاترا کو سیاسی رنگ کے باوجود کشمیری مسلمانوں نے ان شردھالوؤں کی میزبانی کا بہترین حق ادا کیا ہے۔
تیسرے باب ’جموں میں قتل عام‘ (Jammu Massacres) میں ۱۹۴۷ء کے دل دوز واقعات کا ذکر ہے، جس میں شیخ عبداللہ کی قیادت میں کانگریس نوازنیشنل کانفرنس کی قیادت کی دغابازیوں کی خوب خبر لی ہے۔ تقسیم ہند کے ڈیڑھ ماہ بعد جموں شہر کے مسلمانوں کو یہ کہہ کر گاڑیوں میں لادا گیا کہ آپ کو پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ لیکن ان معصوم اور نہتے مسلمانوں کو راستے میں ہی گولیوں، تلواروں اور برچھیوں سے تہ تیغ کرکے ان کی لاشوں کو دریا بُرد کرنے کے علاوہ نذرِ آتش بھی کر دیا گیا۔ مصنف نے مثال کے طور پر ایک واقعے کا ذکر کیا ہے: [ترجمہ] جموں کے شہر ادھم پور میں ۲۵؍اکتوبر ۱۹۴۷ء عید کے دن مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ سیکڑوں افرادپریڈ گراؤنڈ میں جمع تھے اور اُن کو دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کو کہا گیا: ’’موت یا ہندو مذہب قبول کرنا‘‘۔ پھر ہلّہ بول کر بہت سے نہتے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس قتل عام میں سے چند زندہ بچ جانے والوں میں وزیرہ بیگم کا کہنا تھا: بچوں کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کھانے کے ساتھ ملا کر پکایا گیا اور یہ کھانا ان زندہ بچ جانے والے مسلمانوں کوکھلایا گیا۔ وزیرہ بیگم کا کہنا ہے کہ میں نے کھانے میں بچوں کی انگلیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اسی طرح سے چودھری عبداللہ خان کی بیٹی رضیہ بیگم کا کو ٹھاکر بلون سنگھ کے ہاتھوں اغوا اور پھر زبردستی شادی رچانے کا دل دوز سانحہ بھی درج ہے۔
چوتھا باب ’خون ریزی کے عینی شاہد‘ (Eye Witnessess to Bloodshed) جموں میں قتل عام کے چشم دید گواہوں میں کرشن دیوسیٹھی، ویدبھیم، پروفیسرعبدالعزیزبٹ، چودھری شبیراحمد سلیری، محمود احمد خان، بلراج پُری، چودھری فتح محمد، خواجہ عبدالرؤف، وزیرہ بیگم، حاجی محمدبشیر، جمال الدین عبدالرشید کنتھ شامل ہیں۔ انھوں نے روح فرسا رُودادیں بیان کی ہیں۔ وزیرہ بیگم نے قتل عام کے بعد جموں میں زندہ بچ جانے والے مسلمانوں کےایک کیمپ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا: [ترجمہ] ’’جب شیخ عبداللہ ، زندہ بچ جانے والے مسلمانوں کے کیمپ میں گئے، تو وہاں موجود مسلمانوں نے اپنے اُوپر مظالم کا تذکرہ کیا۔ جواب میں شیخ عبداللہ نے کہا:’’یہ سب کچھ جموں کے مسلمانوں کے ساتھ ہونا ہی تھا، کیوں کہ انھوں نے مجھے کبھی اپنا لیڈر تسلیم ہی نہیں کیا‘‘۔
پانچویں باب میں ’جناح اور کشمیر‘ (Jinnah and Kashmir) میں قائداعظم کے کشمیر میں مختلف دوروں، خاص طورپر ۱۹۴۴ء کے دورے کا تفصیل سے ذکر ہے۔ مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے قائداعظم کے لیے الگ الگ جلسے کا تذکرہ ہے۔ بارہ مولا میں مسلم کانفرنس کے منعقدہ جلسے میں تقریر کے دوران نیشنل کانفرنس کے کارکنوں، نے جن کی قیادت مقبول شیروانی کر رہے تھے، قائد اور مسلم کانفرنس کے خلاف نعرے بازی کے واقعے کو بھی صفحۂ قرطاس پہ رقم کیا ہے۔
چھٹے باب میں ’باقاعدہ لکھا ہوا تنازع‘ (A Scripted Controversy) میں اُردو زبان کے خلاف روزِ اوّل سے سازشوں کا احوال لکھا ہے۔ ۱۹۸۲ء میں ایک اسمبلی ممبر مرحوم غلام احمد شنٹو اسمبلی میں اُردو زبان کے حق میں تقریر کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگئے۔ مصنف نے ان کو ’شہیدِ اُردو‘ کے لقب سے یاد کیا ہے۔ واضح رہے کہ جموں و کشمیر سے روزِ اوّل سے اُردو زبان و ادب کو نکال دینے کے لیے سازشیں جاری ہیں۔
ساتویں باب ’ ایک صدی کی یادیں‘ (Recolletions of Century) میں محمدصدیق پرے مرحوم نے اپنی سوسالہ زندگی کے چند واقعات بیان کیے ہیں۔
کشمیر میں سیاسی جدوجہد کے حوالے سے چودھری غلام عباس کی عظیم قربانیاں ہیں۔ ان کے تذکرے کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ عینی گواہان اور مؤرخین کے ساتھ کشمیر کی تاریخی جگہوں کی تصاویر نے بھی کتاب کو زینت بخشی ہے۔ کتاب گلشن بُکس سری نگرکشمیر نے شائع کی ہے۔