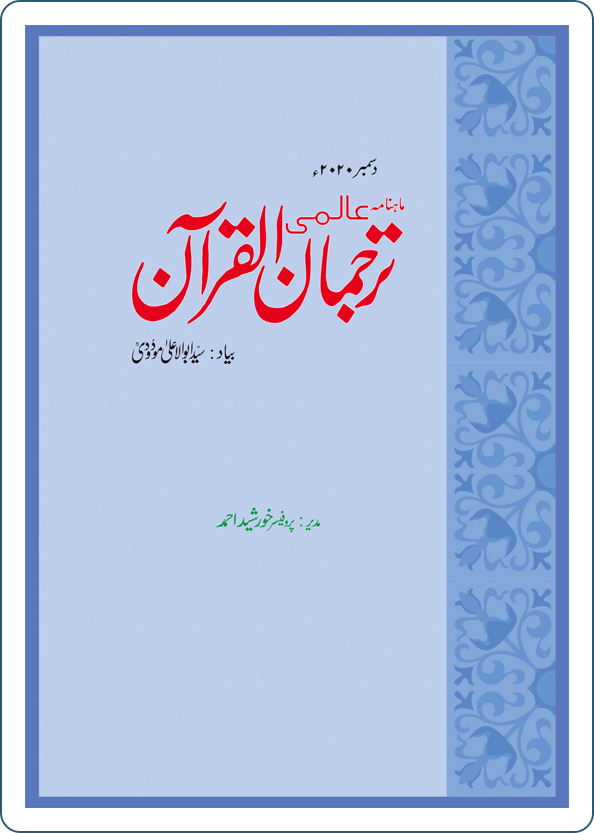
اکتوبر ۱۹۴۷ء کی صبح کو نواب افتخار حسین ممدوٹ نے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ اس وقت ان کی عمر ۴۵سال کے لگ بھگ تھی۔ درازقد، صحت مند، خاموش طبع اور صاف ستھرے ذہن کے مالک اور تقسیمِ ہند سے قبل وہ ایک چھوٹی سی ریاست یا بالفاظ دیگر جاگیر کے کرتا دھرتا تھے۔ یہ جاگیر سترھویں صدی عیسوی میں [ان کے آبا کو] ایک مغل حکمران نے دی تھی۔ نواب صاحب تحریکِ پاکستان کے اکابرین میں شامل رہے اور اپنی ذاتی دولت کا بڑا حصہ اس تحریک کی نذر کر دیا۔ یہ جاگیر مشرقی پنجاب میں واقع تھی، چنانچہ تقسیم کے وقت اسے ہندستان ہی میں چھوڑ آئے اور لاہور آکر یہاں ایک متوسط درجے کے گھر میں سکونت پذیر ہوگئے۔ ان کی وفاداری اور راست بازی کے پیش نظر محمدعلی جناح نے پاکستان کے قائم ہوتے ہی انھیں مغربی پنجاب کا پہلا وزیراعلیٰ مقرر کردیا۔ اس بنا پر انھیں قائداعظم کے قریب ترین رفقا میں شمار کیا جانے لگا۔
جونہی میں ان کے دفتر میں داخل ہوا، ممدوٹ صاحب رسمی تکلفات کی پروا کیے بغیر کہنے لگے: ’’اسد صاحب، میرے خیال میں اب ہمیں نظریاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام اُٹھانے چاہییں۔ آپ نے ان کے بارے میں تقریراً اور تحریراً بہت کچھ کیا۔ اب آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیا ہمیں وزیراعظم سے رجوع کرنا چاہیے؟‘‘
کئی روز سے مجھے ایسے سوال کاانتظار تھا، چنانچہ میں نے پہلے ہی سے اس کا جواب سوچ رکھا تھا:’’ابھی مرکزی حکومت نے ان مسائل کا ذکر نہیں کیا، اس لیے نواب صاحب! آپ ہی اس ضمن میں پہل کیجیے۔ میری رائے میں آپ ہی کو پنجاب میں ایک ایسا خصوصی ادارہ قائم کرنا چاہیے، جو ان نظریاتی مسائل کو زیربحث لاسکے، جن کی بنیاد پر پاکستان معرضِ وجود میں آیا ہے۔ خدا نے چاہا تو آیندہ حکومتِ کراچی بھی اس اہم فریضے کی جانب متوجہ ہوگی۔ اس وقت وہ اپنی خارجہ پالیسی کو تشکیل دینے میں مصروف ہے۔ ان حالات میں شاید وزیراعظم یا قائداعظم اِدھر زیادہ توجہ نہ دے سکیں‘‘۔
نواب صاحب فوری قوتِ فیصلہ کی صلاحیت کے مالک تھے، چنانچہ انھوں نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے پوچھا: ’’آپ کے اس مجوزہ ادارے کا کیا نام ہونا چاہیے؟‘‘
میں نے جواباً عرض کیا: ’’اس کا نام ’محکمہ احیائے ملّت اسلامیہ‘ مناسب رہے گا، کیونکہ اس سے ہمارے مقصد کی بھرپور ترجمانی ہوگی، یعنی صحیح اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی معاشرتی زندگی اور فکر کی تعمیرنو‘‘۔ ممدوٹ صاحب نے بلاتوقف کہا: ’’بالکل درست، ایسا ہی ہوگا۔ آپ اس ادارے کے قیام کا منصوبہ اور اس کے اخراجات کا ایک تخمینہ تیار کیجیے۔ آپ کو سرکاری طور پر اس ادارے کا ناظم مقرر کیا جاتا ہے اور آپ کی ماہوار تنخواہ شعبۂ اطلاعات کے ناظم جتنی ہوگی۔ مجھے اُمید ہے، آپ اسے قبول کرلیں گے‘‘۔
مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی فیصلہ ہوجائے گا، لیکن نواب آف ممدوٹ کے فیصلوں کا یہی انداز تھا۔ چند دنوں کے اندر اندر اس ادارے کا رسمی میمورنڈم تیار ہوگیا۔ اس کے اخراجات کے تخمینے پر بحث ہوئی۔ شعبۂ مالیات کے سربراہ کے صلاح مشورے سے یہ منظور ہوگیا، اور سرکاری اطلاع نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ یوں دیکھتے دیکھتے محکمہ احیائے ملّت اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ پوری اسلامی دنیا میں یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے پہلا ادارہ تھا۔
میں نے لاہور کے بعض معروف علمائے دین بالخصوص مولانا داؤد غزنوی امیرجماعت اہلِ حدیث سے رابطہ قائم کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ایسے دو اصحاب کے نام بتائیں جو ادارے میں کام کرسکیں، عربی اچھی جانتے ہوں اور میری آیندہ کی تجاویز کو عملی شکل دینے میں جن ضروری حوالوں کی ضرورت پڑے، انھیں احادیث کے ضخیم مجموعوں میں سے تلاش کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ جلد ہی ایسے دو نوجوان اور باصلاحیت علما دستیاب ہوگئے اور انھیں یہ کام تفویض کردیا گیا۔ علاوہ ازیں مجھے پنجاب یونی ورسٹی کے ایک پُرجوش طالب علم کی جزوقتی خدمات بھی حاصل ہوگئیں۔ دفتر کے دیگر انتظامی اور مالیاتی امور کو بحسن و خوبی نبٹانے کے لیے مجھے اپنے قریبی دوست ممتاز حسن کا تعاون حاصل تھا، جو مغربی پنجاب کے شعبہ مالیات کے ایک اہم عہدے پر فائز تھے اور بعد میں اس کے سربراہ مقرر ہوگئے۔
اب میں باقاعدہ طور پر سرکاری ملازم تھا، اس لیے مجھے دو رویہ درختوں کے ایک خوب صورت علاقے چمبہ ہاؤس میں بلاکرایہ گھر بھی مل گیا (یہ لین مہاراجا آف چمبہ کے نام سے موسوم تھی۔ یہ ریاست کوہِ ہمالیہ کے دامن میں واقع تھی اور تقسیم ہند سے پہلے مہاراجا کا یہاں محل تھا)۔ اس گھر کے اردگرد چاروں طرف چھوٹا سا باغ تھا۔ یہ ایک تجارت پیشہ ہندو کی ملکیت تھا، جو ہندستان نقل مکانی کر گیا تھا۔ ممکن ہے،وہاں اسے کسی ایسے مسلمان کا گھر مل گیا ہو، جو اپنا سب کچھ چھوڑچھاڑ کر پاکستان آگیا ہو۔ نظربندی کیمپ سے میری رہائی کے بعد میرا بیٹا طلال کیتھولک اسکول میں بطور اقامتی طالب علم زیرتعلیم تھا۔ یہ لاہور کا اعلیٰ ترین ادارہ تھا جس کو آئرلینڈ کے ڈومینیکن چلا رہے تھے۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ لاہور ہی میں مستقلاً رہایش پذیر تھا،اس لیے طلال اس گھر میں منتقل ہوگیا اور یہیں سے ہر روز اسکول جانے لگا۔ اب میرے لیے یہ نئی صورت حال خاصی اطمینان بخش تھی۔
۳۰ جنوری ۱۹۴۸ء کی صبح کو میں دفتر جانے کے لیے بذریعہ کار گھر سے نکل ہی رہا تھا (میں نے ایک متروکہ کار اپنے نام الاٹ کرا لی تھی) کہ اپنے ہمسائے اور دوست سرسکندر حیات خاں کے بھتیجے سردار شوکت حیات خاں سے میری ملاقات ہوگئی۔ وہ اس وقت خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انھوںنے بتایا: ’’میں نے ابھی ریڈیو پر یہ خبر سنی ہے کہ گاندھی کو قتل کردیا گیا ہے۔ خدا کاشکر ہے کہ قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے‘‘ ___ میں اس کی پریشانی میں برابر کا شریک تھا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ اگر قتل کرنے والا مسلمان ہوتا، تو ہندستانی حکومت اپنی مسلمان رعایا کے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ بہرحال چند گھنٹوں بعد آل انڈیا ریڈیو نے واضح بیان جاری کردیا کہ گاندھی کا قاتل راشٹریہ سوامی سیوک سنگھ کا رکن ہے۔ یہ انھی متعصب ہندوؤں کی جماعت تھی، جس نے ڈلہوزی کے مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا تھا۔
محکمہ احیائے ملّت اسلامیہ کا کام آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ہم زکوٰۃ اور عشر کے اہم موضوع پر پورے انہماک سے تحقیق کر رہے تھے، کیونکہ کسی بھی اسلامی مملکت میں شرعی اعتبار سے محصولیات کی بنیاد انھی دو پر ہے۔ ابھی تلاش و تحقیق کا یہ مرحلہ طے ہو رہا تھا کہ ممدوٹ صاحب نے دوبارہ اپنے دفتر بلایا۔ میرے داخل ہوتے ہی وہ حسب معمول کسی تکلف کے بغیر گویا ہوئے: ’’میں نے ابھی ابھی آپ کا مضمون ’اسلامی دستورسازی کی جانب‘ پڑھا ہے، جو عرفات کے تازہ شمارے میں شائع ہوا ہے۔ آپ انھی خطوط پر قدرے شرح و بسط کے ساتھ ایک میمورنڈم تیار کیجیے۔ میں اسے مغربی پنجاب کی حکومت کی جانب سے شائع کراؤں گا اور اس کو دیکھ کر ممکن ہے، مرکزی حکومت بھی اس جانب متوجہ ہو‘‘۔ چنانچہ ۱۹۴۸ء میں میرا یہی انگریزی مضمون مع اُردو ترجمہ مغربی پنجاب کی حکومت کی زیرنگرانی طبع ہوا۔ کچھ ہفتوں بعد وزیراعظم کی جانب سے مجھے کراچی آنے کا پیغام موصول ہوا۔
لیاقت علی خاں سے یہ میری پہلی ملاقات نہیں تھی۔ میں قیامِ پاکستان سے قبل ان سے گاہے گاہے ملتا رہتا تھا۔ ان سے جب بھی گفتگو کا موقع ملتا، وہ کھلے ذہن اور پوری توجہ سے میری باتیں سنتے اور ساتھ ساتھ متواتر سگریٹ نوشی کرتے رہتے (میں نے جب بھی انھیں دیکھا، انھوں نے اسٹیٹ ایکسپریس کے ۵۰ سگریٹوں کا پیکٹ ہاتھ میں پکڑا ہوتا یا ان کے میز پر پڑا رہتا)۔ اس ملاقات میں بھی وہ سگریٹ سے سگریٹ سلگائے جا رہے تھے۔ انھوں نے مجھے بھی سگریٹ پیش کیا، چائے منگوائی اور مجھے اسلامی دستور پر قدرے تفصیل سے لکھنے کا مشورہ دیا۔ ہماری ابتدائی دو ملاقاتوں میں بھی وہ اس اہم مسئلے پر سنجیدگی سے گفتگو کرتے تھے۔ انھوں نے سلسلۂ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا: ’’لیکن ہم ابھی اس موقع پر خود دستورسازی کا عمل شروع نہیں کرسکتے۔ ہمیں اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ کشمیر پر ہندستان نے قبضہ کرلیا ہے اور ہمارے پٹھان بھائیوں کی سری نگر پر قبضہ کرنے کی کوشش ناکام ہوچکی ہے۔ یہ بھی امرمسلّمہ ہے کہ فوجی اعتبار سے ہندستان ہم سے بہت مضبوط ہے۔ ہم تو ابھی حکومتی مشینری کے کل پرزے درست کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے لیے وقت اور سعی پیہم کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ساتھ سارے کام شروع نہیں کرسکتے۔ میں مانتا ہوں کہ دستور سازی کا عمل اہم اور دور رس نتائج کا حامل ہے، لیکن اسے بھی فی الحال مؤخر کرنا پڑے گا‘‘۔
میں وزیراعظم کی اس گفتگو سے متاثر ہوا، کیونکہ انھوں نے بلاتکلف حکومت کو درپیش تمام مسائل پر کھل کر اظہارِ خیال کیا۔ میں جانتا تھا کہ میری طرح وہ بھی پاکستان کے اسلامی تشخص کو اُجاگر کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن ابھی حالاتِ حاضرہ کے دباؤ کے تحت اِدھر توجہ دینے سے گریز کرر ہے تھے۔ میں نے ان کے مؤقف سے اتفاق کیا اور رخصت ہوتے وقت انھوں نے مجھے کہا: ’’فی الحال ہمیں خود کو اس مسئلے پر سوچ بچار کرتے رہنا چاہیے‘‘۔
اس کے بعد کابینہ کے سیکرٹری چودھری محمدعلی سے کئی ملاقاتیں ہوئیں اور مجھے اندازہ ہوا کہ حکومت کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحکام کا ہے۔ انھوں نے بتایا: ’’قائداعظم نے امیرترین مسلمان حکمران نظام حیدرآباد دکن سے درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان کو سونے چاندی کی شکل میں چند لاکھ پاؤنڈ سٹرلنگ اُدھار دیں اور انھیں اپنے نام پر ہی بنک میں جمع کرا دیں، تاکہ پاکستانی کرنسی کو تحفظ مل سکے۔ لیکن نظام، دولت کے انبار کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے انھوں نے قائداعظم کی درخواست کو رد کر دیا ہے‘‘۔ چند ماہ بعد ہی ہندستان نے حیدرآباد ریاست کی خودمختار حیثیت ختم کر کے اسے اپنے ملک کا حصہ بنا لیا اور نظام کے سونے چاندی کے تمام ذخیرے بھی ہندوستانی حکومت کے تصرف میں چلے گئے۔ نظام کے ساتھ ساتھ خود ان کی آل اولاد اور پاکستان بھی ہمیشہ کے لیے ان خزانوں سے محروم ہوگئے۔
جب میں چودھری محمدعلی سے گفتگو کر رہا تھا، معاً مجھے نظام کے ذاتی خزانوں کی یاد آگئی۔ ۱۹۳۹ء میں، مَیں دوسری بار حیدرآباد گیا تھا اور اس وقت ریاست کے وزیرمالیات نے مجھے اس خزانے کا صرف ایک حصہ دکھایا تھا۔ متعدد کمروں میں قطار اندر قطار صندوق رکھے تھے اور یہ سب سونے اور قیمتی پتھروں سے بھرے پڑے تھے۔ ہیرے جواہرات سے بھرے لوہے کے تھال فرش پر رکھے تھے۔ مال و دولت کا ایک ناقابلِ یقین اور مُردہ ڈھیر، جو ایک فانی شخص کی مریضانہ اور عجیب وغریب حرص کا نمونہ تھا۔
لیاقت علی خاں نے اپنی گفتگو میں آزادیِ کشمیر کی جس جدوجہد کا ذکر کیا تھا، وہ ہمیشہ میری اور ہرپاکستانی کی سوچ پر غالب رہی ہے۔ اس کی جغرافیائی، نسلی اور مذہبی وضع قطع کے باعث اس حسین و جمیل سرزمین کو لازماً پاکستان کا حصہ بننا تھا۔ یہاں کی آبادی کی اکثریت مسلمان ہے۔ تمام بڑے دریا (سندھ، جہلم، چناب اور راوی) مغربی پنجاب کی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں اور یہاں کی معیشت کا انحصار مکمل طور پر انھی دریاؤں پر ہے۔ ہندستانی حکومت اور مہاراجا کے مابین اقرارنامہ کی وجہ سے ریڈکلف نے صریحاً دھوکے بازی سے مسلمانوں کی اکثریت کا ضلع گورداسپور ہندستان کے حوالے کر دیا۔ ریڈکلف کی یہ ’خصوصی نوازش‘ تقسیم ہند کے طے شدہ بنیادی اصول کی خلاف ورزی تھی اور اسے کوئی پاکستانی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت پاکستان اپنی کٹی پھٹی فوج کے سبب ہندستان سے جنگ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے قائداعظم نے کسی فوجی مداخلت کے امکان کو بالکل رد کر دیا۔ حکومت پاکستان کی اس واضح پالیسی کے بعد صوبہ سرحد اور افغانستان کے ملحقہ علاقوں کے پٹھانوں کے قبائل پاکستان کے نام پر کشمیر کو فتح کرنے چل پڑے۔
اکتوبر ۱۹۴۷ء میں محسود، وزیری اور آفریدی قبیلوں کے بڑے بڑے جتھوں نے کشمیر کی سرحد عبور کرکے بارہ مولا اور مظفرآباد پر بلامقابلہ قبضہ کرلیا۔ سری نگر کے اردگرد جو فوج تعینات تھی، اس میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی۔ انھوں نے بھی بغاوت کردی اور پٹھان بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھنے کو تیار ہوگئے۔ قبائلیوں کی پیش قدمی جاری تھی اور سری نگر تک پہنچنا انھیں آسان دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس دوران میں ایک تکلیف دہ واقعہ رُوپذیر ہوگیا۔ یہ قبائل اپنی صدیوںپرانی غارت گری کی جبلت پر قابو نہ پاسکے اور سری نگر کی جانب قدم بڑھانے کے بجائے انھوں نے مظفرآباد کے شہریوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ دو دن تک لوٹ مار کا یہ بازار گرم رہا۔ یہ بڑا نازک وقت تھا، جسے ان قبائلیوںنے ضائع کر دیا۔ چنانچہ اسی عرصے میں ماؤنٹ بیٹن اور جواہر لال نہرو کی ملی بھگت سے جوابی حملے کے انتظامات مکمل کرلیے گئے۔ نئی دہلی میں برطانوی فوج کے تعاون سے ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل فوجی دستوں کو جلدی جلدی منظم کیا گیا۔ انھیں ہتھیار فراہم کیے گئے اور ایک ہلکے توپ خانہ کا بھی انتظام کر دیا گیا، تاکہ وہ سری نگر پر قبضہ کرکے وہاں کے ہوائی اڈے کو بھی اپنے دائرۂ اختیار میں لے آئیں۔ اس طرح فوجی اور غیرفوجی جہازوں کے ذریعے ہندستانی فوج کی خاصی بڑی تعداد کو سری نگر پہنچا دیا گیا، جہاں سے وہ ریاست کشمیر کے دوسرے حصوں پر بھی اپنا تسلط جما لیں۔ آہستہ آہستہ پٹھانوں کو نکال باہر کیا گیا اور پھر ان کا جذبۂ جہاد مدہم پڑتے پڑتے ختم ہوگیا۔
تاہم، کشمیر کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ اسی اثنا میں نئے قبائلی مجاہد اور ناگزیر طور پر پاکستانی فوج کے دستے بھی اس جنگ میں شامل ہوگئے۔ ہندستان نے وادیِ کشمیر پر قبضہ جمائے رکھا اور سرحد کے ساتھ ساتھ دُور تک پناہ گاہیں اور خندقیں بنالیں۔ آج تک ہندستان، کشمیر کے اس حصے پر قابض ہے، جو گلگت سے لداخ اور کارگل کے برفانی پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے۔ بالآخر [بھارت] مسئلہ کشمیر کو مجلس اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں استصواب رائے کی قرارداد منظور کی گئی، جو اس علاقے کی قسمت کا فیصلہ کرے گی۔ حکومت ہندستان نے اس قرارداد کو بڑی بے دلی سے قبول کیا، کیونکہ یہ کھلی ہوئی حقیقت تھی کہ اس قرارداد پر عمل درآمد کا نتیجہ پاکستان کی فتح کی صورت میں نکلے گا۔ چنانچہ ہندستان حیلے بہانے سے بار بار اس مسئلے کو ملتوی کرتا رہا۔ اب یہی مسئلہ کشمیر، پاکستان اور ہندستان کے اچھے ہمسایہ ممالک جیسے تعلقات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ دونوں ملکوں کے سپاہی خندقوں میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔
ستمبر ۱۹۴۸ء میں مون سون کی بارشیں رُکتے ہی میں نے کشمیر محاذ پر جانے کا فیصلہ کرلیا۔
مغربی پنجاب کے فوجی افسران نے مجھے ایک جیپ اور دو سپاہی بطور محافظ مہیا کردیے اور میں کوہِ ہمالیہ کی جانب روانہ ہوگیا۔ مری کے بعد سڑک تنگ اور ڈھلوانی ہوتی گئی۔ کہیں کہیں اسے تھوڑا سا چوڑا کیاگیا تھا،تاکہ وہاں سے مقابل سمتوں سے آنے والی دو گاڑیاں گزر سکیں۔ اس سڑک پر ہندستان کے جنگی جہازاچانک یلغار کرتے اور مشین گنوں سے گولیاں بھی برساتے چلے جاتے تھے، اس لیے ہم رات کو روشنی کے بغیر سفر کرتے تھے۔ ہماری رفتار سُست تھی۔ پہاڑ اور ڈھلوان کے درمیان سرکتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تھے اور کبھی کبھی چند لمحات کے لیے جیپ کی بڑی بتیاں جلا لیتے تھے۔
ہم مظفرآباد کے اردگرد چکر لگاتے ہوئے سورج طلوع ہونے سے پہلے بلندوبالا برف پوش چوٹیوں میں واقع پہلی فوجی چوکی تک پہنچ گئے۔ وہاں سے ہم پیدل چلتے ہوئے فوج کے ایک سپاہی کی رہنمائی میں اُونچی نیچی ڈھلوانوں سے گزرتے ہوئے خاصی بلندی پر آگئے۔ یہاں ایک چرواہے کی پرانی سی جھونپڑی تھی، جو اب فوجیوں کو اسلحہ بھجوانے کے لیے بطور ڈاک چوکی استعمال کی جارہی تھی اور محاذ پر لڑتے ہوئے جو فوجی زخمی ہوجاتے تھے، انھیں ابتدائی طبی امداد بھی یہیں فراہم کی جاتی تھی۔
یہ جھونپڑی پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت پتھریلے ٹکڑوں اور درختوں کی ٹہنیوں سے تیار کی گئی تھی اور یہ چٹان کی دو عمودی دیواروں کے درمیان شگاف میں واقع تھی۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو یہ جھونپڑی سپاہیوں سے بھری پڑی تھی۔ کچھ ابھی اگلے محاذ کے مورچوں سے واپس آئے تھے اور کچھ وہاں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ نچلی چھت کے وسط میں پیرافن کا ایک لیمپ لٹک رہا تھا اور اس کی مدھم سی روشنی کئی چارپائیوں پر پڑ رہی تھی۔ چارپائی مخصوص پاکستانی بستر ہے، جو لکڑی اور انترچھال کی رسیوں سے بنایا جاتا ہے۔ ان چارپائیوں پر زخمی سپاہی آرام کررہے تھے۔ کمپنی کا طبی عملہ یہاں ان کا عارضی علاج معالجہ کر رہا تھا اور جونہی گاڑی پہنچتی، انھیں نیچے وادی میں قائم کردہ ہسپتال پہنچا دیا جاتا۔
یہاں دو آدمیوں نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ ساتھ ساتھ پڑی ہوئی دو چارپائیوں پر لیٹے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ شدید زخمی تھے اور ان کے بچنے کی اُمید بہت کم تھی۔ اس کے باوجود وہ ہشاش بشاش اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میرے جیسے کمزور دل شخص کے لیے یہ عجیب و غریب منظر تھا۔ ان میں ایک کہنے لگا: ’’یار! میں تمھیں بہت جلد دوزخ میں ملوں گا‘‘۔ اور دوسرے نے جواب دیا: ’’نہیں، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اگر ہم مرگئے تو یہ شہید کی موت ہوگی، کیونکہ ہم نے اللہ کی راہ میں جان قربان کی ہے‘‘۔ اسی لمحے سیکٹر کمانڈر کا بھیجا ہوا ایک ماتحت افسر آیا اور ہمیں مورچوں کی طرف لے گیا۔
میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح برف سے ڈھکی زمین پر دستی بیلچوں سے یہ مورچے بنائے گئے۔ یہ اتنے گہرے تھے کہ میرے جیسا درازقد شخص سر اور کندھوں کو جھکائے بغیر بآسانی ان میں چل پھر سکتا تھا۔ وہاں جگہ جگہ جال کے نیچے مشین گنیں نصب تھیں، جن کے بیرل عمودی پوزیشن میں تھے اور وہ اس لیے کہ دشمن کے جہاز نچلی پرواز کرتے ہوئے جو حملے کرتے تھے، اُن سے اِن مورچوں کو محفوظ کیا جائے۔ اس وقت یہاں بالکل خاموشی تھی، البتہ فوجی جوان تیار کھڑے تھے۔ بیش تر سپاہی آرام سے بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے یا سگریٹ نوشی کر رہے تھے، جب کہ کچھ اپنی بندوقوں کی نالیاں صاف کرنے میں مصروف تھے یا کارتوس لگانے والی پیٹیوں کی مرمت کر رہے تھے۔ اس سیکٹر کے تمام فوجی پنجابی تھے اور ان کا تعلق جہلم اور راولپنڈی سے تھا۔ یہ اعلیٰ قسم کے انسان ہیں۔ درازقد، دبلے پتلے، بعض چہرے مہرے یونانی دکھائی دیتے ہیں۔ فوراً مجھے یاد آیا کہ سکندراعظم اور اس کے وارثوں کی کئی نسلیں پنجاب کے اسی علاقے میں مستقلاً اقامت پذیر رہیں۔ ممکن ہے یہ لوگ انھی سے نسلی تعلق رکھتے ہوں۔
میں تقریباً ایک گھنٹہ سیکٹر کمانڈر سے گفتگو کرتا رہا۔ وہ ایک نوجوان میجر تھا۔ میں نے اس کے ساتھ چائے پی۔ وہ اور اس کے فوجی ساتھی مجھ جیسے ایک ایسے مہمان سے مل کر بہت خوش ہوئے جو ان کے بلند حوصلوں کا معترف تھا اور ان کے اس جذبے کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، جس کے تحت وہ ملکی سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ میں نے انھیں مغربی پنجاب کے وزیراعلیٰ [افتخار حسین ممدوٹ] اور ان کے توسط سے پاکستانی لیڈروں کی نیک خواہشات پہنچائیں۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں بلکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا میں پنجابی فوجیوں کا کوئی ثانی نہیں اور وہ اپنے فوجی اوصاف جن سے وہ خود کماحقہٗ آگاہ نہیں، کی اس قدر افزائی کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ میں پہلی بار ان اگلے مورچوں تک آیا تھا اور یہاں کے ماحول نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے خود سے یہاں دوبارہ آنے کا وعدہ کرلیا۔
اب مجھے صحیح تاریخ کا تو علم نہیں، لیکن غالباً دسمبر ۱۹۴۸ء یا ۱۹۴۹ء کے اوائل میں مجھے غیرمتوقع طور پر یہاں آنے کی دعوت موصول ہوئی۔ایک روز لاہور کے سب سے بڑے کتب فروش کی دکان میں نئی مطبوعات کو اُلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ میری نظر میجر جنرل حمید پر پڑی۔ وہ بھی میری طرح ایسی کتابوں کی ورق گردانی میں مصروف تھے۔ لاہور کی بیش تر نام وَر شخصیات کی طرح میں انھیں بھی جانتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے (اس وقت ان کی عمر ۴۰سے کچھ زیادہ تھی)، لیکن وہ کشمیر کے محاذ پر ایک اہم عہدے پر فائز تھے۔ میں نے انھیں پوچھا کہ وہ لاہور میں کیا کر رہے ہیں؟ تو انھوں نے بتایا: ’’محاذجنگ کی گھن گرج سے دُور چند روز کے لیے تعطیلات گزارنے یہاں آیا ہوں اور کل صبح واپس جا رہا ہوں‘‘۔ انھوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی جو میرے لیے خاصی پُرکشش تھی، لیکن میں اتنی جلدی اپنے محکمہ احیائے ملّت اسلامیہ کے کاموں کو یک لخت چھوڑ کر نہیں جاسکتا تھا۔ میں نے جواباً عرض کیا: ’’ابھی نہیں، لیکن ہفتے عشرے میں ایسا ممکن ہے‘‘۔
جنرل حمید کہنے لگے: ’’ٹھیک ہے اگلے ہفتے ضرور آجایئے۔ میں روانگی سے قبل جہلم سے محاذِ کشمیر تک آپ کے لیے گاڑی اور حفاظتی دستے کا انتظام کروں گا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کی آمد کے وقت میں کہاں ہوں گا۔ میں سیکٹر کمانڈروں میں کسی ایک کے نام آپ کو خط دے دوں گا اور وہ آپ کو ہرطرح کی سہولت مہیا کر دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے‘‘۔
ایک ہفتے بعد میں جیپ میں سوار جہلم سے مشرق کی جانب جا رہا تھا، اور ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا۔ وہ پنجاب کی آٹھویں رجمنٹ میں دفع دار تھا۔ دوسرا فوجی پیچھے جیپ کے فرش پر تختوں پر مشین گن جمائے بیٹھا تھا۔ اس سفر کے دوران ہمارا رُخ پہاڑوں کی جانب نہیں تھا۔ ہماری سڑک آہستہ آہستہ دل کش مناظر سے گزرتی ہوئی کشمیر کے صوبہ پونچھ تک جاتی تھی، اور موصولہ اطلاعات کے مطابق وہاں تقریباً ایک لاکھ ہندستانی فوجی قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔
پنجاب اور کشمیر کی برائے نام سرحد عبور کرتے ہی ہم پاکستانی فوج کے پڑاؤ پر جاپہنچے۔ یہاں سیکڑوں خیمے نصب تھے اور پیدل فوج کی خاصی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ یہ لشکرگاہ صوبہ پونچھ ہی کا حصہ تھی اور بھاری مشین گنیں اور چھوٹی توپیں اس کی حفاظت کے لیے لگائی گئی تھیں۔ بظاہر ہندستانی فوج کوئی بڑا حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے یہاں کا عمومی ماحول قدرے پُرسکون تھا۔ کیمپ میں فوجیوں اور اسلحہ کی نقل و حرکت میں ڈسپلن کی کمی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ یہاں میں نے پٹھان اسکاؤٹوں کے کچھ گروہ بھی دیکھے، جو اپنی پوشاک، یعنی ڈھیلی شلوارکُرتہ اور پگڑی سے بالکل الگ تھلگ نظر آتے تھے۔ سینوں پر کارتوسوں سے بھری ہوئی چمڑے کی پیٹیاں، کندھوں پر لٹکتی ہوئی بندوقیں اور کمربند میں خنجر۔ ان ہتھیاروں سے لیس جان کی پروا نہ کرنے والے یہ جنگجو، اب حقیقی فوجی ضابطوں کے آہستہ آہستہ پابند ہوتے جا رہے تھے (درحقیقت اس وقت پاکستان کے سرحدی محافظ یہی قبائل پٹھان تھے، جنھوں نے قیامِ پاکستان کے بعد ابتدائی برسوں کے دوران میں انتہائی مؤثر کردارادا کیا)۔
مجھے سیدھے سیکٹر کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل یعقوب خاں کے خیمے میں لے جایا گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے۔ غالباً اس وقت ان کی عمر ۳۵سال ہوگی۔ انھوں نے میرا پُرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے کہا: ’’آپ میرے خیمے ہی میں رہیں گے۔ مجھے امید ہے آپ یہاں خوش رہیں گے‘‘۔ یعقوب خاں ہندستان کی امیرترین اور انتہائی اہم شمال مغربی مسلم ریاست رام پور (جو اَب ہندستان میں ضم ہوچکی ہے) کے موروثی وزیراعظم کے فرزند ہیں۔ وہ بڑے مہذب، دل کش اور خوش مزاج شخص ہیں، اس لیے ہم جلد ہی ایک دوسرے سے بے تکلف ہوگئے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ برسوں گزر جانے اور فاصلوں کے باوجود ابھی تک ہماری دوستی میں فرق نہیں آیا۔ کئی سال بعد وہ جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ پھر وہ سفیرپاکستان کی حیثیت سے واشنگٹن میں تعینات ہوئے اور بالآخر صدر ضیاء الحق نے انھیں حکومت ِ پاکستان کے وزیرخارجہ کا قلم دان سونپا۔
لیفٹیننٹ کرنل یعقوب خاں نے بتایا: ’’میجر جنرل حمید آپ سے فوری ملنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میں آپ کو کل صبح سویرے ان کے ہیڈکوارٹر روانہ کردوں گا‘‘۔ میں نے ان کی تجویز سے اتفاق کیا، کیونکہ اس طرح میں یہاں کے محاذ کی صورت حال کا بھی سرسری جائزہ لے لوں گا۔
رات کا کھانا سادہ، لذیذ اور پُرتکلف تھا۔ دیر تک سگریٹ نوشی اور چائے کے دور چلتے رہے۔ اس کے بعد میں سونے چلاگیا۔ اگلے روز علی الصبح میں تیار ہوگیا۔ سیکڑوں فوجیوں کے ساتھ نمازِ فجر ادا کی۔ یعقوب خاں کے ساتھ ڈبل روٹی، نمکین پنیر اور چائے کا ناشتہ کیااور ان سے عارضی رخصت لے کر اسی جیپ پر اور انھی محافظوں کے ساتھ ہیڈکوارٹر کی جانب روانہ ہوگئے۔
ایک گھنٹہ بعد وہاں پہنچے۔ اس وقت میجر جنرل حمید اپنے افسروں سمیت صوبہ پونچھ کے ایک بڑے نقشے کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے ان کی محویت دیکھ کر ذرا پیچھے ہٹنا چاہا تو انھوں نے مجھے روکتے ہوئے کہا: ’’نہیں، آپ مت جایئے، آپ سے ہماری کوئی رازداری نہیں۔ درحقیقت آج میں آپ کو کچھ اور رازوں سے مطلع کروں گا‘‘۔
اس کے بعد میجر جنرل حمید صاحب نے مجھے اپنی جیپ میں بٹھا لیا اور ہم پونچھ اور ہندستان سے ملحقہ سرحدی علاقے کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر ہماری جیپ شمال کی طرف چلتی رہی۔ چند کلومیٹر کے بعد مغرب کی جانب مڑ گئی اور پھر بڑے سے نصف دائرے میں ذیلی سڑکوں سے ہوتی ہوئی، دوبارہ بڑی سڑک پر آگئی۔ پونچھ کا شہر پیچھے رہ گیا۔ اب نظروں سے بھی اوجھل ہوچکا تھا۔ شاید اس نصف دائرے کے درمیان میں کہیں تھا۔ سڑک پر آمدورفت کم تھی۔ اِدھر اُدھر فوجی ٹولیوں میں سڑک کے کنارے بیٹھے وقت گزار رہے تھے۔ ایک بار مخالف سمت سے آتی ہوئی ایک فوجی گاڑی ہمارے پاس سے گزری۔ دائیں جانب دُور فاصلے پر میں نے ایک گھنا جنگل دیکھا، لیکن وہاں بھی کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آتا تھا۔
یہاں سے آگے بڑھے تو میجر جنرل صاحب نے میری طرف منہ پھیرا اور پوچھا: ’’کیا آپ نے اس جنگل میں کوئی دل چسپ چیز دیکھی؟‘‘ میں نے جواب دیا: ’’کچھ خاص نہیں، صرف درخت ہی تو ہیں‘‘۔
میجر جنرل حمید مسکرائے: ’’آپ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اس چھوٹے سے جنگل میں پاکستان کے توپ خانے کا نصف حصہ چھپا بیٹھا ہے۔ جو سڑک پونچھ اور اس سے آگے جاتی ہے، وہ مکمل طور پر ہماری زد میں ہے اور جب ہم کل حملہ کریں گے، پونچھ میں مقیم ہندستانی فوجوں کا دونوں اطراف سے رابطہ منقطع ہوجائے گا۔ چونکہ ہمارا توپ خانہ ان سے بدرجہا بہتر ہے، اس لیے وہ مزاحمت نہیں کرسکیں گے۔ وقت کی کمی کے باعث انھیں کمک بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ ہم نے اب اپنے تمام فوجی دستوں کو یہاں تعینات کر دیا ہے۔ ان حالات میں ہندستانی فوج ہتھیار ڈال دے گی یا تہس نہس ہوجائے گی۔ اس کے بعد ہم سری نگر کی طرف پیش قدمی کریں گے، ان شاء اللہ۔ ہمارے لیے اب یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے‘‘۔
میجر جنرل حمید کی اس پُرامید گفتگو میں کوئی مبالغہ بھی نہیں تھا۔ جوں ہی ہم واپس ہیڈکوارٹر پہنچے، انھیں ایک شدید دھچکا محسوس ہوا۔ اسی شام افواجِ پاکستان کے کمانڈر انچیف کے توسط سے انھیں وزیراعظم لیاقت علی خاں کا بذریعہ تار ایک خفیہ پیغام موصول ہوا:
’’اگلے روز حملے کا پروگرام منسوخ کردیا جائے‘‘۔
کئی ہفتوں بعد مجھے اصل صورت حال کا علم ہوا۔ ہندستان کی اعلیٰ فوجی کمان کو جونہی پاکستانی فوج کے اس متوقع حملے کا پتا چلا، اس نے فوراً اپنے وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو تمام صورتِ حال اور اس کے مضر اثرات سے آگاہ کردیا۔ پنڈت صاحب نے اسی وقت برطانوی وزیراعظم کلیمنٹ اٹیلی سے فون پر رابطہ قائم کیا اور ان پر زور دیا: ’’پاکستان کو ہرقیمت پر اس حملے سے روکنا ہوگا، کیونکہ اتنے مختصر وقت میں ہندستان کے لیے بذریعہ جہاز پونچھ کمک پہنچانا ممکن نہیں ہے۔ اگر انھیں پاکستانی افواج سے ہزیمت اُٹھانا پڑی تو وہ احتجاجاً دولت مشترکہ کی رکنیت چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے (کہیں اور کا اشارہ اشتراکی روس کی جانب تھا)۔ اگر پاکستان کو اپنا حملہ منسوخ کرنے پر آمادہ کرلیا جائے اور ضلع پونچھ ہندستان ہی کا حصہ رہے تو وہ، یعنی پنڈت صاحب اگلے سال کشمیری عوام کو استصواب رائے کا حق دے دیںگے‘‘۔
تمام رات نئی دہلی اور لندن کے درمیان ٹیلی فون کی تاریں بجتی رہیں۔ وزیراعظم اٹیلی کو ہندستان جیسا بڑا ملک ہاتھ سے نکلتا دکھائی دینے لگا۔ اس نے فوراً لارڈ ماؤنٹ بیٹن (جو ۱۹۴۸ء کے آخر میں ہندستان کے گورنر جنرل کے عہدے سے مستعفی ہوکر اب انگلستان میں اپنی گذشتہ کامیابیوں پر شاداں و فرحاں زندگی گزار رہے تھے) سے مشورہ کیا اور کہا کہ برصغیر کے امورمختلفہ کے تجربہ کار ماہر کی حیثیت سے وہ نہرو کی تشویش دُور کرنے کی کوشش کریں اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنا اثرورسوخ استعمال کریں۔ چند گھنٹوں بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے وزیرخارجہ سر ظفراللہ خاں کو فون کیا اور انھیں بتایا کہ پنڈت صاحب نے کشمیری عوام کو حق رائے دہی کا یقین دلایا ہے اور برطانوی وزیراعظم اٹیلی نے بھی اس حملے کی منسوخی کے لیے ذاتی طور پر درخواست کی ہے۔ اس وقت وزیراعظم لیاقت علی خاں سوئے تھے۔ ظفراللہ نے انھیں جگاکر یہ پیغام پہنچایا اور انھیں اٹیلی کی معروضات پر خصوصی توجہ دینے کی استدعا کی۔
اثر و رسوخ کے ان الجھیڑوں میں وزیرخارجہ سرظفراللہ خاں نے جو کردار ادا کیا، اس کی تفہیم کے لیے ان کی مخصوص وفاداریوں کا مختصراً تذکرہ ضروری ہے۔ وہ جماعت احمدیہ کے سرگرم رکن تھے۔ تمام مسلمان اس جماعت کو دائرۂ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اس جماعت کے بانی قادیان کے مرزا غلام احمد تھے، جو پہلے پہل ایک عالمِ دین کی حیثیت سے مشہور تھے، لیکن بعد میں ان کے ذہن میں یہ خیال جاگزیں ہوگیا: وہ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ یہ ایسا دعویٰ ہے جس کو ہندستان کے تمام مسلمانوں نے چاہے وہ سُنّی ہیں یا شیعہ، قطعی طور پر مسترد کردیا۔ نصِ قرآنی سے یہ بالکل واضح ہے کہ حضور اکرمؐ خاتم الانبیاء ہیں اور ان کے بعد کوئی پیغمبر کرئہ ارض پر مبعوث نہیں ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت اسلام کے بنیادی عقیدے کی نفی ہے، اس لیے وہ اور ان کے پیروکار اسلام کی حدود سے باہر ہیں۔ ہندستان کے برطانوی حکمران، تحریکِ احمدیت کو بڑی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ برسرِاقتدار اسلامی یا غیراسلامی حکومت کی اطاعت اور فرماں برداری کی سخت تاکید کررکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ برطانوی حکومت کے مقتدر اصحاب، جماعت احمدیہ کے اراکین کی ہرطرح سے حمایت کرتے تھے۔ سر ظفراللہ خاں بھی ایک بااثر شخص تھے اور غلام احمد قادیانی سے گہری عقیدت رکھتے تھے، اس لیے وہ تمام عمر انگریزوں سے زیادہ برطانیہ کے خدمت گزار رہے۔
سرظفراللہ خاں باصلاحیت وزیرخارجہ تھے۔ مزید یہ کہ وہ کشمیر میں استصواب رائے کرانے کے بارے میں نہرو کے وعدہ پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ انھیں توقع تھی کہ جس مسئلے نے عرصۂ دراز تک پاکستان کی توانائیوں کو ضائع کردیا ہے، اس کا کوئی مستقل اور پائے دار حل تلاش کیا جاناچاہیے۔ یہی سوچ کر انھوں نے پاکستانی افواج کو پونچھ سے ہٹاکر بین الاقوامی سرحد پر بھجوانے کا حکم دے دیا۔ لیکن یہ خطرہ ٹلتے ہی بھارتی وزیراعظم نہرو فوری استصواب رائے کرانے کے وعدے سے منحرف ہوگیا اور یہ مسئلہ کشمیر غیرمعینہ عرصہ کے لیے معرض التوا میں ڈال دیا گیا۔
یہ اتنا بڑا قومی المیہ تھا کہ جس کی تلافی نہیں ہوسکتی تھی۔ پونچھ میں ہندستانی افواج نے خود کو مضبوط کرلیا، جب کہ پاکستان نے ایک نادر موقع کھو دیا، جو قوموں کی زندگی میں کبھی کبھار آتا ہے۔
وزیراعظم لیاقت علی خاں کا حکم نامہ پونچھ کے گردونواح محاذِ جنگ پر تعینات پاکستانی فوجیوں پہ بم بن کر گرا۔ جب انھیں علم ہوا کہ حملہ منسوخ کردیا گیا ہے، تو وہاں موجود بہت سے افسر اور جوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کشمیر کو ہندوؤں کے تسلط سے آزاد کرانے اور اسے پاکستان کا حصہ بنانے کا انھوں نے جو خواب دیکھا تھا، وہ چکنا چُور ہوگیا۔ کوئی سنجیدہ شخص یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہاں مستقبل بعید میں بھی کبھی کشمیریوں کو موعودہ حق رائے دہی مل جائے گا۔
[اس صدمے کے بعد] میجر جنرل حمید نے خود کو ہیڈ کوارٹر میں بند کرلیا۔ پھر کئی مہینے تک ان سے میری ملاقات نہ ہوسکی۔ اس کے بعد وہ فوج سے مستعفی ہوگئے۔ (مآخذ: محمد اسد، بندۂ صحرائی (خود نوشت سوانح عمری)، مرتب: پولااسد، محمداکرام چغتائی، ناشر: دی ٹروتھ سوسائٹی، ۲-اے،۸۱، گلبرگ III، لاہور۔ فون: 0333-9807767)