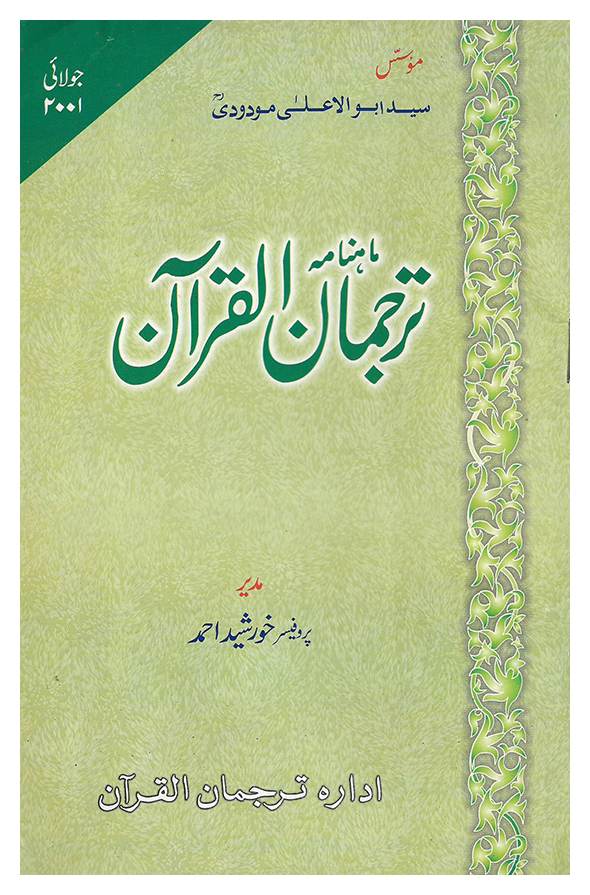
اوّلین چیز جس پر ملک کے تمام مختلف الخیال گروہوں اور اشخاص کو اتفاق کرنا چاہیے‘ وہ صداقت اور باہمی انصاف ہے۔ اختلاف اگر ایمان داری کے ساتھ ہو‘ دلائل کے ساتھ ہو‘ اور اسی حد تک رہے جس حد تک فی الواقع اختلاف ہے‘ تو اکثر حالات میں یہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس طرح مختلف نقطۂ نظر اپنی صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے آجاتے ہیں اور لوگ انھیں دیکھ کر خود رائے قائم کر سکتے ہیں کہ وہ ان میں سے کس کو قبول کریں‘ تاہم اگر وہ مفید نہ ہو تو کم سے کم بات یہ ہے کہ مضر نہیں ہو سکتا۔ لیکن کسی معاشرے کے لیے اس سے بڑھ کر نقصان دہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اُس میں جب بھی کسی کو کسی سے اختلاف ہو تو وہ ’’جنگ میں سب کچھ حلال ہے‘‘ کا ابلیسی اصول اختیار کر کے اُس پر ہر طرح کے جھوٹے الزامات لگائے‘ اُس کی طرف جان بوجھ کر غلط باتیں منسوب کرے‘ اُس کے نقطۂ نظر کو قصداً غلط صورت میں پیش کرے۔ سیاسی اختلاف ہو تو اسے غدار اور دشمنِ وطن ٹھیرائے۔ مذہبی اختلاف ہو تو اس کے پورے دین و ایمان کو مُتَّہَم ]برباد[کر ڈالے‘ اور ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے اس طرح پڑ جائے کہ گویا اب مقصدِ زندگی بس اسی کو نیچا دکھانا رہ گیا ہے۔
اختلاف کا یہ طریقہ نہ صرف اخلاقی لحاظ سے معیوب اور دینی حیثیت سے گناہ ہے‘ بلکہ عملاً بھی اس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی بدولت معاشرے کے مختلف عناصر میں باہمی عداوتیں پرورش پاتی ہیں۔ اس سے عوام دھوکے اور فریب میں مبتلا ہوتے ہیں اور اختلافی مسائل میں کوئی صحیح رائے قائم نہیں کرسکتے۔ اس سے معاشرے کی فضا میں تکدّر پیدا ہو جاتا ہے جو تعاون و مفاہمت کے لیے نہیں بلکہ صرف تصادم و مزاحمت ہی کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ اس میں کسی شخص یا گروہ کے لیے عارضی منفعت کا کوئی پہلو ہو تو ہو‘ مگر بحیثیت مجموعی پوری قوم کا نقصان ہے جس سے بالآخر خود وہ لوگ بھی نہیں بچ سکتے جو اختلاف کے اس بے ہودہ طریقے کو مفید سمجھ کر اختیار کرتے ہیں۔ بھلائی اسی میں ہے کہ ہمیں کسی سے خواہ کیسا ہی اختلاف ہو‘ ہم صداقت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اس کے ساتھ ویسا ہی انصاف کریں جیسا ہم خود اپنے لیے چاہتے ہیں۔
دوسری چیز جو اتنی ہی ضروری ہے‘ اختلافات میں رواداری ‘ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش‘ اور دوسروں کے حق رائے کو تسلیم کرنا ہے۔ کسی کا اپنی رائے کو حق سمجھنا اور عزیز رکھنا تو ایک فطری بات ہے‘ لیکن رائے رکھنے کے جملہ حقوق اپنے ہی لیے محفوظ کر لینا‘ انفرادیت کا وہ مبالغہ ہے جو اجتماعی زندگی میں کبھی نہیں نبھ سکتا۔ پھر اس پر مزید خرابی اس مفروضے سے پیدا ہوتی ہے کہ ’’ہماری رائے سے مختلف کوئی رائے ایمان داری کے ساتھ قائم نہیں کی جا سکتی‘ لہٰذا جو بھی کوئی دوسری رائے رکھتا ہے وہ لازماً بے ایمان اور بدنیت ہے‘‘۔ یہ چیز معاشرے میں ایک عام بدگمانی کی فضا پیدا کر دیتی ہے‘ اختلاف کو مخالفتوں میں تبدیل کر دیتی ہے‘ اور معاشرے کے مختلف عناصر کو جنھیں بہرحال ایک ہی جگہ رہنا ہے‘ اس قابل نہیں رہنے دیتی کہ وہ ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھ کر کسی مفاہمت و مصالحت پر پہنچ سکیں۔ اس کا نتیجہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہ کہ ایک مدّتِ دراز تک معاشرے کے عناصر ترکیبی آپس کی کش مکش میں مبتلا رہیں اور اس وقت تک کوئی تعمیری کام نہ ہو سکے جب تک کوئی ایک عنصر باقی سب کو ختم نہ کر دے‘ یا پھر سب لڑ لڑ کر ختم ہو جائیں اور خدا کسی دوسری قوم کو تعمیر کی خدمت سونپ دے۔
بدقسمتی سے ناروا داری اور بدگمانی اور خود پسندی کا یہ مرض ہمارے ملک میں ایک وباے عام کی صورت اختیار کر چکا ہے جس سے بہت ہی کم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ حکومت اور اس کے اربابِ اقتدار اس میں مبتلا ہیں۔ سیاسی پارٹیاں اس میں مبتلا ہیں۔ مذہبی گروہ اس میں مبتلا ہیں۔اخبار نویس اس میں مبتلا ہیں۔ حتیٰ کہ بستیوں اور محلوں اور دیہات کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں تک اس کے زہریلے اثرات اتر گئے ہیں۔ اس کا مداوا صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگ جو اپنے اپنے حلقوں میں نفوذ و اثر رکھتے ہیں‘ اپنی ذہنیت تبدیل کریں اور خود اپنے طرزِعمل سے اپنے زیراثر لوگوں کو تحمل و برداشت اور وسعتِ ظرف کا سبق دیں۔
تیسری چیز جسے تمام اُن لوگوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو اجتماعی زندگی کے کسی شعبے میں کام کرتے ہوں‘ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی قوتیں دوسروں کی تردید میں صرف کرنے کے بجائے اپنی مثبت چیز پیش کرنے پر صرف کرے۔ اس میں شک نہیں کہ بسااوقات کسی چیز کے اثبات کے لیے اس کے غیر کی نفی ناگزیر ہوتی ہے‘ مگر اس نفی کو اسی حد تک رہنا چاہیے جس حد تک وہ ناگزیرہو‘ اور اصل کام اثبات ہونا چاہیے نہ کہ نفی۔ افسوس ہے کہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یہاں زیادہ تر زور اس بات پر صرف کیا جاتا ہے کہ دوسرے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی مذمت کی جائے اور اس کے متعلق لوگوں کی رائے خراب کر دی جائے۔ بعض لوگ تو اس منفی کام سے آگے بڑھ کر سرے سے کوئی مثبت کام کرتے ہی نہیں‘ اور کچھ دوسرے لوگ اپنے مثبت کام کے فروغ کا انحصار اس پر سمجھتے ہیں کہ میدان میں ہر دوسرا شخص جو موجود ہے اُس کی اور اس کے کام کی پہلے مکمل نفی ہوجائے۔ یہ ایک نہایت غلط طریق کار ہے اور اس سے بڑی قباحتیں رونما ہوتی ہیں۔ اس سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے تعصبات اُبھرتے ہیں۔ اس سے عام بے اعتباری پیدا ہو جاتی ہے‘ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے عوام کو تعمیری طرز پر سوچنے کے بجائے تخریبی طرز پر سوچنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔
یہ روش خصوصیت کے ساتھ موجودہ حالت میں تو ہمارے ملک کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس وقت ہماری قومی زندگی میں ایک بڑا خلا پایا جاتا ہے جو ایک قیادت پر سے عوام کا اعتماد اٹھ جانے اور دوسری کسی قیادت پر نہ جمنے کا نتیجہ ہے۔ اس خلا کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مختلف جماعتیں اپنا جو کچھ اور جیسا کچھ بھی مثبت کام اور پروگرام رکھتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کو یہ سمجھنے کا موقع ملے کہ کون کیا کچھ بنا رہا ہے‘ کیا کچھ بنانا چاہتا ہے‘ اور کس کے ہاتھوں کیا کچھ بننے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہی چیز آخرکار ایک یا چند جماعتوں پر قوم کو مجتمع کر سکے گی اور اجتماعی طاقت سے کوئی تعمیری کام ممکن ہوگا۔ لیکن اگر صورت حال یہ رہے کہ ہر ایک اپنا اعتماد قائم کرنے کے بجائے دوسروں کا اعتمادختم کرنے میں لگا رہے تو نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگاکہ کسی کا اعتماد بھی قائم نہ ہو سکے گا اور ساری قوم بن سری ہو کر رہ جائے گی۔
ایک اور بات جسے ایک قاعدئہ کلیہ کی حیثیت سے سب کو مان لینا چاہیے‘ یہ ہے کہ اپنی مرضی دوسروں پر زبردستی مسلّط کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اپنی بات دوسروں سے منوانا چاہتا ہو وہ جبر سے نہیں بلکہ دلائل سے منوائے‘ اور جو کوئی اپنی کسی تجویز کو اجتماعی پیمانے پر نافذ کرنا چاہتا ہو وہ بزور نافذ کرنے کے بجائے ترغیب و تلقین سے لوگوں کو راضی کرکے نافذ کرے۔ محض یہ بات کہ ایک شخص کسی چیز کو حق سمجھتا ہے یا ملک و ملّت کے لیے مفید خیال کرتا ہے‘ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ اُٹھے اور زبردستی اس کو لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش شروع کر دے۔ اس طریق کار کا لازمی نتیجہ کش مکش‘ مزاحمت اور بدمزگی ہے۔ ایسے طریقوں سے ایک چیز مسلط تو ہو سکتی ہے مگر کامیاب نہیں ہو سکتی‘ کیونکہ کامیابی کے لیے لوگوں کی قبولیت اور دلی رضامندی ضروری ہے۔ جن لوگوں کو کسی نوع کی طاقت حاصل ہوتی ہے‘ خواہ وہ حکومت کی طاقت ہو یا مال و دولت کی یا نفوذ و اثر کی‘ وہ بالعموم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انھیں اپنی بات منوانے اور اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رضاے عام کے حصول کا لمبا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے‘بس طاقت کا استعمال کافی ہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایسی ہی زبردستیوں نے بالآخر قوموں کا مزاج بگاڑ دیا ہے‘ ملکوں کے نظام تہ و بالا کر دیے ہیں‘ اور ان کو پرُامن ارتقا کے راستے سے ہٹا کر بے تکے تغیرات و انقلابات کے راستے پر ڈال دیا ہے۔
پاکستان کے بااثر لوگ اگر واقعی اپنے ملک کے خیرخواہ ہیں تو انھیں دھونس کے بجائے دلیل اور جبر کے ساتھ ترغیب سے کام لینے کی عادت ڈالنی چاہیے‘ اور اسی طرح پاکستان کے عام باشندے بھی اگر اپنے بدخواہ نہیں ہیں تو انھیں اس بات پر متفق ہو جانا چاہیے کہ وہ یہاں کسی کی دھونس اور زبردستی کو نہ چلنے دیں گے۔
اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی عصبیتوں کو ختم کر کے مجموعی طور پر پورے ملک اور ملّت کی بھلائی کے نقطۂ نظر سے سوچنے کا خوگر ہوناچاہیے۔ ایک مذہبی فرقے کے لوگوں کا اپنے ہم خیال لوگوں سے مانوس ہونا‘ یا ایک زبان بولنے والوں کا اپنے ہم زبانوں سے قریب تر ہونا‘ یا ایک علاقے کے لوگوں کا اپنے علاقے والوں سے دل چسپی رکھنا تو ایک فطری بات ہے۔ اس کی نہ کسی طرح مذمت کی جا سکتی ہے اور نہ اس کا مٹ جانا کسی درجے میں مطلوب ہے۔ مگر جب اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے گروہ اپنی محدود دل چسپیوں کی بنا پر تعصب اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے گروہی مفاد یا مقاصد کے لیے معرکہ آرائی پر اُتر آتے ہیں تو یہ چیز ملک اور ملّت کے لیے سخت نقصان دہ بن جاتی ہے۔ اس کو اگر نہ روکا جائے تو ملک پارہ پارہ ہو جائے اور ملّت کا شیرازہ بکھر جائے جس کے برے نتائج سے خود یہ گروہ بھی نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جس فرقے‘ قبیلے‘ نسل ‘ زبان یا صوبے سے بھی اس کا تعلق ہو اُس کے ساتھ اُس کی دل چسپی اپنی فطری حد سے تجاوز نہ کرنے پائے۔ یہ دل چسپی جب بھی تعصب کی شکل اختیار کرے گی‘ تباہ کن ثابت ہوگی۔ ہر تعصب لازماً جواب میں ایک دوسرا تعصب پیدا کر دیتا ہے‘ اور تعصب کے مقابلے میں تعصب کش مکش پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر بھلا اُس قوم کی خیر کیسے ہو سکتی ہے جس کے اجزاے ترکیبی آپس ہی میں برسرِپیکار ہوں۔
سیاسی جماعتوں کا مطلوبہ کردار: ایسا ہی معاملہ سیاسی پارٹیوں کا بھی ہے۔ کسی ملک میں اس طرح کی پارٹیوں کا وجود اگر جائز ہے تو صرف اس بنا پر کہ ملک کی بھلائی کے لیے جو لوگ ایک خاص نظریہ اور لائحۂ عمل رکھتے ہوں انھیں منظم ہو کر اپنے طریقے پر کام کرنے کا حق ہے۔ لیکن یہ حق دو ضروری شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فی الواقع نیک نیتی کے ساتھ ’’ملک کی بھلائی‘‘ ہی کے لیے خواہاں اور کوشاں ہوں۔ اور دوسری شرط یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مسابقت یا مصالحت اصولی ہو اور معقول اور پاکیزہ طریقوں تک محدود رہے۔ ان میں سے جو شرط بھی مفقود ہوگی اُس کا فقدان پارٹیوں کے وجود کو ملک کے لیے مصیبت بنا دے گا۔ اگر ایک پارٹی اپنے مفاد اور اپنے چلانے والوں کے مفاد ہی کو اپنی سعی و جہد کا مرکز و محور بنا بیٹھے اور اس فکر میں ملک کے مفاد کی پروا نہ کرے تو وہ سیاسی پارٹی نہیں بلکہ قزاقوں کی ٹولی ہے۔ اور اگر مختلف پارٹیاں مسابقت میں ہر طرح کے جائز و ناجائز ہتھکنڈے استعمال کرنے لگیں اور مصالحت کسی اصول پر کرنے کے بجائے اختیار و اقتدار کے بٹوارے کی خاطر کیا کریں تو ان کی جنگ بھی ملک کے لیے تباہ کن ہوگی اور صلح بھی۔
یہ پانچ اصول تو وہ ہیں جن کی پابندی اگر ملک کے تمام عناصر قبول نہ کر لیں تو یہاں سرے سے وہ فضا ہی پیدا نہیں ہو سکتی جس میں نظامِ زندگی کی بنیادوں پر اتفاق ممکن ہو ‘ یا بالفرض اس طرح کا کوئی اتفاق مصنوعی طور پر واقع ہو بھی جائے تو وہ عملاً کوئی مفید نتیجہ پیدا کر سکے۔ اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں جن پر ایک صحیح مصالحانہ فضا میں زیادہ سے زیادہ اتفاق کے ساتھ ملک کا نظامِ زندگی تعمیر کیا جا سکتا ہے۔
ان میں ]اہم ترین بنیاد[ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ملک کے آیندہ نظام کے لیے منبع ہدایت اور اوّلین مآخذ قانون تسلیم کیا جائے۔ اس کو بنیادِ اتفاق ہم اس لیے قرار دیتے ہیں کہ ملک کی آبادی کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے اور وہ اس بنیاد کے سوا کسی اور چیز پر راضی اور مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اُن کا عقیدہ اس کا تقاضا کرتا ہے۔ ان کی تہذیب اور قومی روایات اس کا تقاضا کرتی ہیں‘ اور ان کی ماضی قریب کی تاریخ بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ ان کے لیے یہ گوارا کرنا سخت مشکل بلکہ محال ہے کہ جس خدا اور جس رسول پر وہ ایمان رکھتے ہیں‘ اس کے احکام سے وہ جان بوجھ کر منہ موڑ لیں اور اس کی ہدایات کے خلاف دوسرے طریقے اور قوانین خود اپنے اختیار سے جاری کریں۔ وہ کبھی اُن طریقوں کو جاری کرنے میں سچے دل سے تعاون نہیں کر سکتے اور نہ اُن قوانین کی برضا ورغبت پیروی کر سکتے ہیں جن کو وہ عقیدۃً باطل اور غلط سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر آزادی کا جذبہ جس چیز نے بھڑکایا اور جس چیز کی خاطر انھوں نے جان و مال اور آبرو کی ہولناک قربانیاں دیں وہ صرف یہ تھی کہ انھیں غیر اسلامی نظام زندگی کے تحت جینا گوارا نہ تھا اور وہ اسے اسلامی نظام زندگی سے بدلنا چاہتے تھے۔ اب ان سے یہ توقع کرنا بالکل بے جا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ بہ خوشی اُس اصل مقصد ہی سے دست بردار ہو جائیں گے جس کے لیے انھوں نے اتنی گراں قیمت پر آزادی خریدی ہے۔ بلاشبہ یہ ضرور ممکن ہے کہ اگر کوئی جابر طاقت زبردستی ان کے اس مقصد کے حصول میں مانع ہو جائے اور اُن پر اسلام کے سوا کوئی دوسرا ضابطہ ء حیات مسلط کر دے تو وہ اُسی طرح مجبوری کے ساتھ اسے برداشت کر لیں جس طرح انگریزی تسلط واقع ہو جانے کے بعد انھوں نے اسے برداشت کیا تھا‘ لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ ایک نارضامند آبادی پر جبر سے ایک نظام مسلط کرکے اسے کامیابی کے ساتھ چلایا بھی جا سکتا ہے وہ یقینا سخت نادان ہے۔
(ترجمان القرآن‘ جولائی ۱۹۵۵ء)