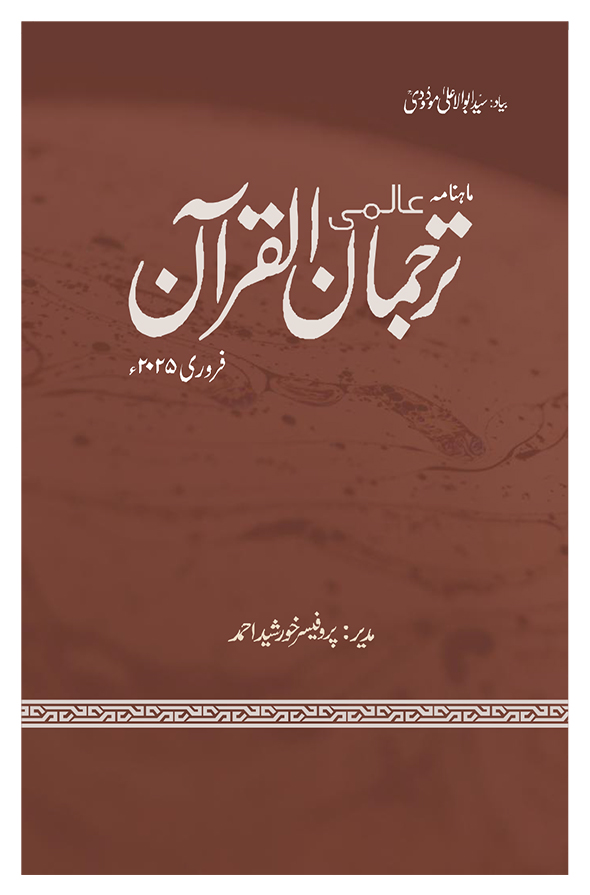
’پرانے یہودیوں‘ (اسرائیل) کے حصے میں تاریخ کی لعنت وملامت آئی، اور دوسری طرف ’نئے یہودیوں‘ (انڈیا) کے لیے تاریخ کا تازیانہ تیار ہے۔ آج ظالموں کے خلاف فلسطینی عوام کی فداکاریوں کے تذکرے عام ہیں آسمانوں میں، تو دوسرے ظالموں کے خلاف ایک لاکھ سے زیادہ کشمیری مظلوموں کا خون عالمی ضمیر کی عدالت میں سراپا سوال ہے۔ تقسیم ِہند کے نامکمل ایجنڈے کا یہ باب ۱۹۴۷ء سے آج ۲۰۲۵ء تک حل طلب ہے۔
سقوط مشرقی پاکستان (۱۶دسمبر۱۹۷۱ء)سے پہلے بھی وہاں نوجوانوں کو ہم سمجھاتے رہے، جھنجھوڑتے اور پکارتے رہے کہ’ ’ہمدردی کے زہر میں لپٹی دشمن کی یہ سرپرستی درحقیقت غلامی کا شکنجہ ہے۔ یہاں گھر میں اپنے بھائیوں سے لڑ جھگڑ کر حقوق لیے جا سکتے ہیں، لیکن دشمن کی نام نہاد ہمدردی کے نام پر حاصل کردہ غلامی سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو گا۔‘‘ اور آج صورت حال یہ ہے کہ نفرت کا الائو بھڑکانے والے نام نہاد آزادی کے علم بردار مجیب اور ان کی بیٹی حسینہ واجد کے ہاتھوں، اسی سابقہ مشرقی پاکستان اور حالیہ بنگلہ دیش کا بال بال غلامی کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ حکومت تو تبدیل کر لی گئی ہے، لیکن معاشی، تہذیبی، سیاسی، جغرافیائی اور دفاعی آزادی کے حصول کے لیے بنگلہ دیشی بھائیوں کو ابھی کئی دریا عبور کرنے ہوں گے۔ ۱۹۷۱ء میں پاکستانی فریم ورک میں حقوق کا حصول دوچار سال میں ممکن نظر آتا تھا، لیکن اب نصف صدی بھسم کرنے کے بعد بھی بے بسی کا نیا شکنجہ، وہاں کے قومی وجود کو گرفت میں لیے سب کے سامنے ہے۔
وہ نوجوان جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہیں، یا آزاد کشمیر اور بیرون پاک و ہند میں ہیں، انھیں خوب اچھی طرح یہ بات جان لینی چاہیے کہ ’خود مختار کشمیر‘ انڈیا کی دوسری دفاعی لائن ہے، بنگلہ دیش سے بھی زیادہ بے بس سیاسی وجود۔ انڈیا کے پالیسی سازوں کی یہ پوری کوشش رہی ہے کہ استصواب رائے (Plebiscite) نہ ہو، اور اگر بظاہر پیچھے ہٹنا پڑے تو ثالثی یا سودا بازی کرکے پورے کشمیر کو ’خودمختار‘ کا درجہ دیتے ہوئے، اپنی ایک باج گذار گماشتہ ریاست بنا لیا جائے، جیسے بھوٹان وغیرہ۔ اسی لیے بڑی تیزی سے مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی نظام پر دن رات کام کیا جا رہا ہے، اور آبادی کا تناسب بڑی تیزی سے بگاڑا جا رہا ہے۔
اس پس منظر میں ہم دعوت دیتے ہیں کہ نئی نسل ہوش کا دامن تھام کر، دشمن سے ملنے والی چمک کو روشنی نہیں بلکہ ظلمت کی سیاہی سمجھ کر جان ومال اور صلاحیت لگائے۔ جو مسائل ہیں، انھیں پاکستانی فریم ورک میں حل کرنا آسان بھی ہوگا اور فطری ومعقول بھی۔ کسی چیز میں کمی بیشی ممکن ہے، لیکن بہرحال پاکستان ہی نے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیا، جب کہ دشمن نے ۱۹۴۷ء سے پہلے اور ۱۹۴۷ء کے بعد بھی جان ومال کی قربانی لی ہے۔ اس لیے دور اندیشی اور سمجھ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بنگلہ دیش کے تجربے سے سبق سیکھیں اور اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق استصواب رائے کے طے شدہ فارمولے ہی پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔
یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آزاد کشمیر حکومت، محض آزاد علاقے کی حکومت نہیں ہے، بلکہ پورے جموں و کشمیر کی آزاد حکومت ہے، بدقسمتی سے جو اپنا کردار ادا کرنے میں بُری طرح ناکام رہی ہے۔ اس کی منصبی ذمہ داریوں کا ادراک اور اس کے اصل کردار کا احیا وقت کی ضرورت ہے۔
آزاد کشمیر میں خواندگی کی سطح، پاکستان کے کسی بھی صوبے سے بلند تر ہے۔ مگر حکومت آزاد کشمیر کی بے سمتی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان پڑھے لکھے لوگوں میں اپنے محکوم کشمیری بھائیوں کے لیے دکھ درد کے احساس کی وہ کسک ایک تحریک کی صورت میں دکھائی نہیں دیتی، کہ جو یہاں پیدا ہونی چاہیے تھی، اور اسے مجبور بھائیوں کی آواز بن جانا چاہیے تھا۔
پھر آزاد کشمیر حکومت نے کم و بیش ایسا رویہ اختیار کیا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تعمیر و ترقی اور عوامی فلاح کے پروگراموں کو پروان چڑھانے کے لیے شب و روز کوششیں کرنے کے بجائے ذاتی اور گروہی مفاد کو زندگی کی کامیابی سمجھ لیا ہے۔ اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کشمیری اہلِ اقتدار کو اپنا طرز عمل بدلنا چاہیے اور یہ جو وقفے وقفے سے یہاں پر بظاہر چند مطالبات کے لیے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی اصل بنیاد کو سمجھنا اور اس کے حل کے لیے بامعنی کوششیں کرنی چاہئیں۔ محض نوجوانوں کی پکڑدھکڑ، حکومت آزاد کشمیر کی بے عملی کا جواب نہیں۔ ایسا مریضانہ رویہ دشمن کے مقاصد پورا کرنے کے لیے زرخیز زمین تیار کرتا ہے اور قومی مفاد کو بربادی کی تصویر بنانا ہے۔
تاریخ میں بہت زیادہ دور جانے کے بجائے ہم اس المیے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، جس نے بعض ا وقات کھلنڈرے پن سے مسئلہ کشمیر اور جدوجہدِ آزادی کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ جس طرح کہ مطلق العنان حاکم جنرل پرویز مشرف نے کشمیر میں ۷۶۷کلومیٹر طویل کنٹرول لائن پر باڑ لگانے کے لیے انڈیا کو یک طرفہ سہولت دی۔ انڈیا نے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان بجلی سے لیس خاردار تاروں کی باڑ نصب کرکے اس میں بجلی کی ہائی وولٹیج رو دوڑائی ہے، ساتھ ساتھ باردوی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، اور جس جگہ باڑ نہیں لگ سکتی، وہاں پر لیزر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس باڑ کو لگانے کی اجازت دینے کا کوئی جواز نہیں تھا کہ بطور سرحد اسے دونوں ملک تسلیم نہیں کرتے، مگر یک طرفہ انڈیا کو سہولت دینا کسی بھی اصول اور قاعدے کے مطابق معقول حرکت نہیں تھی۔ پھر انھوں نے ’آؤٹ آف باکس‘ مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ حالانکہ پاکستان کے کسی بھی حکمران کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کشمیر کے عوام کو نظرانداز کرکے کوئی ایسا قدم اُٹھائے، جو ہمارے اصولی اور بین الاقوامی طے شدہ موقف سے ٹکراتا ہو۔
اسی طرح فروری ۲۰۲۱ء میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے اچانک فوجی کمانڈروں کی سطح پر مذاکرات کیے۔ پھر دو ماہ بعد چند صحافیوں کو کھانے پر بلا کر یہ کہا: ’’ہم بیک ڈور مذاکرات کر رہے ہیں۔ ہمیں ماضی بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے‘‘۔ ان چیزوں کو ’باجوہ ڈاکٹرائن‘ بھی کہنا شروع کیا۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جن سے حکومت اور قوم دونوں بے خبر تھے۔ان اقدامات نے پاکستان کے دفاعی دبدبے (deterrence) کو سخت نقصان پہنچایا اور دشمن کے حوصلے بلند کیے اور اپنے حقِ خودارادیت کے لیے کوشاں تمام متعلقہ حلقوں کو مایوس کیا۔ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی سوچ کی برملا اور واضح الفاظ میں نفی کی جانی چاہیے، تاریخ اور قوم کے موقف کو روندنے کے ہرعمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔
۵؍اگست۲۰۱۹ء کو انڈیا کی جانب سے آرٹیکل ۳۷۰اور ۳۵-اے کی یک طرفہ منسوخی کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں حالات نے تیزی سے پلٹا کھایا۔ ’نسل پرست ہندوتوا‘ نے اپنی سرپرست آرایس ایس کی نگرانی میں یہ قدم کسی الگ تھلگ عمل کے لیے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اس کے ساتھ باقاعدہ سلسلہ وار اقدامات اُٹھائے جارہے ہیں۔ جن کے مطابق:
اس صورت حال میں حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام پر لازم ہے کہ آزمائش کی اس گھڑی میں وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے مظلوم بھائیوں کو یاد رکھتے ہوئے:
اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو وقت تیزی سے گزرتا جائے گا اور کشمیر دوسرا اسپین بن کر رہ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان، یہاں کے اہل حل و عقد اور خردمند اس المیے کا کردار بننا چاہتے ہیں؟
قرآن مزدوروں یا کاشت کاروں یا کارخانہ داروں کو نہیں پکارتا بلکہ انسانوں کو پکارتا ہے۔ اس کا خطاب انسان سے بحیثیت انسان ہے اور وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے سوا کسی کی بندگی، اطاعت، فرماں برداری کرتے ہو تو اسے چھوڑدو، اور اگر خود تمھارے اندر خدائی کا داعیہ ہے تو اُسے بھی چھوڑ دو کہ دوسروں سے اپنی بندگی کرانے اور دوسروں کا سر اپنے آگے جھکوانے کا حق بھی تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تم سب کو ایک خدا کی بندگی قبول کرنی چاہیے اور اس بندگی میں سب کو ایک سطح پر آجانا چاہیے:
آئو ہم اور تم ایک ایسی بات پر جمع ہوجائیں جو ہمارے اور تمھارے درمیان یکساں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور خداوندی میں کسی کو خدا کا شریک بھی نہ ٹھیرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے بجائے امرونہی کا مالک بھی نہ بنائے۔ (اٰل عمرٰن۳:۶۴)
یہ عالم گیر اور کُلی انقلاب کی دعوت ہے۔ قرآن نے پکار کر کہا ہے کہ اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلّٰہِ ط (الانعام ۶:۵۷) ’’حکومت سوائے خدا اور کسی کی نہیں ہے‘‘۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بذاتِ خود انسانوں کا حکمران بن جائے اور اپنے اختیار سے جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے روک دے۔ کسی انسان کو بالذات امرونہی کا مالک سمجھنا دراصل خدائی میں اسے شریک کرنا ہے اور یہی بنائے فساد ہے۔ اللہ نے انسان کو جس صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے اور زندگی بسر کرنے کا جوسیدھا راستہ بتایا ہے، اُس سے انسان کے ہٹنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ خدا کو بھول جائیں اور نتیجتاً خود اپنی حقیقت کو بھی فراموش کردیں۔ اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف بعض اشخاص یا خاندان یا طبقے خدائی کا کھلا یا چھپا داعیہ لے کر اُٹھتے ہیں اور اپنی طاقت سے ناجائز فائدہ اُٹھا کر لوگوں کو اپنا بندہ بنالیتے ہیں۔ دوسری طرف اس خدافراموشی اور خود فراموشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک حصہ ان طاقتوروں کی خدائی مان لیتا ہے اور ان کے اس حق کو تسلیم کرلیتا ہے کہ یہ حکم کریں اور وہ اس حکم کے آگے سر جھکا دیں۔ یہی دُنیا میں ظلم و فساد اور ناجائز انتفاع کی بنیاد ہے۔ قرآن پہلی ضرب اسی پر لگاتا ہے۔ وہ ہانکے پکارے کہتا ہے:
وہ لوگوں سے پوچھتا ہے: ءَ اَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَیْرٌ اَمِ اللہُ الْوَاحِدُ الْقَہَّارُ۳۹ۭ (یوسف ۱۲: ۳۹)، یعنی یہ بہت سے چھوٹے بڑے خدا جن کی بندگی میں تم پسے جارہے ہو، اِن کی بندگی قبول ہے یا اُس خدائے واحد کی جو سب سے زبردست ہے؟ اگر اس خدائے واحد کی بندگی قبول نہ کرو گے تو ان چھوٹے اور جھوٹے خدائوں کی آقائی سے تمھیں کبھی نجات نہ مل سکے گی، یہ کسی نہ کسی طور سے تم پر تسلط پائیں گے اور فساد برپا کرکے رہیں گے:
اسلام کی دعوتِ توحید و خدا پرستی محض اس معنی میں ایک مذہبی عقیدے کی دعوت نہ تھی جس میں اور دوسرے مذہبی عقائد کی دعوت ہوا کرتی ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ایک اجتماعی انقلاب کی دعوت تھی۔ اس کی ضرب بلاواسطہ ان طبقوں پر پڑتی تھی جنھوں نے مذہبی رنگ میں پروہت بن کر، یا سیاسی رنگ میں بادشاہ بن کر اور رئیس اور حکمران گروہ بن کر، یا معاشی رنگ میں مہاجن اور زمیندار اور اجارہ دار بن کر عامۃ الناس کو اپنا بندہ بنا لیا تھا۔ یہ کہیں علانیہ ارباب من دون اللہ بنے ہوئے تھے۔ دُنیا سے اپنے پیدائشی یا طبقاتی حقوق کی بنیاد پر اطاعت و بندگی کا مطالبہ کرتے تھے اور صاف کہتے تھے کہ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَيْرِيْ۰ۚ (القصص ۲۸:۳۸) (میں تو اپنے سوا تمھارے کسی خدا کو نہیں جانتا)، اور اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى۲۴ۡۖ (النازعات ۷۹:۲۴) (میں تمھارا سب سے بڑا ربّ ہوں)، اور اَنَا اُحْیِ وَاُمِیْتُ (البقرہ ۲:۲۵۸) (زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے)، اور مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّۃً ط (حم السجدہ ۴۱:۱۵) (کون ہے ہم سے زیادہ زورآور؟)، اور کسی جگہ اُنھوں نے عامۃ الناس کی جہالت کو استعمال کرنے کے لیے بتوں اور ہیکلوں کی شکل میں مصنوعی خدا بنا رکھے تھے جن کی آڑ پکڑ کر یہ اپنے خداوندی حقوق بندگانِ خدا سے تسلیم کراتے تھے۔ پس کفروشرک اور بُت پرستی کے خلاف قرآن کی دعوت اور خدائے واحد کی بندگی و عبودیت کے لیے قرآن کی تبلیغ براہِ راست حکومت اور اس کو سہارا دینے والوں یا اُس کے سہارے چلنے والے طبقوں کی اغراض سے متصادم ہوتی تھی۔ اس وجہ سے جب کبھی کسی نبی ؑ نے يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللہَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَيْرُہٗ۰ۭ (الاعراف۷:۵۹)کی صدا بلند کی ، کہ اے برادرانِ قوم، اللہ کی بندگی کرو، اُس کے سوا تمھارا کوئی خدا نہیں ہے، تو حکومت ِ وقت فوراً اس کے مقابلے میں آن کھڑی ہوئی اور تمام ناجائز انتفاع کرنے والے طبقے اس کی مخالفت پر کمربستہ ہوگئے کیونکہ یہ محض ایک مابعد الطبیعی قضیہ کا بیان نہ تھا بلکہ ایک اجتماعی انقلاب کا اعلان تھا۔
اسلام نے مال کو خیر سے تعبیر کیا ہے۔ دنیوی ضروریات ہو ں یا دینی ضروریات سب کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے جائز طریقوں سے مال حاصل کرنے کی نہ صرف تحسین کی گئی ہے بلکہ اس کو ایک فریضہ قراردیا گیا ہے کیونکہ فقروافلاس بندے کو بہت سے ناگوار کاموں یہاں تک کہ کفر تک کرنے پر مجبورکردیتا ہے۔صاحب ِمال ہونا بندے کو بہت سے اچھے کاموں کے قابل بنا دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا ہے:’’ مال مومن کی ڈھال ہے‘‘۔(مشکوٰۃ المصابیح)
lکسبِ حلال کی اہمیت: اسلام نے کسب ِحلال کی بڑی تاکیدکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: مَنْ أَكلَ طَیِّبًا وَ عَمِلَ فِی سُنَّــةٍ وَ أَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (ترمذی )’’جو حلال کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہیں ،وہ جنت میں داخل ہوگا‘‘۔
اللہ تعالیٰ نے صرف حلال رزق کھانے کا حکم دیاہے ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: يٰٓاَيُّہَا النَّاسُ كُلُوْا مِـمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ (البقرۃ ۲: ۱۶۸)’’اے لوگو! زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں، انھیں کھاؤ‘‘۔
رزقِ حلال کی اہمیت کے پیش نظر رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ِ گرامی ہے:طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَا لِ فَرِیْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِیْضَةِ (المعجم الکبیر)’’رزقِ حلال طلب کرنا فرض (عبادت)کے بعد فرض ہے‘‘۔
حلال روزی کمانے کے بہت سے طریقے ہیں جن میں تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور ملازمت وغیرہ شامل ہے۔ہاتھ کی کمائی کو بہترین کمائی کا درجہ دیا گیا ہے ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:’’کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کمائی کا کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے‘‘۔(صحیح البخاری)
کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے افضل کمائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاکہ:’’ تجارت جس میں رب کی نافرمانی کے طریقے نہ اختیار کیے جائیں اوراپنے ہاتھ سے کام کرنا‘‘۔(مسند احمد)
خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تجارت بھی کی اور قریش کی بکریاں چراکرمحنت مزدوری بھی کی۔ آپؐ نے حلال روزی کی اہمیت کے بارے میں فرمایا:’’جس نے مانگنے سے بچنے کے لیے ، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا طلب کی وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی مانند ہوگا‘‘۔(شعب الایمان )
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔صحابہؓ نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی لے رہاہے تو انھوں نے آپؐ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ! اگر اس کی یہ دوڑدھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنااچھا ہوتا۔جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:’’ اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑدھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ ہی میں شمار ہوگی، اور اگر بوڑھے والدین کی پرورش کے لیے کوشش کر رہاہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی، او راگر اپنی ذات کے لیے کوشش کررہاہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی، البتہ اگر اس کی محبت زیادہ مال حاصل کرکے لوگوں پربرتری جتانے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو یہ ساری محنت شیطان کی راہ میں شمارہوگی‘‘۔(الترغیب والترہیب)
lرزقِ حرام اور قبولیتِ دُعا:حرام خور کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:’’بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزیں ہی قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ پھر آپؐ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے طویل سفر طے کیا تھا اور اس کے بال اور چہرہ غبار آلود ہوگئے تھے، اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا : اے ربّ ! اے ربّ! حالانکہ اس کا کھانا حرام ، اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام ہے اور وہ حرام مال سے ہی پرورش پاتا رہا تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟‘‘(صحیح مسلم)
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ:’’قیامت کے دن بندے کے قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے پوچھا نہیں جائے گاکہ:کہ عمر کن کاموں میں گزاری؟اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟اور اپنے جسم کو کن کاموں میں گھلایا؟‘‘(سنن ترمذی)
برکت سے مراد دولت کی مقدار میں اضافہ نہیں ہے ، بلکہ دولت کا صحیح جگہ استعمال ہونا اور تھوڑی آمدنی میں ضرورت پوری ہوجانا ہے۔ یہ سب مال کی برکت ہے ، جو اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی کی وجہ سے عطا کرتا ہے ۔ بہت سے امیرلوگوں کی دولت بیماریوں اور ہسپتالوںمیں، کچھ ناجائز مقدمات کی پیروی میں، کچھ عیش و عشرت میں اور کچھ گناہ کے کاموں میں خرچ ہوجاتی ہے۔ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی ان کی ساری رقم ختم ہوجاتی ہے اور قرض لینے تک کی نوبت آجاتی ہے ۔ جس کے نتیجے میں وہ سماجی عزت اور ذہنی سکون دونوں سے محروم ہوتے ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے برکت کے نزول کا ضابطہ اس طرح بیان کیا ہے :
وَلَوْ اَنَّ اَہْلَ الْقُرٰٓي اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْہِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ (اعراف ۷:۹۶) اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں کثرت سے برکت مانگنے کا ذکر ہے۔کھانے کے بعد کی مسنون دعا ہے: اَللّٰھُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیْهِ وَاَطْعِمْنَا خَیْرًا مِّنْـهُ (سنن ترمذی) ’’اے اللہ! ہمارے لیے اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھانا عطا فرما‘‘۔
میزبان کے لیے دعا ہو یادودھ یا دوسرا مشروب پینے کی دعا یا دیگر مواقع ہوں آپؐ برکت ضرور مانگا کرتے تھے۔نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کوجھوٹی قسمیں کھانے سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔آپؐ کا ارشاد ہے: ’’جھوٹی قسموں سے مال تو فروخت ہوجاتا ہے لیکن اس مال سے ہونے والی کمائی سے برکت اُٹھ جاتی ہے‘‘۔(صحیح البخاری)
دوسرے مقام پراللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِہٖ فَاُولٰۗىِٕكَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۹ۚ (الحشر۵۹:۹)’’حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں‘‘۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاہے :
۱- ’’اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دووادیاں بھی ہوں تب بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا اورابنِ آدم کاپیٹ قبر کی مِٹی ہی بھر سکتی ہے۔‘‘(صحیح مسلم)
۲- ’’ دو بھوکے بھیڑیے جنھیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے [وہ بکریوں کو] اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی حرص اس کے د ین کو پہنچاتی ہے‘‘۔ (ترمذی)
۳- ’’انسان کہتا ہے، میرا مال، میرا مال، حالانکہ انسان کا مال بس وہ ہے جو اس نے کھاکر ختم کردیا،پہن کر بوسیدہ کردیا یا صدقہ کرکے آگے ( آخرت کے لیے) بڑھا دیا‘‘۔ (صحیح مسلم)
۴- ’’ہراُمت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز وجہِ آزمایش ہوتی ہے، میری اُمت کے لیے آزمایش مال ہے‘‘۔(سنن ترمذی)
اللہ تعالیٰ نے اسراف اور تبذیر کی مذمت فرمائی ہے:
۱- وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا۰ۚ اِنَّہٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ۳۱(اعراف۷:۳۱) ’’ اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ نکلو، بےشک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا‘‘۔
۲- وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا۲۶ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ۰ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّہٖ كَفُوْرًا۲۷ ( بنی اسرائیل۱۷:۲۶-۲۷) ’’فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے ربّ کا ناشکرا ہے‘‘۔
مال خرچ کرنے میں میانہ روی: خرچ کرنے میں کفایت شعاری اور میانہ روی بہترین حکمت عملی ہے ۔اللہ تعالیٰ بخل اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے: وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَـقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا۶۷ (الفرقان ۲۵:۶۷) ’’ وہ ( ایمان والے) جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں‘‘۔ اسی حقیقت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رہنمائی فرمائی ہے:مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ (مسند احمد)’’جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا‘‘۔
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی کچھ مال اپنے پاس رکھنے کا حکم ہے۔حضرت کعب ؓ نے جب اپنا سارامال صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا:أَمْسِکْ عَلَیْکَ بَعْضَ مَالِکَ فَھُوَ خَیْرٌ لَکَ(صحیح البخاری)’’اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھو تو یہ تمھارے لیے بہتر ہے‘‘۔
قرض کی واپسی میں بھی غریب کی سہولت کو ملحوظ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: مَنْ یَسَّرَ عَلٰی مُعْسِرٍ یَسَّرَاللّٰهُ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا وَالْاَخِرَةِ (صحیح مسلم)’’ جو (قرض خواہ ) کسی تنگ دست( مقروض کو اپنے قرضے کے سلسلے میں ) سہولت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سہولت دے گا‘‘۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے:’’جسے یہ اچھا لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیف سے نجات دے دے اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے‘‘۔ (صحیح البخاری)
امیر کو قرض دینے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ غریب کو حکم ہے کہ وہ احسان شناسی کا مظاہرہ کر کے قرض کو بروقت ادا کرنے کی کوشش کرے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہےکہ ’’قرض کی( بروقت) واپسی واجب ہے‘‘۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی)
دوسری حدیث میں ہے:مَطْلُ الْغَنِیِّ ظُلْمٌ (صحیح البخاری )’’ مال کی واپسی میں صاحب ِاستطاعت کا ٹال مٹول ظلم ہے‘‘۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یوں دعا کیا کرتے تھے: أَللّٰھُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِکَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ(صحیح البخاری)’’اے اللہ! میں گناہ اور قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں‘‘۔اسلامی تعلیمات کے مطابق قرض لینے کی اجازت کے باوجودمجبوری کے بغیر قرض لینے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔اس لیےسادگی اور کفایت شعاری اپنانے اور قرض لینے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَکَذَبَ مَا وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ( صحیح البخاری)’’ بلاشبہ جب بندہ مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے، تو خلاف ورزی کرتا ہے‘‘۔
دین اسلام کا تیسرا بنیادی ستون زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر ایمان کے بعد صرف دو اعمالِ صالحہ کا تذکرہ آیاہے: ایک نماز کا،دوسرا زکوٰۃ کا۔ یعنی جب ایک معیاری مومن کا تصور سامنے لانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوۃَ لَھُمْ اَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّـہِمْ۰ۚ (البقرہ ۲:۲۷۷)بلاشبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنھوں نے صالح اعمال کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کے ربّ کے پاس اجر ہوگا۔
حالانکہ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ایسے بہت سے اچھے اعمال و اخلاق ہیں جن کا اہتمام معیاری مومن و مسلم بننے کے لیے ضروری ہے۔ پھر قرآن حکیم ایسا اندازِ بیان کیوں اختیار فرماتا ہے؟ اور معیاری مومن و مسلم کا تصور دلانے کے لیے اکثر ایمان کے بعد صرف نماز اور زکوٰۃ ہی کا نام لے کر خاموش کیوں ہوجاتا ہے؟ دوسری نیکیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟
ظاہرہے کہ گفتگو کا یہ انداز اس نے بلاوجہ تو اختیار نہیں کیا ہے۔ غور کیجیے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہ مل سکے گی کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نماز اور زکوٰۃ یہی دو چیزیں دین کی اصل عملی بنیادیں ہیں۔ جس نے ان دونوں فرائض کو اچھی طرح ادا کرلیا، اس نے گویا پورے دین پر عمل کرنے کی پکی ضمانت اور عملی شہادت فراہم کردی اور اب اس سے اس بات کا کوئی واقعی اندیشہ باقی نہیں رہا کہ دوسرے احکامِ شریعت سے بے نیازی کا برتائو کرے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس بات کا جواب آپ کو ایک طرف دین کی اور دوسری طرف نماز وزکوٰۃ کی حقیقتوں اور غایتوں پر نظر ڈالتے ہی مل جائے گا۔ احکامِ دین کی اصولی تقسیم کیجیے تو ان کی دو ہی قسمیں ہوسکیں گی۔ ایک قسم ان احکام کی ہوگی جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے۔ دوسری قسم ان احکام کی ہوگی جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ اس طرح دین کی پیروی دراصل اس بات کا نام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق دونوں سے عہدہ برآ ہوجائے۔
نماز انسان کو اللہ اور آخرت کی طرف لے جاتی ہے تو زکوٰۃ اسے دُنیا کی طرف لڑھک جانے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ اگر کڑی چڑھائی کا راستہ ہے تو یہ دونوں چیزیں اس راستے پر سفر کرنے والے انسانی عمل کی گاڑی کے دو انجن ہیں۔ نماز کا انجن اسے آگے سے کھینچتا ہے اور زکوٰۃ کا انجن اسے پیچھے سے دھکیلتا ہے اور اس طرح یہ گاڑی اپنی منزل کی طرف برابر بڑھتی رہتی ہے۔ جب صورتِ واقعہ یہ ہے تو ان دونوں چیزوں (نماز اور زکوٰۃ) کو یہ حق لازماً پہنچنا چاہیے کہ انھیں دین کی اصل عملی بنیادیں قرار دیا جائے۔
آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ کلمۂ شہادت کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے محنت ہورہی ہے ۔ نماز کی اقامت اور اس کی ادائیگی کا اہتمام ہورہا ہے۔ نہ صرف فرائض بلکہ نوافل میں تہجد، چاشت اور صلوٰۃ التسبیح وغیرہ پر بھی زور دیا جارہا ہے۔ لیکن ایتائے زکوٰۃ جو دراصل ملّت کے فقراء و مساکین کا حق ہے ، اس کی طرف توجہ کم ہے۔ حالانکہ قرآنِ حکیم اور سنت ِ رسولؐ کی تعلیمات کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں نماز کے ساتھ ہمیشہ زکوٰۃ کا مکلف بھی بنایا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان گہرا ربط ہے اور ایک مسلمان کے اسلام کی تکمیل ہی ان دونوں سے ہوتی ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے دین کی ساری عمارت کو منہدم کردیا۔ اور زکوٰۃ اسلام کا پُل ہے جو اس پر سے گزر گیا، وہ نجات پاگیا اور جو اس سے اِدھر اُدھر ہوگیا وہ ہلاکت میں جاپڑا۔
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: مَنْ لَمْ یُؤَدِّ الزَّکٰوۃَ فَلَا صَلَاۃَ لَہٗ (مصنف ابن ابی شیبۃ) ’’جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی‘‘۔
چنانچہ قرآن کا صریح حکم ہے کہ کسی فرد کے اسلام لانے کو اسی وقت معتبر مانا جائے گا، جب وہ نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے:
فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوۃَ فَخَــلُّوْا سَـبِيْلَہُمْ۰ۭ (التوبہ ۹:۵) اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کرلیں، نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔
آگے چل کر پھر فرمایا:
فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوۃَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ۰ۭ (التوبہ ۹:۱۱) سو اگر یہ لوگ توبہ کرلیں، نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو اب وہ تمھارے دینی بھائی ہوں گے۔
کلام اللہ کی یہ صراحتیں بتاتی ہیں کہ کسی غیرمسلم کا مسلمان قرار پانا کلمۂ شہادت ادا کرنے کے بعد بھی دو باتوں پر موقوف ہے: ایک یہ کہ وہ نماز قائم کرے، دوسرے یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جب تک وہ ایسا نہیں کرتا اس کا مسلمان ہونا قابلِ تسلیم نہیں ہوسکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر سے تائب ہوکر دائرۂ اسلام میں آنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ایک ضروری علامت اور لازمی شرط ہے۔ اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:
اُمِرْتُ اَنْ اُقاتَلَ النَّاسَ حَتّٰی یَشْھَدُوا اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللہِ وَیُقِیْمُوا الصَّلَاۃَ وَیُؤْتُوْا الزَّکٰوۃَ فَاِذَا فَعَلُوْہُ عَصَمُوا مِنِّی دِمَائَھُمْ وَاَمْوَالَھُمْ وَحِسَابھُمْ عَلَی اللہ ِ (مسلم، کتاب الایمان) مجھے حکم دیا گیا کہ ان لوگوں (اہل عرب) سے جنگ کرتا رہوں، یہاں تک کہ وہ اللہ ہی کے معبود ہونے اور محمدؐ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دے دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تبھی مجھ سے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ پاسکیں گے اور اس کے بعد ان کا حساب لینا اللہ کا کام ہے۔
نہ صرف یہ کہ اسلام کے کسی منکر کا مسلمان ہونا ادائے زکوٰۃ کے بغیر معتبر نہ سمجھا جائے گا بلکہ جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں،وہ بھی اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کردیں تو اسلامی حکومت ان کے خلاف بھی تلوار اُٹھائے گی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے زمانۂ خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو آپؓ نے ان کے خلاف اعلانِ جنگ کردیا اور جب حضرت عمرؓ نے ان کے اس اقدام کے درست ہونے میں تردّد کا اظہار کیا تو آپؓ نے فرمایا:
واللہ لاُقاتِلَنَ من فرق بین الصلٰوۃ والزکٰوۃ (مسلم، کتاب الایمان) بخدا میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا ، جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں۔
دورِ نبویؐ میں زکوٰۃ کا نظام کیا تھا؟ اس پر غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے باقاعدہ ایک نظم قائم کیا جس کے چند اہم شعبے یہ تھے:
۱- عمال الصدقات یا عاملین صدقات: زکوٰۃ وصول کرنے والے افسران
۲- کاتبین صدقات: حساب کتاب کے انچارج
۳- خارصین: باغات میں پھلوں کی پیداوار کا تخمینہ لگانے والے
۴- عمال علی الحمٰی: مویشیوں کی چراگاہ سے محصول وصول کرنے والے
۱- عاملین صدقات: عاملین صدقات کے لیے آپؐ نے بڑے بڑے صحابہ کا انتخاب فرمایا جن میں امانت و دیانت، احساسِ ذمہ داری اور اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں ہوتی تھیں اور آپؐ نے انھیں مختلف قبیلوں کی طرف بھیجا، مثلاً حضرت عمرؓ کو مدینہ کے اطراف، حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ کو بنوکلب، حضرت عمرو بن عاصؓ کو قبیلہ فزارہ، حضرت عدی بن حاتمؓ کو قبیلہ طے اور حضرت ابوعبیدہ بن جراحؓ کو مزینہ اور کنانہ قبیلے کی طرف۔ یہ عاملین ان قبیلوں کے مزاج اور نفسیات سے بھی واقفیت رکھتے تھے اور ان کی مدد کے لیے مقامی عاملین بھی متعین تھے۔ ان عاملین صدقات کو ایک پروانۂ تقرر بھی ملتا تھا اور وصولی کرنے کے لیے ہدایات (Code of conduct) بھی۔ مثلاً زکوٰۃ میں عمدہ مال وصول نہ کریں، زکوٰۃ دینے والوں کے مقام پر جاکر وصول کریں اور وصول یابی کے بعد ان کے لیے دُعائے خیر کریں۔ مذکورہ قبیلے کو بھی ہدایت کی جاتی تھی کہ وصول کنندہ جب ان کے پاس آئے تو حُسنِ سلوک کریں تاکہ وہ خوشی سے واپس جائے۔ آپؐ نے یہ ارشاد فرمایا:
اَلْعَامِلُ عَلَی الصَّدَقَۃِ بِالْحَقِّ کَالْغَازِیْ فِیْ سَبِیْلِ اللہِ حَتّٰی یَرْجِعَ اِلٰی بَیْتِہٖ (ابوداؤد، کتاب الخراج) حق و انصاف کے ساتھ زکوٰۃ کا وصول کرنے والا اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے کے مانند ہے یہاں تک کہ وہ عامل اپنے گھر کو لوٹ جائے۔
اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا محاسبہ کرتے اور ان کی تنخواہ یا مشاہرہ مقرر فرماتے۔ امام بخاریؒ نے کتاب الزکوٰۃ میں ایک باب والعاملین علیھا میں محاسبۃ المصدقین مع الامام کا ذکر کیا ہے۔
۲- کاتبین صدقات: مالی نظام کے حساب کا باقاعدہ شعبہ دورِ نبویؐ میں موجود تھا۔ حضرت زبیر بن عوامؓ اسلامی ریاست کے صدقات کے کاتب تھے اور وہی سارا حساب کتاب رکھا کرتے تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں حضرت جہیم بن صلتؓ اور حضرت حذیفہ بن الیمانؓ صدقات کی آمدنی کے ذمہ دار تھے۔
۳- خارصین (پیداوار کا تخمینہ لگانے والے عاملین):عہدنبویؐ میں ایک عہدہ ’خارصین‘ یعنی افسران برائے تخمینۂ پیداوار کا تھا، جو اپنی خداداد صلاحیتوں کی بناپر کھجور وغیرہ کے باغوں کی پیداوار کا اندازہ لگاتے کہ باغ کی کُل پیداوار کتنے وسق ہوگی اور اس میں زکوٰۃ کی واجب مقدار کتنی ہوگی؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ماہر خراص تھے۔ غزوئہ تبوک کے سفر میں آپؐ نے ایک مسلمان خاتون کے باغ کی پیداوار کا تخمینہ لگایا تھا کہ اس کی پیداوار دس وسق ہوگی اور آپؐ کا تخمینہ بالکل درست ثابت ہوا (بخاری)۔صحابہ کرامؓ میں حضرت عبداللہ بن رواحہؓ ماہر خراص شمار کیے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انھیں ہرسال خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔
۴- عاملین علی الحِمٰی: دورِ نبویؐ میں مختلف قبیلوں سے مویشیوں کی زکوٰۃ کی وصول یابی کے لیے عاملین مقرر تھے، مثلاً حضرت ذرین بن ابی ذرؓ قبیلہ غفار کے لیے، حضرت ابورافعؓ ذوالجدر کے لیے، حضرت سعد بن ابووقاصؓ قریش اور زہرہ کے لیے، حضرت بلال بن حارثؓ مزینہ قبیلے کے لیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دورِ خلافت میں چند قبیلوں نے زکوٰۃ مدینہ کے مرکزی بیت المال میں بھیجنے سے انکار کیا تو آپؓ نے فرمایا: ’’اللہ کی قسم! اگر یہ لوگ مالِ زکوٰۃ میں سے ایک اُونٹ باندھنے کی رسّی یا بکری کا بچہ بھی روک لیں گے تو مَیں ان سے جنگ کروں گا۔ خدا کی قسم! میں ہر اُس شخص سے جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا‘‘۔ (الشوکانی، نیل الاوطار)
علامہ یوسف القرضاوی لکھتے ہیں: ’’حضرت ابوبکرؓ کا مانعینِ زکوٰۃ سے جنگ کرنا غالباً اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی حکومت و ریاست معاشرے کے کمزور افراد اور فقراء و مساکین کے حقوق انھیں دلانے کے لیے آمادئہ جنگ ہوئی، جب کہ تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ سماج کے طاقت ور طبقے کمزور طبقوں کو کھاتے رہے اور حکام و امراء نے کبھی غلاموں اور بے کسوں کی پشت پناہی نہیں کی بلکہ اکثر و بیش تر حکومت ِ وقت نے دولت مند طبقے کی حمایت کی‘‘۔ (فقہ الزکوٰۃ، ص ۱۱۵)
حضرت عمر فاروقؓ کے دورِ خلافت میں زکوٰۃ کی صورتِ حال کیا تھی؟ اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے یمن سے جب زکوٰۃ کا ایک تہائی حصہ بھیجا تو حضرت عمرؓ نے لینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا: میں نے تم کو ٹیکس یا جزیہ وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں کے تمام اغنیاء سے زکوٰۃ وصول کرکے ان ہی کے فقراء میں تقسیم کردو۔ حضرت معاذؓ نے کہا: یہاں زکوٰۃ لینے والے کسی شخص کو محروم کرکے میں نے آپ کے پاس یہ مال نہیں بھیجا ہے۔ پھر دوسرے سال حضرت معاذؓ نے نصف زکوٰۃ بھیج دی۔ اس موقع پر بھی دونوں طرف سے اسی طرح کی گفتگو ہوئی۔ پھر تیسرے سال حضرت معاذؓ نے کُل زکوٰۃ بھیجی۔حضرت عمرؓ نے اس موقع پر بھی یہی بات کہی جو اس سے پہلے کہہ چکے تھے۔ اس کے جواب میں حضرت معاذؓ نے کہا: ’’یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں‘‘۔ (ابوعبید ،کتاب الاموال)
حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور میں مصر کے گورنر نے انھیں لکھا کہ صدقہ وزکوٰۃ کی رقم لینے والا وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ مالِ زکوٰۃ کا اب کیا کریں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے جواب دیا: غلاموں کو خرید کر آزاد کرو، شاہراہوں پر مسافروں کے لیے آرام گاہیں تعمیر کرو اور ان نوجوان مردوں اور عورتوں کی مالی امداد کرو جن کا نکاح نہیں ہوا ہے۔
علامہ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ خلیفہ نے ایک شخص کا خصوصی طور پر تقرر کیا تھا، جو شہر کی گلیوں میں ہر روز یہ اعلان کرتا تھا: کہاں ہیں وہ لوگ جو مقروض ہیں اور قرض ادا نہیں کرسکتے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں ہیں محتاج و حاجت مند اور کہاں ہیں یتیم اور بے سہارا؟ یہ معاملہ چلتا رہا کہ سوسائٹی میں تمام لوگ مال دار ہوگئے اور غربت و افلاس کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ (ابوعبید، کتاب الاموال)
خلفائے راشدین کے بعد اُموی دور میں نظامِ خلافت بدل گیا اور حکام ظلم و تشدد پر اُتر آئے تو بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زکوٰۃ کیسے دی جائے اور انھیں زکوٰۃ کا امین کیسے بنایا جائے؟ لیکن صحابہ کرامؓ نے یہی فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ انھی کو دینی چاہیے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ خود اپنے طور پر خرچ کر ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ایک شخص نے پوچھا: اب زکوٰۃ کسے دیں؟ کہا: وقت کے حاکموں کو۔ اس نے کہا: وہ زکوٰۃ کا روپیہ اپنے کپڑوں اور عطروں پر صرف کرڈالتے ہیں۔ فرمایا: اگرچہ ایسا کرتے ہوں، مگر دو انھی کو،کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ بغیر نظام کے قائم نہیں رہ سکتا۔
واقعہ یہ ہے کہ صدرِ اوّل سے لے کر عہد ِ عباسیہ تک یہ نظام بلااستثناء قائم رہا، لیکن ساتویں صدی ہجری میں تاتاریوں کا سیلاب تمام اسلامی ممالک میں اُمنڈ آیا اور نظامِ خلافت معدوم ہوگیا، تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ فقہائے حنفیہ کے فتوے اسی دور میں یا اس کے بعد لکھے گئے۔ اس وقت پہلے پہل اس بات کی تخم ریزی ہوئی کہ زکوٰۃ کی رقم بطور خود خرچ کرڈالی جائے کیونکہ غیرمسلم حاکموں کو نہیں دی جاسکتی، مگر ساتھ ہی فقہاء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جن ملکوں میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہے اور حالت کا اعادہ فوراً ممکن نہیں، وہاں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کسی اہل مسلمان کو اپنا امیر مقرر کرلیں تاکہ اسلامی زندگی کا نظام قائم رہے، معدوم نہ ہوجائے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا مسلمانوں میں یہ غلط فہمی یقین کی صورت اختیار کرتی گئی کہ جن ملکوں میں اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں زکوٰۃ کا اجتماعی نظم اور بیت المال کا قیام ناممکن ہے۔
عام طور پر عوام اور خواص کا ایک بڑا طبقہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ فقراء کو یا اپنے مستحق رشتہ دار کو چند سو روپے، چند کلو اناج یا چند گز کپڑے دے دیئے جائیں۔ اس سے وہ چند دن یا زیادہ سے زیادہ چند مہینے اپنی ضروریات پوری کرلیتا ہے اور اس کے بعد وہ فاقہ کش اور تہی دست رہتا ہے اور ہمیشہ مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے ۔ کیا اس سے زکوٰۃ دینے کا مقصد پورا ہوجاتا ہے؟
ملت کے اندر بڑے پیمانے پر یہ بیداری اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی دینِ اسلام کی اہم ترین بنیادوں میں سے ایک ہے اور دورِ نبویؐ اور دورِ خلفائے راشدین میں کس طرح اجتماعی نظمِ زکوٰۃ جاری و ساری تھا۔ اس کے علاوہ خاص طور پر قرآن حکیم سورئہ توبہ کی آیات (آیت۶۰ اور ۱۰۳) کو اُجاگر کرنا چاہیے جن میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں اور زکوٰۃ کو وصول کرنے اور اس کی تقسیم کی ذمہ داری کس پر اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے؟
قرآن حکیم نےآٹھ قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے:
اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۗءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْہَا وَالْمُؤَلَّفَۃِ قُلُوْبُہُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللہِ وَابْنِ السَّبِيْلِ۰ۭ فَرِيْضَۃً مِّنَ اللہِ ۰ۭ وَاللہُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۶۰(التوبۃ ۹:۶۰) صدقات (یعنی زکوٰۃ) اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے فقراء کے لیے ، مساکین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ وصول و تقسیم پر مقرر ہیں اور ان کے لیے جن کی تالیف ِ قلب مقصود ہو اورگردن چھڑانے کے لیے اور قرض داروں کے لیے اور راہِ خدا اور مسافروں کے لیے۔ اللہ بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
زکوٰۃ کے جن آٹھ مصارف کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہیں:
۱-فقراء غریب
۲- مساکین:نادار
۳-عاملین:زکوٰۃ کو اکٹھا اور تقسیم کرنے والے
۴-تالیفِ قلب :جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے
۵-رقاب:غلاموں کو چھڑانے کے لیے
۶-غارمین:قرض دار
۷-فی سبیل اللہ:اللہ کی راہ میں
۸-ابن السبیل:مسافروں کے لیے
قرآنِ حکیم کا فرمان ہے:
خُذْ مِنْ اَمْوَالِہِمْ صَدَقَـۃً تُطَہِّرُھُمْ وَتُزَكِّيْہِمْ بِہَا (التوبۃ ۹:۱۰۳) اے نبیؐ ! تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انھیں پاک کرو اور (نیکی کی راہ میں) انھیں بڑھائو۔
دراصل زکوٰۃصرف انفرادی طور پر صدقات اور خیرات کو تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے اور نہ اس کی تقسیم کو امیروں کی صوابدید پر چھوڑدیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک سماجی اور فلاحی ادارہ ہے جس کی نگرانی حکومت ِ وقت کرے گی اور اس کے انتظام و انصرام کے لیے ایک عوامی ادارہ حکومت کے تحت وجود میں آئے گا۔ قرآن حکیم میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کن لوگوں پر اور کن مَدات پر خرچ کی جائے ، وہاں محکمۂ زکوٰۃ کے سرکاری کارندوں (وَالْعٰمِلِیْنَ عَلَیْھَا) کا ذکر بھی ایک مستقل حیثیت سے کیا گیا ہے۔
مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ’’ان کے مالوں میں سے صدقہ حاصل کرو اور انھیں پاک کرو اور ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو بڑھائو‘‘۔ اس میں خُذْ (حاصل کرو) کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ حیثیت سربراہِ مملکت کے ہے اور اس پر عمل خلیفۂ راشد حضرت ابوبکرؓ نے بہ حیثیت خلیفۂ رسولؐ کیا، اور اس پورے عمل کو جاری وساری رکھا۔ زکوٰۃ کی وصولی، عمال کا تقرر اور اس کی تقسیم کا پورا ڈھانچہ باقی اور برقرار رکھا۔ علما وفقہا نے تصریح کی ہے کہ خُذْ کا اطلاق اوّلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا اور آپؐ کے بعد ہراُس شخص پر ہے جو ملّت کا ذمہ دار ہے۔
چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے یمن روانہ فرمایا تو کہا: تُوخَذُ مِن اَغْنِیَائِھِمْ وَتُرَدُّ اِلٰی فُقَرَائِھِمْ (بخاری)’’زکوٰۃ ان کے دولت مندوں سے وصول کی جائے اور پھر ان کے فقرا اور محتاجوں میں لوٹائی جائے‘‘۔ اس طرح زکوٰۃ کے آٹھ حق داروں میں اوّلین مستحقین فقراء اور غرباء ہیں۔
آیئے زکوٰۃ کے مستحقین کی مختصر تفصیل ملاحظہ فرمائیں:
مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمیداللہ کے مطابق: فقر اء سے مراد غریب اور نادار مسلمان ہیں اور مسکین سے مراد غریب اور نادار غیرمسلم ہیں اور اس کے لیے انھوں نے امام ابویوسفؒ کی تالیف کتاب الخراج کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ حضرت عمرؓ اپنی خلافت کے زمانے میں زکوٰۃ کی آمدنی سے یہودیوں کی بھی مدد کرتے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ’’یہ اہل کتاب کے مساکین میں سے ہے، اس لیے زکوٰۃ سے اس کو رقم دی جائے‘‘۔
دیگر اصحابِ رسولؐ مثلاً زید بن ثابت، ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ کی رائے کا ذکر امام طبریؒ نے کیا ہے کہ زکوٰۃ غیرمسلموں کو دی جاسکتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فقراء سے مراد مسلمانوں کے فقراء اور مساکین سے مراد غیرمسلم رعیت کے فقیر ہوں گے۔
فقراء اور مساکین کے بعد ایک اہم مَد، عاملین زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ یہ اس بات کا بیّن ثبوت ہے کہ زکوٰۃ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی شکل میں اداکرنی چاہیے۔ نظامِ حکومت یا مسلم سوسائٹی کا عمل دخل اس میں ہونا چاہیے۔ اس کام کے لیے ایک الگ اور متحرک شعبہ یا ایک ادارہ عوامی سطح پر مختص ہونا ضروری ہے۔ عاملین زکوٰۃ میں نہ صرف زکوٰۃ وصول کرنے والے آتے ہیں بلکہ ایک پورا انتظامی شعبہ اور اس کے کارندے مراد ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے، اس کا حساب کتاب کرنے، مستحقین کے اعداد و شمار جمع کرنے، اس کو تقسیم کرنے اور اس پورے کام کے انتظام و انصرام کے عمل میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس کام میں خواتین سے بعض مخصوص کاموں میں مدد لی جاسکتی ہے، مثلاً بیوائوں اور معذوروں کی دیکھ بھال اور ان کی نگرانی وغیرہ۔
ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی حمایت کے لیے یا اسلام کی مخالفت سے روکنے کے لیے رقم دینے کی ضرورت پیش آئے۔ نیز ان میں وہ نومسلم بھی داخل ہیں جنھیں مطمئن کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی قوم کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آملنے کی وجہ سے بے روزگار یا تباہ حال ہوگیا ہو تو اس وقت اس کی مدد کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن اگر وہ مال دار ہو تب بھی اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے تاکہ اس کا دل اسلام پر جم جائے۔ بعض علما نے مؤلّفۃ القلوب پر تفصیل سے لکھا ہے، مثلاً ابویعلٰی الفرا حنبلی نے اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں جو امام ماوردی کے معاصر ہیں، اس کی چار قسمیں بیان کی ہیں:
پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کو رقم اس لیے دی جائے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے، جن کو رقم اس لیے دی جائے کہ وہ مسلمانوں کو مضرت پہنچانے سے باز رہیں۔ عام حالات میں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو رقم دے دی جائے، تو مثلاً جنگ کے زمانے میں وہ غیر جانب دار رہیں گے، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تیسری قسم، ان لوگوں کی ہے جن کو رقم اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے قبیلے کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ اسلام قبول کریں۔ اس فہرست کے بعد وہ ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں کہ یہ رقم مسلمان اور غیرمسلم کسی کو بھی دی جاسکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کی تالیف ِ قلب کرنی ہو یا کسی کو، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے رقم دی جانی ہو، تو وہ غیرمسلم ہی ہوگا۔ لیکن وہ صراحت سے کہتے ہیں کہ چاہے وہ غیرمسلم ہو یا مسلم، اس کو مؤلّفۃ القلوب کے تحت زکوٰۃ کی آمدنی سے رقم دی جاسکتی ہے۔ (ڈاکٹر حمیداللہ کی بہترین تحریریں، ص ۲۰۲، مرتب: سیّد قاسم محمود)
عام طور پر ملک کے علما کا یہ خیال ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانے کے بعد اسلام کو غلبہ واستحکام حاصل ہوچکا ہے اس لیے مال کے ذریعے تالیف ِ قلب کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ لیکن وہ علما جو اس دعوتی کام میں سرگرم ہیں ان کا خیال ہے کہ اسلام آج حضرت عمرؓ کے دور کی طرح مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے اس مَد میں خرچ کے ذریعے نہ صرف نومسلموں کی اعانت اور مدد کرنی چاہیے بلکہ ان طبقات کو جو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت و مزاحمت میں پیش پیش ہیں، اس کے منفی رویہ و عمل میں کمی یا اس کے خاتمے کے لیے اور بعض افراد اور جماعتوں کو دینِ رحمت کی طرف راغب کرنے کے کاموں میں اس مَد کے ذریعے خرچ کرنے کی گنجائش باقی ہے اور یہ وقت کا اہم تقاضا بھی ہے۔
مصارفِ زکوٰۃ کا ایک حصہ گردنوں کو آزادکرنے میں صرف ہوگا یعنی اس حصہ سے غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرایا جائے گا لیکن آج اس قسم کے غلام اور باندی نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں فقہاء کا کہنا ہے کہ اگر اس کو عام مفہوم میں لیا جائے تو اس سے ان قیدیوں کو جو جیلوں میں جرمانہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید ہیں، ان کو رہا کرانے یا ان کے مقدموں کی پیروی کرکے انھیں آزاد کرانے کے کاموں میں خرچ کیا جاسکتا ہے۔
طبقات ابن سعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا ایک خط جو انھوں نے یمن کے گورنر کے نام لکھا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ جتنی رعایا دشمن کے ہاتھ قید ہو اس کو چھڑانے کے لیے سرکاری خزانے سے رقم خرچ کی جائے اس صراحت کے ساتھ کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا ذمی ہو۔ گویا رقاب کے سلسلے میں اسلامی رعیت کو دشمن کی قید سے رہائی دلانے کے لیے جو فدیہ دیا جاتا ہے اس میں بھی مسلم اور غیرمسلم کا امتیاز نہیں ہے۔ جس طرح فقراء اور مساکین کے سلسلے میں حضرت عمرؓ کی رائے میں زکوٰۃ کی رقم سے غیرمسلم کی مدد کی جاسکتی ہے۔
قرض دار جس پر اتنا قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس مقدارِ نصاب سے کم مال بچتا ہو، اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ البتہ فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی فضول خرچیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے قرض دار ہو، اس کو زکوٰۃ دینا مکروہ ہے۔ لیکن قرض دار کو زکوٰۃ سے حصہ دیا جائے تو ایک طرف تو قرض سے نجات کا ذریعہ بنے گا، دوسری طرف ان کو صاف ستھری باعزّت زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا۔حضرت عمرؓ کے زمانے میں غارمین سے ایک نئی چیز کا استنباط ہمیں ملتا ہے اور وہ سرکاری خزانے سے لوگوں کو امداد نہیں بلکہ قرض دینا ہے۔ اس طرح عہدفاروقی میں زکوٰۃ کی رقم سے بلاسودی قرض دینے کا ثبوت ملتا ہے۔
یہ ایک عام لفظ ہے جو تمام نیک کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن خاص طور پر اس سے مراد دینِ حق کا جھنڈا بلند کرنے کی جدوجہد میں مدد کرنا ہے۔ بعض فقہاء کا خیال ہے کہ فی سبیل اللہ کا لفظ مجاہدین کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جس سے خدا کی رضا مقصود ہو وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ ڈاکٹریوسف قرضاوی نے لکھا ہے کہ فی سبیل اللہ کے حصۂ زکوٰۃ کو دینی، تربیتی اور اشاعتی جہاد پر صرف کرنا زیادہ بہتر ہے بشرطیکہ یہ جدوجہد خالصتاً اسلام کے لیے ہو، مثلاً: دعوتی مراکز قائم کرنا، صلاحیت کے حامل مخلص افراد کی صلاحیتوں کومزید ترقی دینا (Human Resources Development) وغیرہ۔
اگرچہ مسافر کے پاس اس کے وطن میں کتنا ہی مال ہو، لیکن حالت ِ سفر میں اگر وہ محتاج ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ بعض علما کا خیال ہے کہ ابن السبیل کی تعریف کے تحت آج کل کے مہاجرین بھی آجاتے ہیں جو جنگ، غارت گری اور ظلم و جَور کے باعث بے گھر ہوجاتے ہیں۔ جو کچھ مال و دولت ان کے پاس تھا وہ وہیںرہ جاتا ہے اور اب ان کے لیے اس سے استفادہ ممکن نہیں رہ جاتا۔
مصارفِ زکوٰۃ کی آٹھ مدات کی تفصیلات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام نظامِ زکوٰۃ کےذریعے ایک Sharing & Caring (باہمی ہمدردی اور ایک دوسرے سے تعاون) سوسائٹی کا قیام چاہتا ہے جہاں پر ہرشخص کی بنیادی ضرورتیں:غذا، لباس، رہائش، حفظانِ صحت، اس کے لیے گھریلو سازوسامان اور سواری کی سہولتیں کم از کم مہیا ہوں اور ایک معتدل اور متوازن زندگی گزار سکے جو اِکرامِ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح معاشرہ کے تمام افراد میں دولت گردش کرتی رہے اور صرف امیروں کے درمیان گھومتی نہ رہے۔ عام طور پر مسلم سماج میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ستون ہے جس کے ذریعے سے نادار اور غریب زکوٰۃ کی رقم حاصل کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی اہمیت دین میں اس لیے بھی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سماج کے ضرورت مند طبقے کو خوش حال طبقہ بناتا ہے اور انھیں لینے کی پوزیشن سے نکال کر دینے کی پوزیشن میں لاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والوں کا طبقہ اسی وقت پیدا ہوگا جب سوسائٹی کا ہرفرد مضبوط اور مالی طور پر مستحکم ہوگا اورمعاشرے کے کمزور اور کچلے ہوئے طبقے دینے والے بنیں گے۔
اجتماعی نظام زکوٰۃ کے ذریعے ایک ایسے سماج اور سوسائٹی کے قیام کی کوشش ہوتی ہے، جس کے تمام افراد بالخصوص ایک بڑا طبقہ معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور کمزور اور بے سہارا افراد کو ان کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ؒ کے دور میں جب یہ نظامِ رحمت قائم تھا تو زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے لیکن سوسائٹی میں زکوٰۃ لینے والے موجود نہیں تھے۔
زکوٰۃ کی رقم زیادہ تر غریب عوام کی فوری ضرورتوں کی تکمیل میں استعمال ہوتی ہے لیکن اگرچھوٹے صنعت کاروں اور تاجروں کو چھوٹے پیمانے پر بنیادی سرمایہ (Seed money) فراہم کرکے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ دیاجائے تو اس سے غربت بتدریج ختم ہوسکتی ہے اور مستحقینِ زکوٰۃ چند برسوں میں زکوٰۃ دینے والے بن سکتے ہیں۔ دُنیا کے مختلف ملکوں میں مائیکروفنانس کے ذریعے ایسے کامیاب تجربے کیے جارہے ہیں۔ ملک عزیز میں بھی اس قسم کے اداروں کے ذریعے چھوٹے تاجروں اور ہنرمندوں کی امداد کی جاسکتی ہے۔
بہت سے علما کا موقف یہ ہے کہ اموالِ زکوٰۃ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے:
الف: اموالِ ظاہرہ: غلّہ، مویشی وغیرہ ، جنھیں آسانی کے ساتھ معلوم اور متعین کیا جاسکتا ہے۔
ب: اموالِ باطنہ: سونا، چاندی اور تجارتی سامان وغیرہ
اموالِ ظاہرہ کو حکومت یا سماجی ادارہ حاصل کرکے اجتماعی طور پر تقسیم کرسکتا ہے لیکن اموالِ باطنہ کو اس کے مالک کی صوابدید پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ خود اس کی تقسیم زکوٰۃ کی مدات میں کرے، اس لیے کہ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنیؓ نے اپنے دورِ خلافت میں ایسا ہی کیا تھا۔
اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت راشدہ ؓ کے زمانے میں چند قبیلوں کو جو رخصت دی گئی تھی کہ وہ خود غریبوں میں اپنی زکوٰۃ تقسیم کریں ، وہ اَزخود نہیں تھی، بلکہ حکومت نے اس کی اجازت دی تھی۔ یہ صورت بھی دراصل حکومت ہی کے ذریعے زکوٰۃ کی جمع و تقسیم کا ایک خاص انتظام تھا، جو مصلحتوں اور سہولتوں کی خاطر اختیار کرلیا گیا تھا۔
ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ حضرت عثمانؓ کے دور میں حضور اکرمؐ کی وفات کے صرف پندرہ سال بعد اُمت تین براعظموں: یورپ، افریقہ اور ایشیا میں پھیل گئی تھی اور کہیں کہیں ایک سو مربع میل میں ایک سے زائد مسلمان نہیں تھا۔اس وجہ سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ہرمسلمان کے مکان پر کارندوں کو بھیجنا اور حساب مانگنا مشکل تھا، اور اس کے لیے ایک کثیر عملے کی ضرورت پیش آتی تھی جس میں مصارف زیادہ اور آمدنی کم ہوسکتی تھی۔ اس لیے اس طرح کی آبادی کے صاحب ِ نصاب مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ وہ ہرسال زکوٰۃ کی رقم خود ہی احکامِ قرآنی کے مطابق نکال کر تقسیم کردیا کریں۔
بہرحال علمائے کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے حالات کے تناظر میں فیصلہ کریں کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام کیا ہو اور اموالِ باطنہ کو انفرادی طور پر اور ظاہرہ کو اجتماعی طور پر جمع کرکے تقسیم کرنے کا نظم کریں۔
ڈاکٹر یوسف القرضاوی فرماتے ہیں: ’’زکوٰۃ حکام کو دیتے وقت ایک تہائی یا ایک چوتھائی اپنے پاس روک لے، تاکہ اس کو اپنی جان پہچان، اڑوس پڑوس اور غریب رشتہ داروں میں تقسیم کرسکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک چوتھائی یا ایک تہائی زکوٰۃ دینے والوں کے ہاتھ میں رہنے دیں تاکہ وہ خود تقسیم کرسکیں‘‘۔ (فقہ الزکوٰۃ، ج۲)
دورِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کے قیام کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے مخلص اور باصلاحیت افراد جن میں سماجی خدمت کا جذبہ ہو اور جن کی قابلیت پر اعتماد کیا جاسکتا ہو، وہ ہرچھوٹے بڑے شہر میں ایک اجتماعی شکل اختیار کریں اور زکوٰۃ کا ایک اجتماعی نظم قائم کرنے کی سعی و جہد کریں اور اس کے لیے ایک مہم چلائیں۔ آج سے چند سال پہلے مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ نے میوات سے کلمہ اور نماز کے لیے ایک مخلصانہ مہم چلائی تھی جس کی وجہ سے نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دُنیا میں کلمہ پر محنت اور نماز کے قیام اور مسجدوں کے آباد کرنے کی کوشش شروع ہوئی۔ اسی طرح معاشرے کے ہرطبقہ میں اجتماعی نظمِ زکوٰۃ کی ہمہ گیر مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ ان شاء اللہ چندبرسوں میں اس کے مفید اور مؤثر نتائج سامنے آئیں گے اور اس طرح اقامت ِالصلوٰۃ اور ایتاء الزکوٰۃ سے ایک متوازن اور متمول اسلامی معاشرہ ملک میں وجود میں آئے گا جو اپنی مثال آپ ہوگا اور خیراُمت کی حیثیت سے یہ دوسرے معاشروں کے لیے بھی دعوتِ دین کا باعث ہوگا۔
’قابلیت‘ وہ خوبی ہے، جو ایک لیڈر کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ عوام میں اپنا اعتبار قائم کرسکے۔ منظم انداز میں مکمل توجہ کے ساتھ بروقت اپنے فرائض انجام دینا قابلیت کی معراج ہے۔ ایک قابل لیڈر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ دُور اندیش ہو، عمدہ حکمت ِ عملی تیار کرسکتا ہو اور پیشہ ورانہ انداز میں مشکل فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ ایسے واقعات سے جگمگاتی ہے، جن کی بدولت زندگی کے ہرمیدان میں آپؐ کی مہارت اُبھر کر سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کو منظم کرنا، سفارت کاری ، امن معاہدے، عسکری مہارت ، اُمت کی تعلیم و تربیت، مذاکرات کا طریقہ، فنِ تعمیر، شہسواری، تجارت، اندازِ گفتگو، گھریلو کام کاج جیسے کھانا پکانا اور کپڑوںکی سلائی اور جوتوں تک کی مرمت وغیرہ۔
نبوت سے پہلے بھی لوگ آپؐ کی معاملہ فہمی اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت کے معترف تھے۔ آپؐ تقریباً پینتیس برس کے تھے جب قریشِ مکہ نے کعبہ کی تزئین و آرائش کا فیصلہ کیا، جس کے لیے حجرِاسودکو اس کی جگہ سے ہٹانے کی ضرورت پیش آئی۔ جب اسے واپس لگانے کا وقت آیا تو مختلف قبیلوں میں اختلاف پیداہوا کہ یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی؟ یہ جھگڑا چار دن تک جاری رہا اور نوبت یہاں تک آپہنچی کہ خوں ریزی کا اندیشہ پیدا ہوگیا۔
اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے پانچویں دن وہاں پر موجود بزرگ ترین سردار ابواُمیہ ابن مغیرہ نے تجویز دی کہ اگلے دن جو بھی شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا، اسی سے اس معاملے کا فیصلہ کروایا جائے گا۔ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنھیں دیکھ کر سب پکار اُٹھے کہ ’امین‘ آگیا۔ آپؐ نے اپنی چادر زمین پر بچھائی، حجرِاسود کو اس پر رکھا اور تمام سرداروں سے کہا کہ وہ اس چادر کا ایک ایک کونا تھام کر اسے اُٹھا کرلے چلیں۔ اس کے بعد آپؐ نے اپنے ہاتھوں سے حجرِاسود کو اُٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کردیا۔ جنگ کی جانب بڑھتی ہوئی صورتِ حال کو ایسی عمدگی سے حل کرنا، جس سے فریقین مطمئن ہوں، آپؐ کی دانائی اور معاملہ فہمی کا روشن ثبوت ہے۔
یہ آپؐ کی ایمان داری اور لوگوں کا آپؐ پر اعتبار ہی تھا جس کی بنیاد پر حضرت خدیجہؓ نے آپؐ کو اپنے کاروبار پر نگران مقرر کیا ، اور آپؐ کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور مہارت سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ کچھ ہی عرصے بعد آپؐ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ رفتہ رفتہ آپؐ ایک کامیاب تاجر سے ایک پیغمبر بنائےگئے اور بالآخر ایک ایسے بااثر راہ نما بن کر دُنیا میں اُبھرے جنھیں ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا گیا۔ مختلف ریاستی اُمور کی انجام دہی کے لیے موزوں ترین افراد کو نامزد کرنے کا معاملہ ہو یا ریاست ِ مدینہ کے پہلے آئین کی تشکیل، ریاستی اُمور میں آپؐ کی قابلیت و معاملہ فہمی اور تحمل و دُور اندیشی بے نظیر تھی۔ اسی قائدانہ مہارت کے نتیجے میں مدینہ میں ایسا منفرد معاشرہ وجود میں آیا، جہاں پر رنگارنگ ثقافتوں اور الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ رواداری اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔
اسلام کے پہلے آئین کی نمایاں خصوصیات میں مساوات، عدل و انصاف، پس ماندہ طبقے کی مدد اور تحفظ، مذہبی رواداری، قتل و غارت کی ممانعت اور نبی پاکؐ کی اجازت کے بغیر جنگ کا اعلان کرنے کی ممانعت شامل ہیں۔ اسی آئین میں خارجہ پالیسی اور اس جیسے دیگر اہم ریاستی اُمور انجام دینے کے لیے باہمی مشاورت کا نظام قائم کیا گیا، جس میں مسلمان اور غیرمسلم بشمول یہودی قبیلے شامل تھے۔ آئین میں واضح کیا گیا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار کیا جائے گا اور کسی یہودی کو محض اس کے مذہبی عقائد کی بناپر بدسلوکی کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد تھی، جس میں الگ الگ قومیں اور مذاہب ہم آہنگی کے ساتھ پُرامن زندگی گزار سکیں اور اچھے اور بُرے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔
مکہ میں مسلمانوں کی قلیل تعداد اور انھیں پیش آنے والے خطرات اور تکالیف کے برعکس مدینہ میں حالات کافی مختلف تھے۔ مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی اور عسکری لحاظ سے مضبوط تھے اور ان کی طاقت میں روز بہ روز اضافہ ہورہا تھا، لیکن ایک نئی ریاست کی تشکیل اوراس کا انتظام بخوبی چلانا بذاتِ خود ایک بڑا چیلنج تھا۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف ہوکر اکثر دشمن قبیلے ان پر حملہ آور ہونے اور ان کا نام و نشان مٹادینے کے درپے تھے۔ بدر، اُحد اور خندق کے غزوات ان کی ایسی ہی چند کوششیں تھیں جن میں آنحضورؐ کی عسکری مہارت، عزم اور قائدانہ صلاحیت کی بناپر، محدود وسائل کے باوجود مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔
مدینہ میں گزرے آخری برسوں کے دوران میں مذاکرات کے حوالے سے آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ اور پھر صلح حدیبیہ کا مرحلہ وہ موقع تھا جب آپؐ نے اپنی اس مہارت کا دانش مندانہ استعمال کرتے ہوئے کمالِ حکمت کے ساتھ صلح نامے کی شرائط طے کیں، جس کے نتیجے میں بالآخر کسی قسم کی خوں ریزی کے بغیر مکہ فتح کرلیا گیا۔ آپؐ کی قائدانہ مہارت اور اعلیٰ ظرفی کا نتیجہ عام معافی کی صورت میں سامنے آیا اور وہی لوگ جو کبھی آپؐ کی جان کے دشمن ہوا کرتے تھے، نہ صرف آپؐ کے زیراقتدار امن اور آزادی سے زندگیاں گزارنے لگے بلکہ آنے والے دنوں میں اسلام کی قوت بن کر اُبھرے۔
وقت کا بہترین استعمال (ٹائم مینجمنٹ)ایک ایسی مہارت ہے، جس سے انسان کے پیشہ ورانہ رویے اور قابلیت کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ حضوؐر مثالی ڈسپلن کا عملی مظاہرہ خود بھی کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی تاکید کرتے تھے کہ وہ اپنے وقت کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں پر صرف کریں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ وقت ایک دولت ہے، لیکن آپؐ کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو وقت خود زندگی ہے، اس لیے وقت ضائع کرنے کا مطلب زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ روزانہ کی پانچ فرض نمازوں کے اوقات مخصوص ہیں اور مسلمانوں کو تاکیدکی گئی ہے کہ وہ ہر نماز اپنے مقررہ وقت کے اندر اندر پڑھ لیں۔ گھڑی یا الارم کلاک ایجاد ہونے سے پہلے کے اس زمانے میں آپؐ نے مسلمانوں کو سورج کے ذریعے نماز کے وقت کا تعین کرنا سکھایا، جب کہ آج مختلف آلات اور ایجادات کے باوجود ٹائم مینجمنٹ بہت سوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اسی طرح آپؐ نے فارغ وقت کو فضول گفتگو اور بے جا گپ شپ میں برباد کرنے کی بھی حوصلہ شکنی کی اور اس کے بامقصد استعمال پر زور دیا۔
صحیح مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مضبوط ایمان رکھنے والا، کمزور ایمان رکھنے والے سے بہتر ہے۔ یہ اصول انسانی زندگی کے جسمانی، ذہنی اور پیشہ ورانہ پہلوئوں پر لاگو ہوتا ہے۔ قیادت کے لیے مضبوط اُمیدوار درحقیقت وہی ہوتا ہے جو ہرلحاظ سے اس کے لائق ہو۔ دُنیا میں کئی مضبوط اور قابل راہ نما آئے، لیکن ان میں ایسے افراد بہت کم تھے جنھوں نے اپنے جانشین تیار کیے ہوں۔ حالانکہ ایک طاقت ور اور لائق لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ قابل اور باصلاحیت افراد کی اس طرح تربیت کرے کہ وہ اس کے جانے کے بعد کامیابی سے نظام چلا سکیں۔ اس لحاظ سے آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقی مربی یعنی سرپرست تھے، جنھوں نے ہر زاویے سے صحابہ کرامؓ کے اخلاق اور کردار کی تربیت کی اور انھیں ذمہ داریاں سونپتے وقت ان کی شخصیت اور اہلیت کو مدنظر رکھا۔ آج ہیومن ریسورس سے تعلق رکھنے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ فرد کی کامیابی کے لیے فنی مہارت کے ساتھ ساتھ ذہنی صلاحیت کا ہونا بھی لازم ہے۔ لیڈرشپ محض ایک اندازِ فکر نہیں بلکہ ایک صلاحیت ہے، جس کی جامع مثال آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک ہے۔
جب کبھی آپؐ کسی وجہ سے نماز کی امامت کروانے سے قاصر ہوتے تو یہ ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیقؓ کے حوالے کر دیتے تھے۔ پہلے امامت اور بعدازاں پہلے خلیفہ کے طور پر حضرت ابوبکرؓ کا انتخاب اسی لیے کیا گیا کیوں کہ ان کی قابلیت اور اہلیت اس منصب کے لیے موزوں ترین تھیں۔ بطور سپہ سالار حضرت خالد بن ولیدؓ کئی معروں میں اپنی عسکری مہارت منوا چکے تھے، جس کی وجہ سے بہت سی جنگی مہمات ان کے سپرد کی گئیں حالانکہ اس پر چند بزرگ صحابہؓ کو اعتراض بھی ہوا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشیؓ کی سُریلی آواز کی بنا پر انھیں اسلام کا پہلا مؤذن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ پُراثراندازِ گفتگو اور سفارت کاری میں مہارت رکھنے والے حضرت جعفرؓ بن ابی طالب کو نمائندہ بناکر حبشہ بھیجا گیا۔ حضرت مصعب ؓ بن عمیر میں قدرتی طور پر معلّمانہ خصوصیات موجود تھیں، جس کی وجہ سے انھیں مدینہ بھیج دیا گیا تاکہ وہ وہاں پر لوگوں کو تعلیم دے سکیں۔ حضرت معاذؓ بن جبل میں معلّمانہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ اجتہاد اور علمی بصیرت جیسی خوبیاں پائی جاتی تھیں، اس لیے انھیں یمن کی طرف روانہ کردیا گیاتاکہ وہ وہاں پر دین اسلام کو پروان چڑھا سکیں۔ حضرت سلمان فارسیؓ کی بہترین عسکری حکمت عملی کی وجہ سے جنگی معاملات میں ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ حضرت حسانؓ بن ثابت عمدہ شاعری کیا کرتے تھے اور انھیں منبر رسولؐ سے بھی اپنے اشعار سنانے کا شرف حاصل ہوا۔
قابلیت کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب آپؐ کی قائدانہ خصوصیات کا ایک اہم پہلو ہے اور اس کی کئی مثالیں آپؐ کی زندگی میں موجود ہیں۔ اس ضمن میں آپؐ کی حضرت ابوذر غفاریؓ کو دی جانے والی ایک مشہور نصیحت ہے، جب اُنھوں نے آپؐ سے کوئی عہدہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا تو آپؐ نے ان کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا: ’’اے ابوذرؓ! تم کمزور ہو اور یہ عہدہ عوام کی امانت ہے۔ جو انسان اس ذمہ داری اور اس سے وابستہ فرائض احسن طریقے سے پورے نہیں کرپائے گا اسے آخرت میں ندامت اُٹھانا پڑے گی‘‘ (مسلم)۔ ایک اور موقعے پر آپؐ نے حضرت ابوذرؓ سے کہا:’’مجھے تمھارے اندر کمزوری دکھائی دیتی ہے۔ کبھی کوئی عہدہ قبول نہ کرنا، چاہے اس میںتمھیں صرف دو لوگوں پر ہی نگران کیوں نہ بنایا جائے اور کبھی کسی یتیم کے مال کی رکھوالی کی ذمہ داری مت لینا‘‘۔ (مسلم)
آپؐ کی ان باتوں کا مقصد حضرت ابوذرؓ کی دل آزاری کرنا نہیں بلکہ یہ سمجھانا تھا کہ لیڈرشپ کے لیے صرف خلوص اور نیک نیتی کافی نہیں بلکہ اہلیت بھی انتہائی ضروری ہے۔
خلفائے راشدین بھی باصلاحیت لوگوں کی قدروقیمت سے بخوبی آگاہ تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر ؓ نے اپنے ساتھیوں سے کہا: اپنی کوئی خواہش بیان کرو۔ ان کے ایک ساتھی نے کہا: میری خواہش ہے کہ یہ تمام جگہ سونے سے بھر جائے تاکہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں۔
ایک اور ساتھی بولے: میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ ہیرے جواہرات، موتیوں اور زیورات سے بھر جائے تاکہ میں انھیں اللہ کی راہ میں خیرات کرسکوں۔
اس پر حضرت عمرؓ نے کہا: میری خواہش ہے کہ یہ جگہ ابوعبیدہؓ بن الجراح، معاذؓ بن جبل، سالمؓ اور حذیفہؓ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے۔
پروفیسر ایڈیئر کا کہنا ہے کہ ایک قابل اور بااثر لیڈر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہرفرد کام کو مکمل طور پر سمجھ لے۔ یعنی وہ جانتا ہو کہ اس کام کو کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے ذریعے کیا حاصل ہوگا؟ اس میں کون سے کام کیے جائیں گے؟ اور ان سب چیزوں کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ اسی طرح ٹیم میں توازن اور ہم آہنگی برقرار رکھی جاسکتی ہے۔ ایک باصلاحیت لیڈر اپنی ٹیم میں موجود لوگوں کا انفرادی طور پر بھی خیال رکھتا ہے۔ ایسا کرنے کی مختلف صورتیں ہوسکتی ہیں، جن میں لوگوں کی ذاتی ضروریات کا خیال رکھنا، معاوضے اور مواقع دینے میں انصاف سے کام لینا اور ان کی دل داری اور حوصلہ افزائی کی کوشش کرنا شامل ہیں۔ ایک عمل پسند قیادت ( Action Centred Leadership)کا یہ ماڈل ان تین عوامل کے توازن سے مل کر بنتا ہے:
کام
ٹیم
فرد
نتیجہ خیز ماڈل میں یہ تینوں عوامل ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اورکسی ایک کو نظرانداز کر دیا جائے تو باقی دونوں بھی اپنا کام صحیح طور پر انجام نہیں دے پاتے۔ اگر ٹیم کے کچھ افراد ناخوش ہوں تو مطلوبہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں کیا جاسکتا اور نہ ٹیم کا جوش اورلگن ہی برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح صرف افراد کی خوشی عمدہ ٹیم ورک کی ضمانت نہیں ہوسکتی اور نہ صرف عمدہ ٹیم ورک کے ذریعے کام کی تکمیل کرنا ممکن ہے۔ لہٰذا ایک قابل لیڈر ایک ایسا نظام تیار کرتا ہے، جس کے تحت کاموں کی نگرانی کی جاسکے۔ ٹیم ممبران کے ساتھ فرداً فرداً ملاقاتوں کے ذریعے ان کی خوشی اور کارکردگی کا اطمینان کرلیا جائے، ٹیم ممبران میں اعتبار اور دوستانہ تعلقات قائم ہوں اور کسی قسم کے اختلافات پیدا ہونے کی صورت میں انھیں فوراً حل کرلیا جائے۔
جب اس ماڈل کے تینوں عوامل اپنی اپنی جگہ حرکت میں آجائیں اور نظام چل پڑے تو لیڈر پیچھے ہٹ کر لوگوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ کھل کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں اور کامیابیاں حاصل کرسکیں۔ لیڈر ہر چھوٹی چھوٹی بات کا انتظام سنبھالنے کے بجائے ایسے عوامل پیدا کرتا ہے کہ لوگ بآسانی اپنا کام انجام دے سکیں۔ایڈئیر کا کہنا ہے کہ لیڈر کے پیچھے ہٹ جانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس ماڈل کے تینوں عوامل سے بے خبر ہوجائے بلکہ اسے چاہیے کہ وہ نظام کے چلنے سے باخبر رہے۔ ایڈئیر اس عمل کو ہیلی کاپٹر ویو (Helicopter View) کا نام دیتا ہے۔ اس طرز کی نگرانی کا مقصد یہ ہے کہ کام، فرد اور ٹیم کی کارکردگی پر نظررکھی جائے اور جہاں کوئی پہلو کمزور پڑتا نظر آئے تو نیچے آکر اس کی اصلاح کی جائے اور پھر واپس اُونچائی کی طرف پرواز کرلی جائے۔ایڈئیر کا کہنا ہے کہ اس لحاظ سے ایک قابل لیڈر کی زندگی ضرورت کے مطابق اُوپر اور نیچے آنے جانے کا نام ہے، جس کے ذریعے بہترین نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
حقیقی معنوں میں قابل انسان وہ ہےجو دوسرے باصلاحیت لوگوں سے مسابقت کرسکتا ہو۔ اس لحاظ سے اگر آج کی دُنیا میں مسلمانوں کی قابلیت اور صلاحیتوں کا جائزہ لیا جائے تو صورتِ حال زیادہ خوش آئند دکھائی نہیں دیتی۔ نبویؐ تعلیمات سے جنم لینے والی سائنسی ریسرچ، جدت اور ایجادات کی روایات صدیوں تک اعلیٰ پائے کے محققین پیدا کرتی رہیں، لیکن صرف ابن سینا، ابن الہشام اور الخوارزمی کے شان دار کارناموں کے گُن گانے سے ہماری موجودہ نااہلی اور بدعملیاں ختم نہیں ہوسکتیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر ہمت اور قوتِ عمل کو جگانا ہوگا تاکہ ہم میں وہ اہلیت پیدا ہوسکے جو لیڈر شپ کا خاصہ ہے۔
علّامہ ابن القیم کا قول ہے:’’عزم وہ بیج ہے جس سے ساری عظمتیں جنم لیتی ہیں۔ عظیم لیڈر بھی اسی عزم کی بہ دولت وجود میں آتے ہیں‘‘۔
مستقل مزاجی سے نئی مہارتیں سیکھنے اور اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش مسابقت کے عمل کو پروان چڑھاتی ہے۔ ابن ماجہ میں روایت درج ہے کہ حصولِ علم ہرمسلمان پر فرض ہے۔ اس فرمانِ رسولؐ میں ’ہرمسلمان‘ کہہ کر مرد اور عورت کی تفریق ختم کرتے ہوئے، بلاامتیاز دونوں کے لیے علم کا حصول لازم قرار دیا گیا ہے۔
علم انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علم و حکمت کا حصول اسلام کے اعلیٰ مقاصد میں سے ایک ہے۔
کسی قوم کی سیاسی اور معاشی کامیابی کا براہ ِ راست تعلق وہاں پردی جانے والی تعلیم اور اس کی نوعیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہر شعبے کے لیے موزوں ترین افراد کا انتخاب اور ان کی تربیت کا اہتمام کرتا ہے۔ لہٰذا سب سے زیادہ باصلاحیت، ماہر اور قابل لوگ ایسے معاشروں ہی میں پائے جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اس سے قریب ترین مثال اندلس (موجودہ اسپین اورپرتگال) کی ہے جب وہاں اسلامی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ مگر آج عبرت کا مقام ہے کہ جدید دُنیا کا کوئی مسلمان اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ دُنیا کی سو بہترین یونی ورسٹیوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو کسی مسلمان ملک میں قائم کی گئی ہو۔ شاید ہی کوئی مسلم کمپنی یا برانڈ ایسا ہوگا جسے بین الاقوامی شہرت یا مقام حاصل ہوگا۔ گاڑی سے لے کر ہوائی جہاز اور موبائل فون سے لے کر لیپ ٹاپ تک ہمارے استعمال کی ہرچیز غیرمسلم ذرائع سے حاصل کردہ ہے۔
ٹکنالوجی کے میدان کا نقشہ بدل دینے والے الگورتھم (Algorithm)، کمپیوٹنگ (Computing) کی بنیاد ہیں، جنھوں نے آج ایپل (Apple) برانڈ کو دُنیا بھر میں مقبول کردیا ہے۔ حساب کا یہ کلیہ نویں صدی کے عظیم ترین محقق اور حساب دان الخوارزمی نے اپنی کتاب حساب الجبر والمقابل میں پیش کیا لیکن مقامِ افسوس ہے کہ اس سے مسلمان کوئی فائدہ نہیں اُٹھا سکے۔ اسی طرح طبّ کے میدان میں ابن سینا اور بصری علوم میں ابن الہشام کے کارنامے صدیوں تک جدید ایجادات کی بنیاد بنے رہے۔ آج بھی اوکسفرڈ یونی ورسٹی کی بوڈلیئن (Bodleian) لائبریری میں عربی زبان میں لکھی گئی ایسی کئی تاریخی تصنیفات موجود ہیں۔ حصولِ علم سے بے پرواہی اور دانش و حکمت کے حصول میں دلچسپی نہ رکھنے کا نتیجہ ہے کہ آج دُنیا کے کامیاب ترین اداروں اور راہ نمائوں میں مسلمانوں کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے۔
دُنیا کے کم و بیش تمام مشہور ترین برانڈز کا تعلق غیرمسلم دُنیا سے ہے۔ فوربز میگزین نے ایک دفعہ ایک مضمون شائع کیا تھا، جس کا عنوان تھا: ’وہ چارکمپنیاں جو ان ۴۷ کمپنیوں کو کنٹرول کرتی ہیں جو دُنیا کی ہر شے کی مالک ہیں‘۔ اس کی اَن گنت وجوہ ہوسکتی ہیں جیساکہ حکومتوں کے غیرجمہوری رویے، افراد یا کمپنیوں کے غیرقانونی ہتھکنڈے یا پھر بادشاہت کے خاتمے کے بعد ملکوں کی ترقی میں عدم توازن وغیرہ۔ لیکن وجوہ چاہے کچھ بھی ہوں غیرمسلم بہرحال اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ترقی کے لیے نت نئی مہارتوں کا حصول اور اپنی قابلیت میں اضافہ ناگزیرہے۔ ہرمیدان میں کامیابی غیرمسلموں کے حصے میں آتی ہے کیوں کہ اب مسلمانوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور سیکھنے کی لگن نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف ماضی کی عظمتوں کے گُن گاتے رہنے سے حال کے چیلنجوں اور بدحالی کا خاتمہ نہیں کیا جاسکتا، بلکہ ماضی کی طرح علم و حکمت کی جستجو اور اپنی اہلیت میں اضافے کی مسلسل کوشش کرکے ہی بین الاقوامی پیشہ ورانہ معیار کے حامل افراد تیار کیے جاسکتے ہیں، جو اپنے اداروں اور معاشرے کی ترقی میں بھرپور حصہ ڈال سکیں۔
ایک کامیاب انسان زندگی کے مختلف پہلوئوں پر دسترس رکھتا ہے اور مختلف شعبوں میں اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ عمومی دانائی اور حکمت کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے مخصوص شعبوں میں اعلیٰ درجے کی مہارت یا اسپیشلائزیشن حاصل کرنے پر بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر ٹکنالوجی کے شعبے میں جدت اور تخلیقی صلاحیت بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اکائونٹنگ کے شعبے میں ان دونوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں بلکہ وہاں پر باریک بینی اور حساب کتاب میں حاضر دماغی زیادہ اہم ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اپنی ٹیم سے بھرپور طریقے سے کام لینے کے لیے ضروری نہیں کہ لیڈر خود شعبے میں مکمل تکنیکی مہارت رکھتا ہو۔ لیڈر کے پاس علم اور ہنر دونوں ہونے چاہئیں، لیکن اس کا اصل ہنر لوگوں کی مہارتوں اور صلاحیتوں کو موزوں ترین طریقے سے استعمال کرکے ان کے بہترین نتائج حاصل کرنا ہے۔ ہرشعبے کو احسن طریقے سے سنبھالنا اور اس سے بہترین نتائج حاصل کرنا نبی کریمؐ کے قائدانہ کردار کی ایک اور اعلیٰ خصوصیت تھی، جس کی عملی مثالیں آپؐ کی زندگی کے ہر ہر پہلو میں دیکھی جاسکتی ہیں۔(نبیل الاعظمی کی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم: گیارہ قائدانہ اوصاف کا باب، انگریزی سے ترجمہ: رافعہ تحسین)
مقاصد شریعہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اجتہادی عمل کے ذریعے معاشرے کے پیش آمدہ مسائل اور درپیش مشکلات کو حل کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی کم از کم اتنی تربیت ضرور ہو، کہ ان میں باہم وحدت و اجتماعیت کا شعور پیدا ہو، تاکہ لوگوں کا اپنے اعتقاد، نظریے اور تہذیب کے ساتھ تعلق مضبوط بنیادوں پر قائم ہو۔ جب معاشرے کے عام لوگوں میں اپنے نظریہ کا شعور اُجاگر ہوتا ہے، تو ان کا اپنے دور کے ان اہلِ علم و دانش کے ساتھ بھی قلبی تعلق پیدا ہوجاتا ہے، جو اپنے دور کے مسائل کو حالات کے تناظر میں سمجھتے ہوں اور ان کا حل اجتماعی یا شورائی اجتہاد کے ذریعے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ عوام اور اہلِ علم و دانش کے مابین تعلق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو بھی معاملات اور ان کے حل کے لیے اجتماعی کوششوں کو سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس اجتماعی شعور کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف نہ صرف قانون سازی کا عمل بہتر ہوتا ہے بلکہ قانون نافذ ہونے کے بعد اس پر عمل درآمد کی صورت بھی بہتر ہوجاتی ہے۔
کسی ملک اور قوم کے حالات میں مثبت اور تعمیری تبدیلی اسی وقت ممکن ہوتی ہے، جب لوگ خود فکر کی بلندی اور اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عظیم الشان کام ملک کے اہل علم و دانش اور قائدانہ صلاحیت رکھنے والے افراد انجام دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:
اِنَّ اللہَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِہِمْ۰ۭ (الرعد۱۳: ۱۱) حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔
اس آیت مبارکہ میں فطرت کا ایک اصول یہ بیان کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنے انعامات سے اس وقت تک محروم نہیں کرتا، جب تک وہ خود اپنے آپ کو علم و شعور اور ان اخلاقی اقدار سے محروم نہ کر لیں جو انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقاء اور کامیابیوں کے لیے ضروری ہیں۔ اس مفہوم کی وضاحت اور بھی بہت سی آیات میں بیان ہوئی ہے۔
ان آیات مبارکہ میں انسانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے عروج و زوال کا ایک اصول اور ضابطہ مقرر کیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں بہت سی فطری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، خیر کی صلاحیتیں بھی ودیعت کی ہیں اور شر کی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں۔ خیر کی صلاحیتوں کو اُجاگر کرنے اور انھیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے باقاعدہ انبیا علیہم السلام کو بھیجا، تاکہ وہ خیر و شر کے فرق کو سمجھا کر انسان کو فلاح و سعادت کے راستہ پر گامزن کریں۔ اب اگر انسان خیر کی صلاحیتوں کو بھلائی کے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ عروج و کمال کو حاصل کر لے گا اور اگر خواہشاتِ نفس کی پیروی کرتے ہوئے شر کی طرف مائل ہوگا، تو اس کے اپنے تخریبی کرتوت اسے زوال اور مصائب میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانونِ فطرت ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا مستحق بننے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے اور وہ کون سا راستہ ہے جو زوال و تباہی کی طرف دھکیل دیتا ہے، جس سے ہر صورت بچنا چاہیے؟
اصل موضوع پر گفتگو سے قبل یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہجِ اصلاح و دعوت پر روشنی ڈال لیں تاکہ مسائل کے حل میں رسولؐ اللہ کا طرزِعمل اور آپؐ کی رہنمائی اچھی طرح واضح ہوجائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہذب اور منظم معاشرے کی تشکیل کے لیے دوچیزوں کی طرف توجہ فرمائی: ایک انسانی فکر کی اصلاح اور دوسری انسانی رویے کی اصلاح۔ اصلاحِ فکر کے لیے حصولِ علم کو فرض قرار دیا اور توحید کی بنیاد پر عقیدہ کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ انسان ہر قسم کی توہم پرستی اور شرک کی ہر صورت سے محفوظ ہوجائے۔ انسانی رویوں کی اصلاح کے لیے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی اور فارمولا نہیں ہوسکتا۔ اخلاقی اصول، عالمی صداقتوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی صحیح الفطرت انسان ان کی خوبیوں کا انکار نہیں کرسکتا۔ اخلاقِ حسنہ اپنے اندر بےپناہ قوت اور دور رس تاثیر رکھتے ہیں۔ دُنیوی زندگی کا کوئی شعبہ اخلاقی اصولوں کو نظر اندازکرکے کامیابی کی شاہراہ پر آگے نہیں بڑھ سکتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بنیادی ستونوں پر اسلامی معاشرے کی تشکیل فرمائی: علم، ایمان اور اخلاق___ یہ تینوں ستون اس قدر اہم ہیں کہ ان میں کوئی ایک ستون بھی منہدم ہوجائے تو سارا معاشرہ زوال کا شکار ہوجاتا ہے۔ تہذیب و تمدن کے استحکام اور ارتقاء کے لیے تینوں لازمی بنیادوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔
سرفہرست بنیادی ستون علم ہے۔ علم محض معلومات کو جمع کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اشیاء کی حقیقت کے ادراک اور اس فہم کا نام ہے، جو معلومات کو منظم انداز میں ترتیب دے کر ان سے نتائج اخذ کر سکے اور اپنے اندر استدلال و استنباط کی صلاحیت کو مضبوط کر سکے۔
علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں علم کی دولت عطا فرماکر بھیجا۔ حضرت آدمؑ جب تک جنت میں رہے ملائکہ کی صحبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی عبادت اور تسبیح و تقدیس کا علم حاصل کیا۔ پھر دنیا میں بھیجا تو وہ علوم بھی عطا فرمائے، جن کی دُنیوی زندگی میں ضرورت پڑ سکتی تھی۔یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کی دُنیوی زندگی کا آغاز وحی الٰہی کی رہنمائی اور علم کی روشنی میں ہوا۔
دنیا میں نسلِ انسانی کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اسے حصولِ علم کے وسائل (Tools) بھی عطا فرمائے تاکہ وہ سمع و بصر، عقل و حواس، مشاہدے اور تجربہ سے اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرتا رہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے پہلا سبق یہی پڑھایا گیا کہ وہ اپنی تمام تر توجہ حصولِ علم پر مرکوز کر دے۔ سورۂ علق کی ابتدائی پانچ آیات پر غور کیجیے۔ وحی کا آغاز ہی صیغۂ امر سے ہو رہا ہے۔ ‘إقرأ’ پڑھیے، ان پانچ آیات کے اسلوبِ بیان کو دیکھیے کہ حصولِ علم کو کس قدر زورِ بیان کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان کا پڑھائی، کتاب و قلم، تعلیم و تعلم اور بحث و تحقیق کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔
صحابہ کرامؓ جو عربی زبان کی بلاغت اور اسلوبِ بیان سے اچھی طرح واقف تھے، انھوں نے ان آیات کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھا۔ انھیں اس بات کا ادراک تھا کہ ایمان و عبادت کی حقیقت کو سمجھنے، زندگی کے انفرادی اور اجتماعی امور کو طے کرنے اور درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر انسان نہ دُنیوی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ اُخروی زندگی ہی میں نجات و فلاح پاسکتا ہے۔
علم ایک بحرِ بےکراں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح انسان کے حالات اور مسائل بھی گونا گوں ہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے میں نئے نئے مسائل اُبھرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر دور اور ہر زمانے میں علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور و فکر سے کام لیا جائے تو علوم و فنون کے نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں، اور انھی میں اپنے مسائل اور درپیش تحدیات کا حل بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ علم بھی عطا فرمایا جو قطعی اور یقینی ہے۔ یہ علم وحی کے ذریعے انبیا علیہم السلام پر نازل ہوا ہے۔
اُمتِ مسلمہ کے پاس علومِ وحی کا سرمایہ قرآنِ حکیم اور سنت نبویؐ کی صورت میں محفوظ ہے، لہٰذا مسلمان اہلِ علم کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ان تصوراتِ علم کو جنھیں وہ اپنی عقل اور حواس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں علومِ وحی کی روشنی میں پرکھ لیں، اس لیے کہ عقل و حواس کے ذریعے جو رائے قائم ہوتی ہے وہ ظنی کہلاتی ہے، اس میں خطا اور غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ ظن و تخمین پر مبنی رائے کو پرکھنے کے لیے علمِ قطعی کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنِ حکیم کے مضامین اور احکام کی وضاحت اور تشریح کا حکم دیا ہے۔ (النحل۱۶: ۴۴)
اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے اُمتِ مسلمہ کو اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہےکہ وہ اپنی عقل اور حواس کو استعمال کرکے وہ علوم اور تربیت ضرور حاصل کریں، جو نہ صرف اُمتِ مسلمہ کی فلاح و سعادت کے لیے ضروری ہیں بلکہ ساری انسانیت کے امن و سکون کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ان علوم کا تعلق تزکیۂ نفس، احسان اور اخلاقِ کریمہ سے ہے۔ جس قوم کی تعلیم و تربیت تزکیۂ نفس اور احسان کے ذریعے کی گئی ہو اور جس کا مزاج اعلیٰ اخلاقی قدروں کے مطابق ڈھل گیا ہو، وہ قوم ایسے اُمور، فن کاری یا فتنہ کی طرف توجہ نہیں دیتی، جس کا مقصد ہی تخریب کاری یا فتنہ و فساد پھیلانا ہو۔
آج کے دور میں تخریب کاری اور دہشت گردی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اس فتنے میں صرف چند پراگندہ ذہنیت کے لوگ ہی ملوث نہیں بلکہ بعض بڑی بڑی حکومتیں بھی تخریب کاری کے عمل کو منظم کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کی قائم کردہ خفیہ ایجنسیوں، مثلاً ’سی آئی اے‘ ، ’موساد‘ اور ’را‘ (RAW) وغیرہ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔
مسلم اُمہ کو دیگر اقوام کے ساتھ مل کر بیرونی اور اندرونی، ریاستی اور اداراتی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مسلم امت اجتماعی طور پر یا پھر کوئی ایک مسلم مملکت یہ فریضہ اس وقت انجام دے سکتی ہے، جب کہ وہ نہ صرف علوم و فنون میں نمایاں حیثیت حاصل کرلے بلکہ سیاسی اور معاشی طور پر بھی مستحکم ہو۔ فکری استحکام کے لیے علمی وسعت کے ساتھ راسخ ایمان و اعتقاد بھی ضروری ہے۔ ایسا ایمان، جو اسلامی معاشرے کا دوسرا بنیادی ستون ہے۔ ایمان تصدیقِ قلبی کا نام ہے، جو یقینِ کامل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ایمان دل و دماغ میں راسخ ہوتا ہے تو انسان کی عملی اور اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
ایمانیات میں تین عقیدے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت___ باقی عقائد انھی تین کا حصہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ذات تو پردۂ غیب میں ہے۔ انسان کو جو کچھ علم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و تقدس، اس کا کائنات کی ہر چیز پر اقتدار، اس کا وسیع و جامع علم، اس کی گرفت اور حساب و کتاب پر قدرت کے بارے میں جب غور کرتےہیں تو انسانوں کے دل خشیتِ الٰہی سے لبریز ہوجاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفاتِ رحمت، عفو و درگزر اور اس کے انعامات و احسانات پر غور کرتے ہیں، تو اہل ایمان کے دلوں میں بےپناہ جذبۂ محبت پیدا ہوتا ہے۔ ان کے قلوب میں شکر و امتنان کے جذبات کا سیلاب اُمنڈ آتا ہے۔ نتیجتاً بندہ مؤمن نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیمِ خم کر دیتا ہے۔
انبیا علیہم السلام جس خطہ اور جس قوم میں مبعوث ہوئے، ان کی زبان و ادب پر انھیں عبور حاصل تھا۔ ان کے حالات اور سماج سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ تہذیب و اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ابلاغ کا فريضہ انجام دیتے تھے۔ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے منصب ِنبوت پر فائز کیا، انھیں یہ تمام صلاحیتیں عطا فرمائیں، پھر انھیں معلم و مربی کی حیثیت میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا منصب عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے معلم و مربی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دنیا بھر کے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قیادت و سیادت کا فريضہ صحیح طور پر وہی انجام دے سکتا ہے، جس کی اپنی زندگی، اپنا کردار اور اپنے اعمال بنی نوع انسان کے لیے مثالی نمونہ ہوں۔
مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور تقریرکے ذریعے جو دین ہم تک پہنچا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ اسی لیے دین کی تعلیمات، اس کے عطا کردہ احکام اور اصول و قواعد میں تقدس اور عظمت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یہی وہ عنصر ہے جو لوگوں کے دلوں میں دینی احکام کے لیے احترام کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور اہل ایمان کو احکام و قوانین پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی جذبہ معاشرے کو تہذیب و اخلاق کے دائرے میں رکھنے اور عملی زندگی میں احکام و قوانین پر آمادۂ عمل کرنے میں ایک قوی محرک کے طور پر کام کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا بھر کے انسانوں کے لیے محض نظری یا تصوراتی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سراسر عملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو پیغام دیا ہے، سب سے پہلے اس پر خود عمل پیرا ہوکر عملی نمونہ بھی پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی پیش کی، یہاں تک کہ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی مثالی نمونہ کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش فرمائی:
فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُـرًا مِّنْ قَبْلِہٖ۰ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۱۶(یونس ۱۰: ۱۶) میں نے نبوت سے پہلے بھی تمھارے درمیان رہ کر زندگی گزاری ہے کیاتم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟
عقیدۂ آخرت کوئی فلسفیانہ تصور نہیں ہے، بلکہ فطرت اور عقلِ سلیم کے مطابق ہے۔ آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو کر اپنی دُنیوی زندگی کے اعمال کا حساب دینے کا یقین، دُنیوی زندگی سے متعلق انسان کا نقطۂ نظر مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ اس عقیدے کو تسلیم کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو پوری طرح ذمہ دار سمجھتا ہے، اور وہ دُنیوی زندگی سے متعلق فیصلے کرتے ہوئے آخرت کی دائمی زندگی کو نظر انداز نہیں کرتا۔
مومن کی زندگی میں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک، احساسِ شکر و امتنان، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا کے حصول کا شوق اور جنت کی نعمتوں اور پُرسکون زندگی کی کشش اسے اعمالِ صالحہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے اعمال کا محاسبہ، اللہ کی ناراضی کا ڈر اور عذابِ جہنم کی شدت انسان کو منکر، فحشا، فتنہ و فساد اور بغی و ظلم سے روکتی ہے۔
اس دُنیا میں انسان کا قیام عارضی ہے۔ انسانی تاریخ میں ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ ہر آنے والا انسان موت کا شکار ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ہر فرد ایک مختصر زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ دنیا کا نظام کچھ ایسا ہے کہ یہاں نہ تو انسان کو اس کے اچھے اعمال کی پوری پوری جزا مل سکتی ہے اور نہ بُرے اعمال کی پوری سزا مل سکتی ہے۔ باقی وقتی طور پر مکافاتِ عمل کے لیے کچھ قوانین جزا و سزا طے کر لیے جاتےہیں تاکہ دُنیوی معاشرہ میں امن و سلامتی کی صورت حال برقرار رکھی جاسکے۔ لیکن ان قوانین اور ضابطوں کے باوجود بھی ایسے جرائم وقوع پذیر ہوتے ہیں، جن کا ارتکاب کرنے والے قانون اور جرائم کو کنٹرول کرنے والے اداروں کی گرفت میں نہیں آپاتے، اور انھیں کوئی سزا نہیں ملتی۔ حقیقت یہی ہے کہ دُنیوی اعمال کی حقیقی پوری جزا و سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عدالت سے مل سکتی ہے۔ آخرت پر ایمان ہی انسان کو منکرات سے روک کر تعمیر و اصلاح اور معروف کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔
علم و ایمان کے ساتھ تیسرا بنیادی ستون اخلاق ِ حسنہ ہے۔ جس طرح اسلام میں علم اور ایمان و عقیدہ کو اہمیت حاصل ہے اسی طرح کریمانہ اخلاق کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خیر و شر، نیکی اور بدی کی پہچان رکھی، اچھے اور بُرے کے درمیان امتیاز کرنے کی حِس بھی رکھی ہے۔ یہ فطری صلاحیت بہت قدر و قیمت رکھتی ہے۔ انبیا علیہم السلام اپنی تعلیمات اور تربیت کے ذریعے اس حِس کو اس قدر طاقت ور کر دیتے ہیں کہ ان کا تربیت یافتہ انسان شر سے پوری کراہت کے ساتھ اجتناب کرتا ہے اور خیر کو صحیح جذبہ اور ذوق شوق کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت کا فريضہ تو اعلانِ نبوت کے بعد شروع فرمایا، لیکن اخلاقیات کی تعلیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نو عمری ہی سے دیتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی بالادستی کا سارا عرب معترف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظمت کا کبھی کسی دشمن نے بھی انکار نہیں کیا۔قرآن حکیم نے اس کی شہادت دی:
وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ۴ (القلم۶۸: ۴) اور آپ ؐیقیناً اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔
انبیا علیہم السلام انسانوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز اصلاحِ قلب اور تزکیۂ نفس سے کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں وہ ان امراض کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ان امراض میں نفاق، بغض، حسد، کینہ، حرص و لالچ، تعصب، نفرت و حقارت اور تکبر وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ایسے امراض ہیں جو انسان کے رویے، عادات و اطوار اور کردار کو بُری طرح بگاڑ دیتے ہیں۔ معاشرے کے یہی بگڑے ہوئے لوگ سارے معاشرے اور معاشرتی اداروں میں آلودگی اور فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں انبیاء علیہم السلام انسانی قلوب کو رذائل سے پاک صاف کرتےہیں، پھر فضائلِ اخلاق کی آبیاری کرتے ہیں، جن میں خاص طور پر اخلاص، صدق و امانت، تقویٰ، صبر و شکر، توکّل، ایثار و تواضع، رحم دلی وغیرہ جیسی اعلیٰ صفات کی جڑیں انسانی دماغ اور رویوں میں نہایت مضبوطی کے ساتھ پیدا کرتے ہیں۔
ان میں سے بعض اخلاقی فضائل بڑی جامعیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اخلاص کی صفت اخلاقیات میں سر فہرست ہے۔ یہ ایسی جامع صفت ہے جو صدق و امانت کے وسیع مفہوم کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ قلب ِمومن جب اخلاص کی صفت سے متصف ہوتا ہے تو اس کے ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا ہوتی ہے۔
اسلامی ادب میں تقویٰ بھی ایک جامع صفت ہے۔ قرآن حکیم میں تقویٰ کا لفظ مختلف صیغوں کے ساتھ بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اہل ایمان کے تمام اعمال، اخلاق، کردار اور رویوں کا محور تقویٰ ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو قلب و دماغ میں معروف اور خیر کے امور کو پرکھنے اور سمجھنے کا شعور پیدا کرتی ہے۔ تقویٰ کی صفت اہل ایمان میں تعمیر اور تخلیقی صلاحیتوں کو اُجاگر کرتی ہے، جن کا مظاہرہ وہ میدانِ عمل، تعلیم و تربیت، نظمِ مملکت و حکومت، خاندانی نظم، معیشت و معاشرت اور علوم و فنون کی ترویج میں کرتے ہیں:
يٰٓاَيُّھَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللہَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا (الانفال۸: ۲۹) اے ایمان والو! اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمھیں وہ کسوٹی عطا فرمائیں گے جس کی بنیاد پر تم حق و باطل کے درمیان فرق کر سکو گے۔
تقویٰ کی صفت انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نکال کر کامیابی اور سکون و خوش حالی کی شاہراہ پر رواں کرتی ہے:
وَمَنْ يَّـتَّقِ اللہَ يَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا۲ۙ وَّيَرْزُقْہُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۰ۭ (الطلاق۶۵: ۲، ۳) جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات سے نجات کی راہیں پیدا کر دیتے ہیں، اور ان پر رزق کے ایسے در کھول دیتے ہیں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔
وَمَنْ يَّتَّقِ اللہَ يَجْعَلْ لَّہٗ مِنْ اَمْرِہٖ يُسْرًا۴ (الطلاق۶۵: ۴) جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں سہولت پیدا کر دیتے ہیں۔
وَمَنْ يُّطِعِ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ وَيَخْشَ اللہَ وَيَتَّقْہِ فَاُولٰۗىِٕكَ ہُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ۵۲ (النور۲۴: ۵۲) جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔
ہمارے معاشرے میں عام طو رپر خطبا اور علما تقویٰ کی تشریح و تعبیر ذکر و اذکار، تسبیح و تہلیل، اعتکاف و تنہائی پسندی اور صوم و صلوٰۃ میں انہماک سے کرتے ہیں۔ یقیناً یہ سب چیزیں انسان کی تربیت اور تعلق مع اللہ کے لیے مفید ہیں۔ لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام امور کے ساتھ تقویٰ کی واضح جھلک خاندانی معاملات، تجارت، معاشرتی اُمور، ملکی نظم و نسق اور بین الاقوامی امور حل کرتے ہوئے بھی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ خلفائے راشدینؓ اور صحابہ کرامؓ کے حالات کا مطالعہ کیجیے تو وہاں بھی تقویٰ لوگوں کی تخلیقی اور تعمیری و رفاہی کاموں میں انہماک پیدا کرنے والی صفت کے طور پر نظر آتا ہے۔ گویا تقویٰ معاشرہ میں خیر خواہی کے جذبہ کے ساتھ فلاح و بہبود کے کاموں میں متحرک رکھنے والی طاقت و صفت ہے، جو ذکر و اذکار، تسبیح و تلاوت کے ساتھ لوگوں کے باہمی معاملات، نظمِ معیشت اور سیاست و حکومت میں بھی مؤثر ذریعہ ہے۔
مذکورہ تینوں عناصر اسلامی معاشرہ کے قیام و استحکام کے لیے بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی اعلیٰ تہذیب وجود میں نہیں آسکتی۔ جب تک معاشرے میں کوئی ایسی تہذیب وجود میں نہیں آتی، جو علم، ایمان اور اعلیٰ اقدار و روایات پر قائم نہ ہو ملک اور معاشرے میں آئین و دستور اور قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوسکتی، نہ کوئی مستحکم معاشرہ تکمیل پاسکتا ہے۔
اس ملک پر حکمرانی کرنے والوں نے ہمیشہ مذکورہ تینوں عناصر کو بری طرح نظر انداز کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے تقریباً سبھی ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ رشوت، چور بازاری، دھوکا بازی اور بےراہ روی کا دور دورہ ہے۔ ہر ادارہ اور ہر شعبہ بدعنوانی کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔
اس اہم کام کے لیے حکومت کا کردار اپنی جگہ لیکن یہ کام اپنی سطح پر کرنا ہوگا۔ اگر دینی مدارس اور مساجد کے ذمہ داران اجتماعی طور پر ایک منظم تحریک کی صورت میں کام کریں تو یقیناً اس کے مثبت اثرات جلد ظاہر ہونے لگیں گے۔
تعلیم اور تربیتِ اخلاق کا کام ملک کے سارے لوگوں کے لیے بہت منظم تحریک کی صورت میں انجام دیا جاسکتا ہے۔ سرکاری نظم میں چلنے والے تعلیمی ادارے تو تقریباً ناکامی کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ نجی شعبہ میں اکثر کے پیش نظر محض دولت کمانا یا کچھ تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، لیکن مجموعی طور پر تربیت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔
ملک کے خیر خواہ اور صاحبِ استطاعت لوگوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے اور اعلیٰ معیار کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینا ہوگی، اور ملک کے ہر شہری کو حصولِ علم اور تربیتِ اخلاق کی سہولت مہیا کرنا ہوگی، البتہ مسلمان طلبہ کے لیے ایمان و عقیدہ اور فہم دین کی تعلیم کا خصوصی انتظام ہرصورت میں کرنا ہوگا۔ ملک میں بہت سے رفاہی کام کرنے والے ادارے، مثلاً یتیم خانے، ہسپتال، غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے بعض ادارے بھی اس تحریک میں شامل ہو کر اسے مزید مؤثر بنا سکتے ہیں۔
حُسن معاشرت، تمدن کی روح ہے۔ اس کا دارومدار معاشرے میں قائم ایک اعلیٰ تہذیب پر منحصرہے۔ انسانی معاشرے میں وہی تہذیب پائیدار ہوتی ہے، جو علمِ نافع، ایمانِ راسخ اور اخلاقِ کریمہ کی بنیادوں پر قائم ہو۔ محض آئین اور قانون کی بنیاد پر نہ کوئی تہذیب قائم ہوتی ہے، نہ تمدن آگے بڑھتا ہے، البتہ اگر مذکورہ اصولوں کی بنیاد پر کوئی تہذیب وجود پا چکی ہو اور ملک و معاشرہ میں تمدن ارتقائی مراحل طے کرنے لگا ہو، تو ایسے معاشرے میں دستور اور قانون بھی مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آئین و قانون کی پشت پر علم و ایمان اور اخلاق کی قوت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ قوت معاشرے کے افراد کے رگ و پے میں رچی بسی ہوتی ہے۔
اگر ہم مذکورہ تین عناصر کو معاشرے میں متعارف کرا سکیں اور ایک اسلامی تہذیب کی بنیاد ڈال دیں، تو پھر تمام مسائل کا حل بھی نکل آئے گا اور ترقی کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ ان شاء اللہ، وھو المستعان۔
ہم ۳۰دسمبر ۲۰۲۴ء کو ڈھاکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اُترے تو سب سے پہلے جس جنّتی روح کا تذکرہ ہوا، وہ عبدالمالک شہیدؒ تھے۔ ’اسلامی چھاترو شبر‘ کے امور خارجہ کے سیکریٹری ہمیں ائیرپورٹ پر لینے آئے تھے۔ باہر نکلتے ہی شہید عبدالمالک کا تذکرہ چھڑ گیا، اور بنگال کی سرزمین پر اسلام کے فداکاروں کے قافلۂ سخت جان کی ساری قربانیاں چمک اُٹھیں۔
’افسو‘ (IIFSO) کی مرکزی ٹیم کے ساتھ’ اسلامی چھاترو شبر‘ کے سالانہ اجتماع ارکان میں شرکت کے احساس سے ہی دل ایک عجیب کیفیت سے سرشار تھا۔ ’اسلامی چھاترو شبر‘ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اور منظم طلبہ تحریک ہے۔ سابق وزیراعظم حسینہ واجد کی ۱۵سالہ ظالمانہ حکمرانی کے اختتام پر، ملک کی یہ سب سے بڑی طلبہ تنظیم پہلی بار کھلے میدان میں اپنا اجتماع ارکان منعقد کررہی تھی، جس میں کارکردگی کے جائزے اور تربیتی و فکری پروگراموں کے ساتھ تنظیم کے نئے مرکزی صدر (ناظم اعلیٰ) کا انتخاب بھی ہونا تھا۔ اجتماع ۳۱ دسمبر ۲۰۲۴ء کو منعقد ہونے جارہا تھا۔ ہم ائیرپورٹ سے نکل کر پرانے ڈھاکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں پر دسمبر کی ہوا میں سردی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ڈھاکہ بڑی گنجان آبادی والا شہر ہے، اور یہاں ٹریفک کے بڑے گمبھیر مسائل ہیں۔ سڑکوں پر لوگوں اور ٹریفک کا رش ایک جیسا ہے۔
میزبانوں نے ہمیں پرانے ڈھاکہ کے ایک ہوٹل میں ٹھیرایا۔ اس دن اگرچہ کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن ڈھاکہ یونی ورسٹی سے متصل تاریخی ریس کورس گراؤنڈ میں شبر کے اہتمام سے بنگلہ دیش میں پہلا سب سے بڑا ’سائنس فیسٹیول‘ اختتام پذیر ہورہا تھا۔ شام کو شبر کے دوست بیرونِ ملک سے آنے والے مندوبین کو فیسٹیول میں لے گئے۔ ’ابن الہیثم سائنس فیسٹیول‘ میں شام کے وقت بھی طلبہ کی ایک بڑی تعداد آرہی تھی۔ خوب صورت انداز میں ترتیب دی گئی اس سائنسی نمائش کو کئی دلچسپ حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس میں طلبہ نے اپنے بنائے سائنسی پروجیکٹوں کے نمائشی مقابلے میں حصہ لیا۔ قرآن اور سائنس کے حوالے سے مسلم سائنس دانوں، علمی شخصیات اور فلسفیوں کے کام کو اجاگر کرنے والا ایک حصہ بھی نمائش میں شامل تھا۔ جدید سائنسی ایجادات اور آرٹیفیشل انٹیلی جنس (AI)کے حوالے سے معلومات سے بھرپور ایک حصہ نمائش میں شامل تھا۔ مختلف کمروں سے گزرنے کے بعد شرکاء آخری کمرے میں اسلامی چھاترو شبر کے تعارف پر مبنی، خوب صورتی سے سجائے گئے ایک کمرے سے گزرتے تھے۔ اس کمرے میں ایک قدِ آدم اسکرین لگی ہوئی تھی، جہاں شبر کے کام سے اتفاق کرنے والے طلبہ، تنظیم میں شمولیت کا فارم بھر سکتے تھے۔ اس دلچسپ دورے کے بعد ہم واپس ہوٹل آئے۔
ہوٹل میں اسلامی چھاترو شبر کے ناظم اعلیٰ منظور الاسلام ہم سے ملنے آئے۔ چہرے پر سجی مسکراہٹ، سادگی، محبت کا پیکر اور ملک کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم کے سربراہ سے ملنا ایک خوش گوار تجربہ تھا۔ ہم براہ راست کوئی بات نہیں کرپائے، شبر کے ساتھی نے ترجمانی کی ذمہ داری انجام دی۔ اسلامی چھاترو شبر کے مرکزی نظام پر ایک مختصر سی گفتگو ہوئی۔
اگلے روز ۳۱ دسمبر ۲۰۲۴ء کو اسلامی چھاترو شبر کا اجتماع ارکان، ۱۵ سال کے طویل وقفے کے بعد پہلی بار، ڈھاکہ کے تاریخی ریس کورس گراؤنڈ میں منعقد ہورہا تھا۔ ملک بھر سے آئے ہوئے تقریباً سات ہزار ارکان کے علاوہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی مرکزی قیادت، دیگر دینی و سیاسی تنظیموں کے سربراہان اور حالیہ طلبہ انقلاب میں مرکزی کردار ادا کرنے والے طلبہ رہنما بھی موجود تھے۔
’اسلامی چھاترو شبر‘ کا سالانہ اجتماع ارکان جوش و ولولے کے ایک ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند تھا۔ شبر کے ناظم اعلیٰ کی ولولہ انگیز تقریر سے اجتماع کا آغاز ہوا۔ چھاترو شبر کے سابق قائدین کی تقاریر، جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر اور قیم جماعت نے بھی خطاب کیا۔ مختلف دینی، سیاسی تنظیموں کے قائدین کے ساتھ حالیہ طلبہ انقلاب کے رہنماؤں، بیرون ملک سے آنے والے طلبہ مندوبین کی تقاریر اجتماع ارکان کے پہلے حصے میں پیش ہوئیں۔ تقاریر کے دوران اسلامی چھاترو شبر کے ارکان کا جوش اور نظم و ضبط دیدنی تھا۔
ان تقاریر میں ایک منفرد تقریر، جماعت اسلامی کے ایک مقامی ذمہ دار کی تھی، جن کا بیٹا حالیہ طلبہ تحریک میں شہید ہوا تھا۔ اس تقریر کے دوران کوئی آنکھ نم ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور تقریر کا اہم حصہ تو وہ تھا جب شہید کے والد نے حسینہ واجد کے آمرانہ دور کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ ’’میرے بیٹے کی شہادت بنگلہ دیش میں اسلامی نظامِ حیات کے قیام کے لیے ہوئی ہے، اور بنگلہ دیش کی سرزمین کسی بھی صورت میں اسلام دشمنی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے اس کے لیے کتنے ہی بیٹوں کا لہو درکار ہو‘‘۔
ظہر اور ظہرانے کے بعد اجتماع ارکان کا دوسرا سیشن منعقد ہوا جس میں اسلامی چھاترو شبر کے ناظم اعلیٰ کا انتخاب اور نتیجے کا اعلان ہوا۔ سال ۲۰۲۵ء کی میقات کے لیے ارکان نے زاہد الاسلام کو ناظم اعلیٰ منتخب کیا۔ ان کی حلف برداری کا نظارہ بڑا رقت انگیز اور ایمان افروز تھا، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسلامی تحریکات میں کوئی بھی عہدہ اپنے ساتھ ایک بھاری احساسِ ذمہ داری اور آخرت میں بازپُرس کا احساس دلاتا ہے، اور اسی لیے اسلامی تحریکات میں عہدہ ملنے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ زاہدالاسلام پچھلی میقات میں شبر کے سیکریٹری جنرل کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ انگریزی لٹریچر میں ماسٹرز کے بعد، اب وہ بین الاقوامی تعلقات میں ایم اے کررہے ہیں۔ نرم طبیعت کے حامل زاہد بھائی کے چہرے سے ذہانت مترشح ہے، ان شاء اللہ۔ وہ سخت ترین حالات کا کامیابی سے مقابلہ کرنے والی طلبہ تنظیم کو آزاد فضا میں نئی بلندیوں تک لے جائیں گے، اور بنگلہ دیش کی تعمیر و ترقی میں ’اسلامی چھاترو شبر‘ کے ارکان کی بہترین رہنمائی اور قیادت کریں گے۔
اسی روز، شام کے وقت جماعت اسلامی ڈھاکہ سٹی (شمالی) کے ذمہ داران نے غیرملکی مندوبین کے لیے عشائیے کا اہتمام کیا تھا۔ جماعت اسلامی نے ڈھاکہ شہر کو جنوبی اور شمالی، دو تنظیمی اکائیوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس خصوصی نشست میں جماعت اسلامی کے دعوتی اور سماجی کام کے بارے میں واقفیت حاصل ہوئی۔ ڈھاکہ جیسے بڑے شہرمیں جماعت اسلامی کی دعوتی و سماجی سرگرمیاں کافی دلچسپ ہیں۔ جماعت اسلامی دعوتی پروگرام کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے میں سرگرمِ عمل ہے۔ خدمت خلق کے ذریعے رضائے الہٰی کا حصول، عوام سے رابطہ، اور اس ضمن میں نئے تجربات کے حوالے سے ڈھاکہ شہر کی جماعت سے معاصر دینی تحریکات کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔
ڈھاکہ ایک بہت بڑا شہر ہے، اور اس طرح کے شہروں میں گھریلو سروسز کا حصول ایک مشکل عمل ہے۔ پچھلے چھ سال استنبول میں رہ کر ہم نے جس چیز میں لوگوں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا، وہ قابل اعتماد اور مناسب گھریلو سروسز ہیں۔ جماعت اسلامی ڈھاکہ نے ۲۰۱۹ء سے ایک متبادل دعوتی پروگرام کے تحت اس حوالے سے ایک منظم پروگرام کا آغاز کیا ہے، جو اعداد و شمار کے مطابق ایک کامیاب تجربہ رہا ہے۔ اس تجربے کے بارے میں دنیائے عرب، جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے اسلامی تحریکات کے قائدین مزید تفصیلات جاننے کے لیے سوالات کررہے تھے۔ شاید اسی منظم دعوتی پروگرام، اور جماعت اسلامی ڈھاکہ کی باصلاحیت قیادت کا نتیجہ ہے کہ صرف ڈھاکہ شہر (شمالی) ضلع میں جماعت اسلامی کے گیارہ ہزار ارکان ہیں، جن میں پانچ ہزار خواتین ارکان شامل ہیں۔ ارکان کے علاوہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب کارکنان اور ۲۵لاکھ ہمدردان صرف شہر کے ایک حصے میں جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں۔
یہ اعداد و شمار سن کر اگلے روز ہم نے ڈھاکہ یونی ورسٹی کے وائس چانسلر اور حالیہ انقلاب میں طلبہ قیادت سے ملاقات کی، اور عام طلبہ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ ملائشیا اور انڈیا سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے ایک استاد سے میں نے بنگلہ دیش کی تازہ صورتِ حال کے بارے میں بات کی، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انھوں نے جماعت اسلامی کے حوالے سے کافی مثبت رائے کا اظہار کیا، حالانکہ وہ بی این پی کے حامی تھے۔ اسی طرح عام طلبہ سے بات کرتے ہوئے بھی بنگلہ دیشی سیاست میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا وزن محسوس ہوتا ہے۔ عوام میں اس مقبولیت کی وجہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی دعوتی و سماجی خدمات کے میدان میں منظم جدوجہد ہے۔
اگلے روز اسلامی چھاترو شبر اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے مراکز کا دورہ اور مرکزی قیادتوں سے ملاقات کا پروگرام تھا۔ صبح سویرے پرانا پلٹن ڈھاکہ میں اسلامی چھاترو شبر کے مرکز پر پہنچے۔ شبر کا مرکزی دفتر پندرہ سال تک مقفل رہا ہے۔ اس تمام مدت میں چوبیس گھنٹے پولیس ناکہ اس دفتر کی نگرانی کرتا رہا ہے۔ پندرہ سال تک بند رہنے کے باوجود دفتر کی موجودہ حالت کو دیکھ کر بے پناہ مسرت ہوئی۔ اگرچہ دفتر کی عمارت بڑی نہیں ہے، اور عمارت کی وسعت بھی کم ہے، لیکن کام کے حوالے سے یہ چھوٹا سا دفتر اپنے اندر ایک دنیا سموئے ہوئے ہے، اور اسلامی تحریک کے ساتھ وابستہ لاکھوں نوجوانوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔
اسلامی چھاترو شبر کے نئے سیکریٹری جنرل نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اسلامی چھاترو شبر کے مرکزی نظام کے تحت۱۶ سیکریٹریز مرکز میں ناظم اعلیٰ اور سیکریٹری جنرل کی معاونت کرتے ہیں۔ نشست میں سبھی شعبوں کے ذمہ داران موجود تھے، جنھوں نے اپنے شخصی تعارف کے علاوہ اپنے شعبہ جات کا مختصر تعارف بھی کروایا۔ شعبہ ادب کے ناظم کے مطابق اس وقت اسلامی چھاترو شبر چودہ رسائل کی اشاعت کررہی ہے، جن میں سے ہر رسالے کے مخاطب مختلف قارئین ہیں۔ ان رسائل میں ایک رسالے کی تعدادِ اشاعت ماہانہ ایک لاکھ ہے۔ میڈیا کا شعبہ دو ادارے چلاتا ہے، جہاں میڈیا کی پروفیشنل تربیت فراہم کی جاتی ہے، اور میڈیا کے شعبے میں پوسٹ گریجویشن پروفیشنل ڈپلوما بھی کروایا جاتا ہے۔ ملک بھر میں سو کے قریب آرٹ کے مراکز اسلامی چھاترو شبر کے زیرانتظام کام کر رہے ہیں۔ بزنس اسٹڈیز کے لیے ایک الگ سیکرٹری ہے، جس کا کام صرف اس شعبے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے اندر دعوتی و فکری کام کی نگرانی ہے۔ اس شعبے کے تحت ششماہی مجلّہ شائع ہوتا ہے، جو اسلامی اور معاصر معاشیات کے حوالے سے تحقیقی مقالوں کی اشاعت کرتا ہے۔ ملک بھر میں ۴۰ ہزار کتب خانے موجود ہیں، جن کی نگرانی مرکزی سطح کے ایک سیکرٹری کے ذمے ہے۔ انسانی وسائل کی بہترین تربیت و تنظیم کے حوالے سے مرکزی سطح کا ایک شعبہ قائم ہے۔ عالمی سطح پر ’گلوبل وارمنگ‘ اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے جن ممالک کو فوری خطرہ درپیش ہے، بنگلہ دیش ان میں سے ایک ملک ہے۔ اسلامی چھاترو شبر کا مرکزی سطح پر اس شعبے کے حوالے سے مختلف نوعیت کی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے ایک سیکرٹری موجود ہے۔
اسلامی چھاترو شبر کا یونٹ سطح سے لے کر مرکزی سطح تک کا نظام انتہائی منظم ہے۔ اس طلبہ تنظیم کے مثبت کام کو عام طلبہ بھی سراہتے ہیں۔ حالیہ دورے کے دوران ایک بنگالی صحافی سے گفتگو کا موقع ملا، جو اس وقت ایک غیرملکی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان کے بقول بنگلہ دیشی معاشرے میں جس شعبے میں بھی کسی باصلاحیت نوجوان کی ضرورت پڑ جائے، اسلامی چھاترو شبر کے تربیت یافتہ افراد ایک بہترین انتخاب ہیں۔
اسلامی چھاترو شبر کے جتنے بھی ذمہ داران اور ارکان سے ملنے اور باہم گفتگو کا موقع ملا، دوچیزوں نے بہت زیادہ متاثر کیا: تقریباً سبھی افراد کو فکری اور نظریاتی طور پر بہت ہی پختہ پایا، اور سب کی اسلامی تحریک کے ساتھ وابستگی کا جذبہ قابلِ تقلید بھی ہے اور قابلِ رشک بھی۔ لیکن دوسری جس چیز نے بہت زیادہ متاثر کیا وہ ان نوجوانوں کا تعلیمی کیرئر اور پیشہ ورانہ میدان میں کامیابی ہے۔ مرکزی ذمہ داران اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور اپنی صلاحیتوں سے تنظیم کے کام کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے میں تقابلی طور پر، میرے مشاہدے کے مطابق، بہت آگے ہیں۔ برصغیر، عرب دنیا، ترکی اور یورپ میں اسلامی تحریکات کے ساتھ کام کرنے والی طلبہ تنظیموں کے لیے اسلامی چھاترو شبر کے کام میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ۱۵ سال تک عتاب کا شکار رہنے کے باوجود اس تنظیم کی جڑیں اکھڑنے کے بجائے مزید گہری ہوئی ہیں، اور بنگلہ دیشی طلبہ کو متاثر کرنے، اور اسلامی بنیادوں پر ان کی فکری و عملی تربیت کرنے میں یہ تنظیم سب سے نمایاں اور ممتاز ہے۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں اس تنظیم سے فارغ ہونے والے افراد، ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کررہے ہیں۔
اسی دن ظہرانے پر جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی مرکزی قیادت کے ساتھ جماعت کے مرکزی دفتر میں ملاقات طے تھی۔ ڈھاکہ کے پرانے علاقے میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے مرکزی دفتر کی عمارت جس گلی میں واقع ہے، اس کے سامنے سے گزرنے والی سڑک پر روزنامہ سنگرام کا دفتر ہے۔ عمارت پر سنگرام کا بورڈ لگا ہوا دیکھا تو سرزمین بنگال میں جماعت اسلامی کے ممتاز قائد خرم مرادؒ کی کتاب لمحات ذہن میں آئی۔ ڈھاکہ میں جماعت اسلامی کی دعوت کو مضبوط کرنے، اور سنگرام کے قیام و اشاعت میں ان کی کوششوں کی یادیں تازہ ہوگئیں۔ محترم خرم مرادؒ نے ڈھاکہ میں جس پودے کو خونِ جگر سے سینچا ہے، وہ اسلام دشمنوں کے شرپسند عزائم کے باوجود ایک تناور درخت کی صورت میں کھڑا لہلہا رہا ہے۔ اسلامی چھاترو شبر کے مرکزی دفتر کی طرح جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا مرکزی دفتر بھی گذشتہ ۱۵ سال سے مقفل تھا، اور حسینہ واجد کے آمرانہ دور میں گذشتہ ایک عشرے سے زائد عرصے کے دوران جماعت اسلامی بنگلہ دیش پر ناقابلِ بیان ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ لیکن جماعت اسلامی صبر و استقامت کا ایک پہاڑ ثابت ہوئی۔ اس تنظیم کے وابستگان نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کردی۔ عوامی لیگ کے سیاہ دورِ اقتدار کے خاتمے کے ساتھ ہی جماعت پر قدغنیں ختم ہوئیں اور اس نے بنگلہ دیش میں لاکھوں لوگوں کے اجتماعات منعقد کیے، اور بنگلہ دیش میں بھرپور واپسی کی۔
جماعت کی نشست میں امیر و قیم جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ جماعت کے دیگر مرکزی ذمہ داران کو سننے کا موقع ملا۔ امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر شفیق الرحمان نے شرکاء کے تعارف کے فوراََ بعد ہر خطے کے طلبہ قائدین سے وہاں کی اسلامی تحریکات کے بارے میں مختصر سوالات کرکے بنیادی واقفیت حاصل کی۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے بنگلہ دیش کی تازہ صورتِ حال کے بارے میں بیرونی مندوبین کو آگاہ کیا، اور ان کے سوالات کے جوابات دیئے۔
بنگلہ دیش کا حالیہ انقلاب نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ جنوبی ایشیا کے پورے خطے میں نئی امیدوں کا پیش خیمہ ثابت ہوسکتا ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش ملک کی تیسری بڑی سیاسی و دینی قوت ہے۔ ماضی میں جماعت اسلامی ملک کی دو دیگر بڑی سیاسی جماعتوں عوامی لیگ اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی)کے ساتھ حکومت سازی میں شامل رہی ہے۔ تاہم،عوامی لیگ نے بیرونی شہہ اور مدد سے حکومت پر قبضہ جمایا اور بنگلہ دیش میں حزبِ اختلاف کو دھونس اور دباؤ سے کچلنے کا جو ظالمانہ کھیل کھیلا، الحمدللہ وہ عمل گذشتہ سال کی طلبہ تحریک کے نتیجے میں کیفرِ کردار کو پہنچ چکا ہے۔ حسینہ واجد کا ملک چھوڑ کر بھاگ جانا، اور انڈیا میں پناہ لے کر چھپ جانا، عوامی حلقوں میں عوامی لیگ کے خلاف غصے کو مزید ہوا دینے کا سبب بن گیا ہے۔
ڈھاکہ یونی ورسٹی کے اطراف میں، تاریخی کرزن ہال کی دیواریں، ڈھاکہ ریس کورس گراؤنڈ، جو سرزمین بنگال میں تاریخ ساز لمحوں کا شاہد میدان ہے، اور ڈھاکہ کی مشہور شاہرائیں اس انقلاب کی گواہی پیش کررہی ہیں جس کے لیے طالب علموں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ظلم و زیادتی، رائے عامہ کی آواز کو دبانے، اور عوامی حقوق پر ڈاکا ڈالنے والی طاقتوں کے خلاف نعرے ہر دیوار پر نظر آرہے ہیں، اور ہر طرف اس عوامی انقلاب کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ڈھاکہ شہر میں یاد گاری مقامات اور دیواروں پر شیخ مجیب کے مجسمے اور تصاویر یا تو ہٹائی جاچکی ہیں، یا ہٹائے نہ جانے والے مجسموں اور تصاویر کی شکل کو بگاڑ دیا گیا ہے، حتیٰ کہ ائیر پورٹ سے باہر آنے والی ایک ذیلی سڑک، جوائیر پورٹ کو عام شاہراہ سے ملاتی ہے، بنگلہ دیش کی پاکستان سے الگ ہونے والے واقعات اور شخصیات کی تصاویر کی یادگار پر مبنی ہے۔ یہاں سے باہر آکر ہماری نظروں نے جو پہلا منظر دیکھا، وہ اس یادگاری دیوار پر شیخ مجیب کی تصویر کے سر والے حصے کو مٹانے کی صورت میں دیکھنے والوں کو عبرت کا درس دیتا ہے۔ گویا انقلاب کی گونج ہرطرف سنائی دیتی ہے۔
بلاشبہ اس انقلاب کے پیچھے حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف لوگوں میں موجود عدم اطمینان اور غم و غصہ تھا اور یہ کسی ایک خاص سیاسی تنظیم کی کوششوں کے نتیجے میں آنے والا انقلاب نہیں ہے، بلکہ اس انقلاب کے پیچھے بنگلہ دیشی طلبہ کا احتجاج اور ان کی حمایت و پشت پناہی کرنے والے عوام ہیں۔ عوام کی ہمدردیاں بلاشبہ سیاسی طور پر بی این پی اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں۔
جماعت ایک طویل عرصے تک عتاب کی شکار رہی ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی پہلی صف کی ساری قیادت شہید کردی گئی ہے، اور موجودہ قیادت کو جھوٹے مقدموں کے ذریعے آئے روز تنگ کیا جاتا تھا۔ اس انقلاب نے جماعت اسلامی کے لیے عوام کے ساتھ رابطے کا راستہ کھول دیا ہے، اور تنظیم کو ایک فطری ماحول میں پنپنے کا موقع فراہم کردیا ہے۔ عوامی لیگ کا سیاست کے منظرنامے سے باہر ہوجانے کے ساتھ ہی جماعت اسلامی ملک کی دوسری بڑی تنظیم کے طور پر سامنے آئی ہے۔
جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی مرکزی قیادت کے بقول حالات ابھی قومی انتخابات کے لیے سازگار نہیں ہیں، اور وہ عبوری حکومت کو مزید کچھ عرصہ تک حکومت میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ انتخابات کے لیے ماحول سازگار ہو۔ اسی طرح ایک دوسرا اہم مسئلہ بیرونی مداخلت ہے۔ بنگلہ دیش کی سیاست میں بیرونی طاقتوں کا اپنے مفادات کے لیے مداخلت کرنا سب کو دکھائی دے رہا ہے۔ نئے انقلاب کے بعد عوام اور عوام دوست سیاست پر یقین رکھنے والے لوگ اس بیرونی مداخلت سے بہت نالاں ہیں، اور وہ اس چیز کے مستقل حل کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ظاہر ہے جماعت اسلامی بنگلہ دیش اس سلسلے میں چھوٹی بڑی سبھی سیاسی تنظیموں میں ہراوّل دستے کا کام انجام دے رہی ہے۔ اسی لیے اندرونی اور بیرونی سطح، ہر دو محاذ پر جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو بڑے چیلنج درپیش ہیں۔
بنگلہ دیش میں کامیاب عوامی تحریک کے بعد ایک نئی سیاسی تنظیم کے وجود میں آنے کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ عوامی اور خاص حلقوں میں اس حوالے سے ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، اور شاید ملک میں عام انتخابات کا عمل شروع ہونے سے پہلے ایک نئی سیاسی تنظیم وجود میں آجائے۔ اس تنظیم کو قائم کرنے والے طلبہ تحریک کے قائدین ہی ہوسکتے ہیں۔ عوامی سطح پر اس خیال کو سراہا جارہا ہے اور دانش ور حلقے بھی اس خیال کی تائید کررہے ہیں۔ اگر یہ سیاسی تنظیم وجود میں آتی ہے، اور عام انتخابات میں کوئی قابلِ ذکر کامیابی حاصل کرتی ہے، تو یہ بنگلہ دیش میں جمہوری نظام کے عمل کو مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوسکتی ہے۔
اس دورے میں ایک اہم تجربہ پروفیسر غلام اعظمؒ کے مرقد کی زیارت تھی۔ پروفیسر غلام اعظمؒ بنگلہ دیش کی دینی و سیاسی تحریک کے قدآور لیڈر تھے۔ اپنے زمانۂ طالب علمی سے ہی بڑے سرگرم رہنے والے اعظم صاحب کی تربیت ایک دینی گھرانے میں ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ پہلے تبلیغی جماعت کے ساتھ شامل رہے، اور بعد میں جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے قائدین میں شمار ہوئے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو عوامی سطح پر متعارف کرانے میں ان کا کردار سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ ساری زندگی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے جدوجہد کرنے والے اس قائد کو حسینہ واجد نے انتہائی پیرانہ سالی میں قید و بند کی صعوبتوں سے گزارا، اور اس مردمجاہد نے بڑی استقامت کے ساتھ اس آزمائش کا مقابلہ کیا۔ ۳؍اکتوبر۲۰۱۴ء کو ۹۱سال کی عمر میں جیل میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔ ڈھاکہ کی بیت المکرم مسجد میں ان کے جنازے میں عوام کی ایک بڑی تعداد نے شمولیت کی۔ اپنے گھر کے نزدیک ایک چھوٹے سے قبرستان میں پروفیسر غلام اعظم آسودئہ خاک ہیں۔ مسجد سے متصل اس آبائی قبرستان میں ان کے مرقد کی زیارت نے اس پُرعزم قائد کے ساتھ وابستگی کے جذبے کو مزید گہرائی بخشی، اور دل میں بے اختیار ان کے لیے تشکر کے احساسات موجزن ہوگئے، اور آنکھیں نم ہوگئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس خاص بندے پر رحمتوں کی بارش کرے، جس نے عمر کے آخری لمحات میں بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور تاریخ میں ایک درخشندہ مثال بن کر اُبھرا۔
اس تحریر کا مقصد قارئین کو بھارت یا پاکستان کی طرف جھکاؤ رکھنے کی اپیل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ضمیر، انسانی ہمدردی، اور اخلاقی حِس کو مخاطب کرنا ہے۔
حقِ خودارادیت اقوام متحدہ کے چارٹر کا ایک بنیادی اصول ہے، جس کی توثیق انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں کی گئی اور متعدد بین الاقوامی تنازعات کے حل میں اسے کئی بار استعمال کیا گیا ہے۔
۱۴؍اگست ۱۹۴۱ء کے اٹلانٹک چارٹر میں، جو برطانوی وزیراعظم ونسٹن چرچل اور امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے جاری کیا، تمام افراد یا قوموں کا اپنی حکومت کے انتخاب کا حق تسلیم کیا گیا۔ انھوں نے مزید کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان قوموں کو خودمختار حقوق واپس دیے جائیں، جن سے زبردستی یہ حقوق چھین لیے گئے تھے۔
آخر کار، ۱۹۴۵ء میں اقوام متحدہ کے قیام نے خودارادیت کے اصول کو ایک نئی جہت دی اور اسے ان مقاصد میں شامل کیا گیا جنھیں اقوام متحدہ نے حاصل کرنے کا ہدف قرار دیا تھا، ساتھ ہی تمام اقوام کے مساوی حقوق کے ساتھ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل ۱.۲ میں مقاصد میں سے ایک درج ہے: ’’قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا، جو مساوی حقوق اور خودارادیت (Self-determination) کے اصول کے احترام پر مبنی ہو‘‘۔
۱۹۵۰ء اور ۱۹۶۰ء کے عشرے میں، خودارادیت کے حق کو تقریباً مکمل طور پر نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے عمل کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ قرارداد ۱۵۱۴ کا عنوان ہے: ’نوآبادیاتی ملکوں اور قوموں کو آزادی دینے کا اعلامیہ‘۔ اس میں اصول کا یہ بیان شامل ہے: ’’تمام قوموں کو خودارادیت (Self-determination)کا حق حاصل ہے؛ اس حق کے تحت وہ آزادانہ طور پر اپنا سیاسی درجہ طے کرتی ہیں اور اپنی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی ترقی کو آزادانہ طور پر آگے بڑھاتی ہیں‘‘۔
۱۹۷۰ء کی قرارداد ۲۶۲۵نے ایک دستاویز منظور کی جس کا عنوان تھا:’دوستانہ تعلقات اور ریاستوں کے درمیان تعاون سے متعلق بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا اعلامیہ‘۔ ایک حصہ، جس کا عنوان ہے:’قوموں کے مساوی حقوق اور خودارادیت کا اصول‘، اعلامیہ میں کہا گیا: ’’اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج قوموں کے مساوی حقوق اور خودارادیت (Self-determination) کے اصول کے تحت، تمام قوموں کو حق حاصل ہے کہ وہ بیرونی مداخلت کے بغیر آزادانہ طور پر اپنا سیاسی درجہ طے کریں اور اپنی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی ترقی کو آگے بڑھائیں، اور ہر ریاست کا فرض ہے کہ اس حق کا احترام کرے، جیسا کہ چارٹر کی دفعات میں مقرر کیا گیا ہے‘‘۔
’’۱.۱تمام قوموں کو خودارادیت کا حق حاصل ہے۔ اس حق کے تحت وہ آزادانہ طور پر اپنا سیاسی درجہ طے کرتی ہیں اور اپنی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی ترقی کو آزادانہ طور پر آگے بڑھاتی ہیں‘‘۔
یہ معاہدے ۱۹۷۶ء میں نافذ ہوئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردادوں کے برعکس، بین الاقوامی قانون کے تحت توثیق کرنے والی ریاستیں ان کی پابند ہیں، بشرطیکہ توثیق کے وقت کوئی تحفظات پیش نہ کیے گئے ہوں۔ بھارت نے ان دونوں معاہدوں کی توثیق ۱۰؍ اپریل ۱۹۷۹ء کو کی تھی۔
یہ خیال کہ جموں و کشمیر کی حیثیت کا تنازعہ صرف عوام کی مرضی کے مطابق طے ہو سکتا ہے، جو آزاد اور غیر جانب دار استصواب رائے کے جمہوری طریقۂ کار سے معلوم ہو، پاکستان اور بھارت دونوں نے قبول کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کسی اختلاف کے بغیر اس کی حمایت کی اور اسے امریکا، برطانیہ، فرانس اور دیگر جمہوری ریاستوں نے بھرپور انداز سے پیش کیا۔
اس قرارداد کے بعد، امریکا ’اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انڈیا اور پاکستان‘ (UNCIP) کے ایک اہم رکن کے طور پر اس موقف پر قائم رہا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بنیادی فارمولا کمیشن کی ۱۳؍ اگست ۱۹۴۸ء اور ۵ جنوری ۱۹۴۹ء کی قراردادوں میں شامل کیا گیا۔
امریکا اور برطانیہ نے روایتی طور پر استصواب رائے (Plebiscite)کے معاہدے کو مسئلہ حل کرنے کا واحد راستہ سمجھا ہے۔ انھوں نے سلامتی کونسل کی ان تمام قراردادوں کی سرپرستی کی، جن میں استصواب رائے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان کی وابستگی اس وقت ظاہر ہوئی جب امریکی صدر ہیری ٹرومین اور برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے ذاتی اپیل کی کہ غیر مسلح ہونے کے تنازعے کو استصواب رائے کے منتظم، ایک ممتاز امریکی جنگی ہیرو، ایڈمرل چیسٹر نمٹز کے ذریعے ثالثی کے لیے پیش کیا جائے۔ انڈیا نے اس اپیل کو مسترد کر دیا اور بعد میں کسی امریکی کے استصواب رائے کے منتظم کے طور پر کام کرنے پر اعتراض کیا۔ ایک اور امریکی سینیٹر فرینک گراہم نے اقوام متحدہ کے نمائندے کے طور پر برصغیر کا دورہ کیا تاکہ استصواب رائے سے قبل کشمیر کو غیر مسلح کرنے پر بات چیت کریں۔ انڈیا نے ان کی تجاویز کو بھی مسترد کر دیا۔ یہ معاملہ صرف اس وقت متنازعہ ہوا جب انڈیا کو احساس ہوا کہ وہ استصوابِ رائے کے نتیجے میں تائید حاصل نہیں کرسکتا۔
… ہمارے پاس موجود دستاویزات فریقین کے درمیان درج ذیل تین نکات پر اتفاق ظاہر کرتی ہیں:
۱- یہ سوال کہ ریاست جموں و کشمیر بھارت میں شامل ہوگی یا پاکستان میں، استصواب رائے کے ذریعے طے کیا جائے گا۔
۲- یہ استصواب رائے ایسے حالات میں کیا جانا چاہیے جو مکمل غیر جانبداری کو یقینی بنائیں۔
۳- لہٰذا، یہ استصواب رائے اقوام متحدہ کی سرپرستی میں منعقد کیا جائے گا۔
انڈیا اور پاکستان کی حکومتیں اس خواہش کا اعادہ کرتی ہیں کہ جموں و کشمیر ریاست کی آئندہ حیثیت عوام کی خواہشات کے مطابق طے کی جائے گی، اور اس مقصد کے لیے جنگ بندی معاہدے کی منظوری پر، دونوں حکومتیں کمیشن کے ساتھ مشاورت کرنے پر متفق ہیں تاکہ ایسے منصفانہ اور مساوی حالات کا تعین کیا جا سکے جن کے ذریعے آزادانہ اظہار رائے کو یقینی بنایا جا سکے۔
۵ جنوری ۱۹۴۹ء کی قرارداد میں یہ حکم دیا گیا کہ جموں و کشمیر ریاست میں تمام حکام استصواب رائے کے منتظم کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کشمیری عوام کی آزادانہ رائے شماری کے لیے بنیادی حالات کو یقینی بنایا جا سکے، جس میں اظہار رائے اور اجتماع کے بنیادی سیاسی حقوق کا تحفظ شامل ہے۔
چونکہ دونوں حکومتوں نے کمیشن کی تجاویز کو رسمی طور پر قبول کر لیا تھا، اور یہ ایک بین الاقوامی معاہدے کے طور پر اتنی ہی پابند تھیں جتنی کہ ایک معاہدہ۔ فوری طور پر جنگ بندی نافذ کی گئی۔ کمیشن نے انڈیا اور پاکستانی افواج کو ریاست سے اس طرح نکالنے کے لیے منصوبہ بندی پر بات چیت شروع کی کہ کسی بھی فریق کو نقصان نہ ہو اور استصواب رائے کی آزادی کو خطرہ نہ ہو۔ اس دوران امریکی ایڈمرل چیسٹر نمٹز کو استصواب رائے کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر نامزد کیا گیا۔
مہاتما گاندھی نے ۲۶؍اکتوبر ۱۹۴۷ء کو اپنی حکومت کی پوزیشن ان الفاظ میں بیان کی: ’’اگر کشمیری عوام پاکستان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت انھیں ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی۔ انھیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دینا چاہیے‘‘۔
بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ۲ جنوری ۱۹۵۲ء کو اعلان کیا:’’ہم نے یہ معاملہ اقوام متحدہ میں پیش کیا ہے اور قابلِ احترام وعدہ کیا ہے کہ ہم نے مسئلے کے حتمی حل کو کشمیری عوام کے فیصلے پر چھوڑ دیا ہے‘‘۔
جب ہم کشمیر سے افواج کی واپسی کی بات کر رہے ہیں، تو بھارت یہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے کیونکہ اس نے ان قراردادوں کے تحت اپنی افواج کشمیر سے واپس نہیں بلائیں۔ یہ ہراعتبار سے غلط بات ہے۔
پروفیسر جوزف کوربل، جو ’اقوامِ متحدہ کمیشن برائے بھارت و پاکستان‘ کے پہلے چیئرمین تھے، انھوں نے اس سوال کا جواب اپنے مضمون ’نہرو، اقوامِ متحدہ اور کشمیر‘ میں دیا ہے، جو ۴مارچ ۱۹۵۷ء کو دی نیو لیڈر میں شائع ہوا۔ جوزف کوربل لکھتے ہیں:
بھارتی مندوب کے مطابق: ’پاکستان نے اقوامِ متحدہ کمیشن کی قرارداد کے اس حصے پر عمل درآمد روک دیا جو استصوابِ رائے سے متعلق ہے، کیونکہ اس نے کشمیر سے اپنی افواج واپس بلانے کی تجویز پر عمل نہیں کیا‘۔ یہ سچ نہیں ہے۔ پاکستان سے اس وقت تک یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنی افواج کشمیر سےواپس بلائے جب تک بھارت کے ساتھ افواج کی بیک وقت واپسی کے لیے کوئی متفقہ منصوبہ نہ ہو۔
ان تمام عوامل کے مطابق کشمیریوں کا خودارادیت کے حق کا دعویٰ غیرمعمولی طور پر مضبوط ہے۔ اس علاقے کی خود حکمرانی کی ایک طویل تاریخ ہے، جو نوآبادیاتی دور سے پہلے کی ہے۔ کشمیر نے کامیابی سے اپنی آزادی دوبارہ حاصل کی، جب اسے تیسری صدی قبل مسیح میں سکندراعظم کے دور میں اور ۱۶ویں اور ۱۷ویں صدی کے مغل دور میں زیر کیا گیا۔ کشمیر کی حدود کئی صدیوں سے واضح طور پر متعین ہیں اور دنیا کے نقشوں پر بھی واضح طور پر دکھائی گئی ہیں۔ کشمیر کا رقبہ تقریباً ۸۶ہزار مربع میل پر محیط ہے، جو برطانیہ سے کچھ بڑا اور بیلجیم، لکسمبرگ اور نیدرلینڈ کے مجموعی رقبے سے تین گنا بڑا ہے۔
کشمیری عوام کشمیری زبان بولتے ہیں، جو ہندی یا اردو سے مختلف ہے۔ ان کی ثقافت بھی ہر لحاظ سے علاقے کی دیگر ثقافتوں سے منفرد ہے - لوک کہانیاں، لباس، روایات، کھانے پینے کی اشیاء، یہاں تک کہ روزمرہ کے استعمال کی اشیاء جیسے برتن، زیورات، خاص کشمیری انداز رکھتے ہیں۔ خاص طور پر کپڑے، کڑھائی اور قالین کشمیری ڈیزائن کے لیے مشہور ہیں۔
۱- یہ ایک ایسے علاقے میں موجود ہے جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے تحت ایک متنازعہ علاقہ تسلیم کیا گیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اقوام متحدہ کی نگرانی میں کیے گئے بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق، اس علاقے کی حیثیت عوام کے آزادانہ ووٹ کے ذریعے اقوام متحدہ کی نگرانی میں طے کی جانی ہے۔
۲- یہ ایک ایسی حکومت کی جانب سے جبر کی نمائندگی کرتا ہے جو علیحدگی پسند یا علیحدگی کی تحریک کے خلاف نہیں بلکہ غیر ملکی قبضے کے خلاف بغاوت کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ قبضہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کے تحت ختم ہونے کی توقع تھی۔ کشمیریوں کو ’علیحدگی پسند‘ کہنا درست نہیں کیونکہ وہ کسی ایسے ملک سے الگ نہیں ہو رہے کہ جس کے ساتھ وہ کبھی شامل ہی نہیں ہوئے۔
۳- اقوام متحدہ نے اس معاملے کو نظرانداز کیا ہے۔ اس بے پروائی نے انڈیا کو مکمل استثنیٰ کا احساس دیا ہے۔ اس سے یہ تاثر بھی پیدا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ انسانی حقوق اور جمہوریت کے اصولوں کے اطلاق میں متعصبانہ رویہ رکھتی ہے۔
۴- یہ اقوام متحدہ کے غیر فعال ہونے کا ایک افسوس ناک کیس ہے، جو ایک ایسی صورت حال کو حل کرنے سے قاصر ہے، جس پر اس نے متعدد قراردادیں منظور کیں اور اپنی موجودگی قائم کی۔ انڈیا اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کا گروپ (UNMOGIP) اقوام متحدہ کے سب سے پرانے امن مشنوں میں سے ایک ہے۔ یہ فورس کشمیر میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کی نگرانی کے لیے تعینات ہے۔
۵- کشمیر واحد بین الاقوامی تنازع ہے جس کا حل خود فریقین – انڈیا اور پاکستان – نے تجویز کیا۔ یہ حل کہ کشمیری عوام خود فیصلہ کریں، انڈیا کی طرف سے تجویز کیا گیا، پاکستان نے اس کی حمایت کی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسے قبول کیا۔
۶- کشمیر دنیا کا واحد خطہ ہے جو تین ایٹمی ممالک – انڈیا، پاکستان اور چین – کی سرحدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر (UNHCHR) نے ۱۴ جون ۲۰۱۸ء اور ۸جولائی ۲۰۱۹ء کو ’کشمیر میں انسانی حقوق کی صورت حال‘ پر رپورٹس جاری کیں۔ ان رپورٹس میں انڈین قابض افواج کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں کیے جانے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تفصیلی دستاویزات شامل ہیں۔ یہ ایک اہم قدم تھا جس سے کشمیری عوام پر انڈین فوج کے مظالم بین الاقوامی سطح پر سامنے آئے۔
رپورٹ میں انڈین حکومت کی جانب سے کشمیری عوام کے خلاف جمہوری آزادیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے واقعات درج ہیں۔ اس میں متعدد ایسے مواقع کی تفصیلات دی گئی ہیں جہاں سخت قوانین کے استعمال نے انڈین فوج کو مکمل استثنیٰ فراہم کیا۔ رپورٹ نے اس بات پر زور دیا کہ ’’انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے استثنیٰ اور انصاف تک رسائی کا فقدان جموں و کشمیر میں کلیدی چیلنجز ہیں‘‘۔ مزید یہ کہ ’’کشمیر میں جبری گمشدگیوں کے لیے استثنیٰ برقرار ہے کیونکہ شکایات کی تحقیقات یا وادیٔ کشمیر اور جموں کے علاقوں میں مبینہ اجتماعی قبروں کے مقامات کی قابل اعتماد تفتیش کی طرف بہت کم پیش رفت ہوئی ہے۔
انڈیا اپنے آپ کو عالمی برادری میں بڑا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ایک ملک متنازعہ سرحدوں کے ساتھ اپنی ساکھ اور اثر و رسوخ برقرار نہیں رکھ سکتا۔درحقیقت، کچھ باشعور مبصرین پہلے ہی بھارتی متوسط طبقے میں بڑھتی ہوئی اس آگاہی کو محسوس کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا مستقل طور پر پایا جانا انڈیا کو کمزور کرتا ہے۔ اسی طرح خود انڈیا میں ہمیشہ ایسے معقول عناصر موجود رہے ہیں، جنھوں نے کشمیر پر انڈیا کے جارحانہ رویے کے اخلاقی اور عملی پہلو پر سوال اٹھائے ہیں۔ تاہم، انھیں باہر سے بہت کم حمایت ملی ہے، جس کی وجہ سے وہ دبے رہے ہیں۔
انڈیا کی پالیسیوں کی ظاہری ناکامی، کشمیر میں قائم کی گئی شکست خوردہ حکومت اور وہاں ہونے والے نقصانات، جنھیں کشمیری عوام کو دبانے کے لیے زبردست قوت کے استعمال کے باوجود برداشت کرنا پڑا۔ – یہ سب چیزیں انڈیا میں، یہاں تک کہ اس کی فوج میں، مزید لوگوں کو یہ باور کرا رہی ہیں کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن یہ تعمیری رجحان اس وقت ختم ہو جائے گا اگر دنیا کی طاقتیں بھارت کی ہٹ دھرمی کو برداشت کرتی نظر آئیں اور خود انڈیا میں صحت مند رائے عامہ کو نظرانداز کریں۔
اس کے ساتھ ہی، آل پارٹیز حریت کانفرنس (APHC) نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ انڈیا، پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان تین طرفہ مذاکرات ہی مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا واحد راستہ ہیں۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی قیادت اس حقیقت کو تسلیم کرے گی کہ جموں و کشمیر کے عوام کی مکمل اور فعال شرکت کے بغیر کشمیر تنازع کا کوئی حل ممکن نہیں۔
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر ۱۲۲ واضح کرتی ہے کہ ’’آل جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کی جنرل کونسل کی سفارش پر ایک آئینی اسمبلی کا انعقاد اور اس اسمبلی کے ذریعے ریاست کی مستقبل کی شکل اور الحاق کے بارے میں کیے گئے یا کیے جانے والے کسی بھی اقدام کو اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق ریاست کا فیصلہ نہیں سمجھا جائے گا‘‘۔
تازہ ترین شکار خرم پرویز ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر معروف انسانی حقوق کے کارکن ہیں اور یو اے پی اے کے تحت گرفتار کیے گئے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے محافظین کے لیے خصوصی نمائندہ مس ماری لاولر نے ۲۳ نومبر ۲۰۲۱ء کو کہا: ’’وہ (خرم پرویز) دہشت گرد نہیں، بلکہ انسانی حقوق کے محافظ ہیں‘‘۔اسی قانون کے تحت دیگر متاثرین میں محمد یاسین ملک (چیئرمین، جے کے ایل ایف)، شبیر احمد شاہ (۳۵ سال سے زائد قید میں رہے)، مسرت عالم، آسیہ اندرابی، مسز صوفی فہمیدہ، اور مسز ناہید نسرین شامل ہیں۔
اقوام متحدہ کی قراردادیں کبھی غیر مؤثر نہیں ہو سکتیں یا تبدیل شدہ حالات کے سبب ختم نہیں ہو سکتیں۔ وقت کا گزرنا کشمیری عوام کے حقِ خود ارادیت جیسے ناقابل تنسیخ اصول کو ختم نہیں کرسکتا۔ اگر وقت گزرنے سے عالمی معاہدے ختم ہو جائیں، تو اقوام متحدہ کے چارٹر کو بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہیے، جیسا کہ کشمیر پر قراردادوں کے ساتھ ہوا۔
۱۹۹۵ءمیں بین الاقوامی کمیشن برائے انصاف نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام کے حقِ خود ارادیت کو کبھی ختم نہیں کیا گیا اور انڈیا اور پاکستان کو تجویز دی کہ وہ ایک ایسا حل تلاش کریں جس کی ریاست کے عوام ریفرنڈم میں منظوری دیں۔
کشمیری عوام ،اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل مسٹر انتونیو گوتریس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل ۹۱ کے تحت کشمیر کی صورتِ حال میں مداخلت کریں۔ کیونکہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں منظم، جانتے بوجھتے اور انڈین حکومت کی سرپرستی میں کی جارہی ہیں۔ انڈیا نے کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کو قانونی حیثیت دی ہوئی ہے، اور اپنی قابض افواج کو گولی مارنے اور کشمیری عوام پر ظلم کرنے کا مکمل اختیار دے رکھا ہے۔
۱- شہری آبادی کے خلاف تمام فوجی اور نیم فوجی کارروائیوں کا فوری خاتمہ۔
۲- شہروں اور دیہاتوں سے فوج کی واپسی۔
۳- بنکرز، واچ ٹاورز اور رکاوٹوں کا خاتمہ۔
۴- سیاسی قیدیوں کی رہائی۔
۵- آبادیاتی تبدیلی کے لیے بنائے گئے ڈومیسائل قانون کو منسوخ کرنا۔
۶- جابرانہ قوانین کو ختم کرنا۔
۷- پُرامن اجتماع، مظاہروں اور تنظیم سازی کے حقوق بحال کرنا۔
۸- حریت قیادت کو بیرون ملک سفر کی اجازت دینا۔
۹-کشمیری قیادت کو جموں و کشمیر کے دورے کے لیے ویزا دینا تاکہ امن عمل شروع کیا جاسکے۔
انڈیا کی بڑھتی ہوئی ضد اور بین الاقوامی وعدوں کو نظر انداز کرنے کے پیش نظر، حکومت پاکستان کو کشمیر کے معاملے کی وکالت کے لیے اپنی پالیسی کو اَزسرنو مؤثر بنانا ہوگا۔ اگر پاکستان اس معاملے پر کسی مضبوط اور مؤثر حکمت عملی کے بغیر سست روی کا مظاہرہ کرے گا تو اس کے نتیجے میں انڈیا صورتِ حال کا فائدہ اٹھاتا رہے گا۔
پاکستان کی موجودہ داخلی سیاست اہلِ کشمیر کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ وہ اپنی کامیابی صرف ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو ایسا ماحول بنانا چاہیے جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادت کشمیر کے مسئلے پر مکمل اتفاق رائے کے ساتھ نظر آئے۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کمزوری انڈیا کے شدت پسند قوم پرست میڈیا کے ہاتھ میں کھیلنے کے مترادف ہوگی۔
یہ انتہائی ضروری ہے کہ حکومت پاکستان بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے مسئلے پر کانفرنسز اور سیمینار منعقد کرے تاکہ اس مسئلے پر تفصیل سے بحث ہو اور ایک ایسی حکمت عملی تیار کی جا سکے جو تین فریقین: بھارت، پاکستان، اور آل پارٹیز حریت کانفرنس (APHC) کے درمیان فعال اور مؤثر مذاکرات کی راہ ہموار کرے۔ اس سے کم کسی بھی کوشش سے مسئلہ کشمیر کے حل میں ناکامی ہوگی، جو خطے کو ایٹمی جنگ کی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ عالمی برادری کو اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ اس دیرینہ مسئلے کو حل کیے بغیر اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی جانب سے ۱۴ جون ۲۰۱۸ء اور ۸جولائی ۲۰۱۹ء کو جاری کی گئی رپورٹس، جن میں ’کشمیر کی صورتِ حال‘ پر روشنی ڈالی گئی ہے، کو مدنظر رکھتے ہوئے، حکومت پاکستان کو انسانی حقوق کونسل کے او آئی سی ارکان پر زور دینا چاہیے کہ وہ ان رپورٹس کی حمایت کریں اور آئندہ جنیوا میں جون-جولائی ۲۰۲۵ء اور ستمبر-اکتوبر ۲۰۲۵ء کے دوران ہونے والے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن کے قیام کے لیے مشترکہ او آئی سی قرارداد پیش کریں۔
ڈاکٹر گریگوری اسٹینٹن، چیئرمین ’جینوسائیڈ واچ‘، کی ۱۲ جنوری ۲۰۲۲ء کو امریکی کانگریس میں دی گئی گواہی اور ۱۹جنوری ۲۰۲۲ء کو کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو میں دیے گئے بیان کو بڑے پیمانے پر پھیلایا جائے۔ انھوں نے کہا تھا کہ ’’بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی تیاری ہو رہی ہے، جو کشمیر اور آسام سے شروع ہو رہی ہے‘‘۔
حکومت پاکستان کو ’اسلامی تعاون تنظیم‘ (OIC) کو قائل کرنا چاہیے کہ وہ کشمیری تارکینِ وطن کے لیے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، جیسے طلبہ، اسکالرز، کارکنان، صحافی اور کاروباری افراد۔ او آئی سی کے رکن ممالک ان ہنر مند اور پیشہ ور کشمیریوں کے لیے ویزا، ملازمتوں، اور نقل مکانی کی سہولت کو ادارہ جاتی انداز میں یقینی بنائیں، جن کے لیے مودی کے انڈیا میں رہنا ناقابلِ برداشت ہو گیا ہے۔
او آئی سی کو انڈیا مقبوضہ کشمیر کے مستحق طلبہ کے لیے اپنے تمام رکن ممالک میں اسکالرشپ پروگرام شروع کرنا چاہیے۔
آخر میں، یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ کئی اہم دارالحکومتوں میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ’جنرل پرویز مشرف فارمولا‘ پر عمل کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ لیکن ایک نکتے کے علاوہ، یعنی فوجوں کی واپسی (کشمیر کو غیر فوجی بنانا تاکہ تنازعے کا حل نکل سکے)، دیگر تمام نکات یا تو سراسر جھوٹ ہیں یا انڈین موقف کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہیں۔ حکومت پاکستان کو بخوبی علم ہونا چاہیے کہ ’مشرف فارمولا‘ ایک مکمل فریب (absolute fallacy) ہے۔
یہ اُمید کی جاتی ہے کہ اقوام متحدہ اور او آئی سی کے رکن ممالک مسئلہ کشمیر کا واحد حل – حقِ خودارادیت کا وہ اَدھورا وعدہ، جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مسلسل قراردادوں نے دی ہے – کے حل کی طرف توجہ دیں گے۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی قوانین کے مطابق ہر ۳۰ سال بعد امریکی خفیہ (کلاسیفائیڈ) دستاویزات، عوام کے لیے کھول (یعنی ڈی کلاسیفائی) دی جاتی ہیں۔ ان میں مختلف امریکی سفارت کاروں کے خفیہ مراسلے، ٹیلی گرامز وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان دستاویزات کی جانچ پڑتال کرنے سے بہت سے انکشافات سامنے آتے ہیں۔ایسے ہی انکشافات کشمیر تنازع کے حوالے سے امریکی ڈی کلاسیفائی ڈاکومنٹس سے سامنے آئے ہیں۔
ان کے مطابق تقسیم کے بعد پہلے ڈیڑھ سال تک امریکا، کشمیر میں استصواب رائے کرانے کے حق میں تھا، تب بھارت میں موجود امریکی سفیر بھی واشنگٹن یہی رپورٹیں بھیجتے تھے کہ پاکستان کا کشمیری عوام سے رائے لینے کا مطالبہ جائز اور منصفانہ ہے، تاہم بتدریج اپنی مصلحتوں کی بنا پر امریکا اس سے پیچھے ہٹتا گیا۔ امریکیوں نے تب بھارت کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دی اور اقوام متحدہ کی قرارداد کو پس پشت ڈال دیا۔
۱۹۵۶ء میں انڈیا میں امریکی سفیر نے اسٹیٹ آفس کو خط لکھا کہ بھارت کسی بھی صورت میں استصواب رائے نہیں کرائے گا اور جنگ کے بغیر اس سے یہ بات نہیں منوائی جاسکتی۔
یہ رپورٹ ممتاز کشمیری اخبار کشمیر ٹائمز نے چند دن قبل شائع کی ہے۔ اس میں ’کشمیر، لا اینڈ جسٹس پراجیکٹ‘ کی جانب سے امریکی اسٹیٹ آفس (وزارت خارجہ) کے ڈی کلاسیفائی ڈاکومنٹس کےمطالعے کے بعد اخذ کردہ نتائج کا حوالہ دیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق ابتدا میں امریکا نے کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کی حمایت کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکا انسانی حقوق اور نوآبادیاتی نظام کے خاتمے پر زور دیا کرتا تھا۔ تاہم، جیسے جیسے سرد جنگ کا آغاز ہوا، ایشیا میں اس کے اسٹرے ٹیجک مفادات امریکی خارجہ پالیسی پر غالب آنے لگے، جس کے نتیجے میں کشمیر کے معاملے پر اس کے موقف میں نمایاں تبدیلی آئی۔
۱۹۴۸ء میں امریکا نے کشمیر میں رائے شماری کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور چارلس ڈبلیو لیوس کی جانب سے کی گئی بات چیت میں پاکستان کی غیر جانب دار انتظامیہ اور بعد میں رائے شماری کی تجویز کو ’منصفانہ اور جائز‘ قرار دیا گیا۔
امریکا نے بھارت کو آزاد جموں و کشمیر کا تصور پیش بھی کیا اور یہ تجویز سامنے آئی کہ استصواب رائے دو مرحلوں میں ہو۔ کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ کیا وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، الگ ملک بناکر؟ اگر جواب نفی میں ہو تو پھر بھارت یا پاکستان میں شمولیت کے ممکنہ سوال پر استصواب رائے ہو۔ امریکی سفارت کاروں نے اس تجویز پر سینئر بھارتی افسران سے تبادلۂ خیال بھی کیا۔
۱۹۵۰ء کے عشرے کے اوائل تک امریکی نقطۂ نظر میں واضح تبدیلی آچکی تھی۔ امریکی سفارت کاروں اور بھارتی حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رائے شماری کی حمایت سے بتدریج دوری اختیار کی گئی۔ ۱۹۵۱ء میں بھارت میں امریکی سفیر لوئے ہینڈرسن کی خط کتابت میں بھارت کی رائے شماری کرانے میں ہچکچاہٹ پر امریکی مایوسی کا اظہار کیا گیا، لیکن ساتھ ہی بھارتی اعتراضات کے حوالے سے زیادہ مفاہمتی رویہ بھی اپنایا گیا۔
۱۹۵۰ء میں امریکی وزیرخارجہ کو ایک یادداشت میں واضح طور پر کہا گیا کہ اگر کشمیر الگ ملک ہوا تو اس پر کمیونسٹوں کا قبضہ ہو جائے گا، یوں امریکا، کشمیر کی آزادی کا مخالف ہوگیا۔
۱۹۵۰ء کے عشرے میں امریکا نے کشمیر کے معاملے پر محتاط موقف اختیار کیا۔ بھارتی اور پاکستانی ریاستوں کے درمیان توازن برقرار رکھا۔ اندرونی یادداشتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے بارے میں مایوسی کا احساس موجود تھا، اور امریکی سفارت کار اکثر کسی معاہدے کی عملیت کے بارے میں شک کا اظہار کرتے تھے۔
۱۹۵۰ء کے عشرے کے وسط تک امریکا نے کشمیر میں فعال طور پر حل تلاش کرنے سے دستبرداری اختیار کرنا شروع کی، جیسا کہ ۱۹۵۶ء کے ایک ٹیلیگرام میں کہا گیا کہ ’’جنگ کے بغیر کوئی دباؤ بھارتی حکومت کو وادیٔ کشمیر چھوڑنے پر مجبور نہیں کرےگا‘‘۔ دراصل یہ جوں کی توں صورتِ حال قبول کرنے کی علامت تھی۔
۱۹۵۷ء میں ان دستاویزات کا اختتام ہوتا ہے۔ سرد جنگ یعنی کولڈ وار نے نہ صرف امریکی خارجہ پالیسیوں کو تشکیل دیا بلکہ کشمیر جیسے غیر حل شدہ تنازعات کو بھی چھوڑا۔ آخر کار امریکی اسٹرے ٹیجک مفادات غالب آئے اور حقِ خودارادیت و بین الاقوامی اصول پیچھے رہ گئے۔
ہمارے ہاں اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب بھارت نے خود اقوام متحدہ جا کر استصواب رائے کا وعدہ کیا تھا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جاتا؟ پنڈت نہرو کے خطوط اور دیگر دستاویزات سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت دانستہ طور پر اقوام متحدہ گیا تھا۔
جب بھارت نے اقوامِ متحدہ سے جنگ بندی کی درخواست کی، تو یہ خدشہ تھا کہ اگر بھارت ایسا نہ کرتا تو پاکستان خود اقوامِ متحدہ سے رجوع کرسکتا تھا یا اقوامِ متحدہ قرارداد منظور کرسکتی تھی جو عمل درآمد کے طریقۂ کار کا تقاضا کرتی۔
کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے اقوامِ متحدہ کے چارٹر کے باب ششم کے تحت درخواست دی، جو پُرامن حل پر زور دیتا ہے اور عمل درآمد کے لیے لازمی طریقۂ کار فراہم نہیں کرتا۔ چونکہ پاکستان نے رائے شماری پر اتفاق کیا تھا، اس لیے اقوامِ متحدہ نے عمل درآمد کا کوئی مخصوص طریقۂ کار وضع نہیں کیا۔
اس حوالے سے قانون کے استاد پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق خان کا کہنا ہے: یہ انڈین پروپیگنڈا ہے کہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قرارداد کم اہم ہے اور کشمیر کے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادیں اقوام متحدہ کے منشور کے بابِ ششم کے تحت تھیں اور اس وجہ سے کم اہمیت کی حامل تھیں، یا اس وجہ سے کم وزن ہیں کہ سلامتی کونسل نے تنفیذ کا کوئی نظام وضع نہیں کیا۔ بھارتی پروپیگنڈا کے زیر اثر لوگوں کا یہ دعویٰ بین الاقوامی قانون اور تعلقات، دونوں کے لحاظ سے غلط ہے۔
اس لیے بابِ ششم کی قراردادیں ہوں یا بابِ ہفتم کی، دونوں کا وزن یکساں ہے۔ ان میں فرق کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ مزید یہ کہ جب انڈیا نے یہ قراردادیں نہ صرف اقوامِ متحدہ میں تسلیم کیں، بلکہ باقاعدہ ان پر عمل کا اعلان کیا اور پھر اپنے آئین میں بھی دفعہ ۳۷۰ ڈال کر اسے آئینی حیثیت بھی دے دی، تو پھر یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ کیا یہ قراردادیں اس پر لازم تھیں یا نہیں؟ ان کاموں کے بعد وہ اس پر لازم ہوگئیں۔اس لیے کشمیر پر اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کو کمزور قرار دینا درست نہیں ہے۔ بین الاقوامی قانون میں انھی قراردادوں پر تو پاکستان کا، بلکہ کشمیر کا، پورا مقدمہ قائم ہے۔
جب مہاراجا ہری سنگھ نے جموں و کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی مبینہ درخواست کی، تو بھارت کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ۲۷؍ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو اس الحاق کو قبول کرتے ہوئے مہاراجا کو ایک خط لکھا: ’’یہ میری حکومت کی خواہش ہے کہ جیسے ہی جموں و کشمیر میں قانون اور نظم بحال ہو جائے اور اس کی سرزمین کو حملہ آوروں سے پاک کردیا جائے، ریاست کے الحاق کا سوال عوام کی رائے سے طے کیا جائے‘‘۔ یہ اقوامِ متحدہ کی قراردادوں سے بہت پہلے کی بات ہے۔ لہٰذا اقوامِ متحدہ نے کسی عمل درآمد کے طریق کار کو وضع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔
اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ نہرو صرف وقت گزارنے کی کوشش کررہے تھے۔ ان کا رائے شماری کرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انھیں صرف کشمیر کی وادی اور جموں چاہیے تھا، انھیں باغ، پلندری، میرپور، مظفرآباد وغیرہ کی کوئی خواہش نہیں تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شیخ عبداللہ کا ان علاقوں میں کوئی اثرورسوخ نہیں ہے اور ان علاقوں پر قبضہ کرنا ہمیشہ کی سردردی مول لینے کے مترادف ہوگا۔
اس طرح پاکستان کو اس بات کا موردِ الزام ٹھیراتے ہیں کہ اس نے رائے شماری نہیں کروائی۔ یہ انکشافات بتاتے ہیں کہ ان کے یہ دعوے قطعی طور پر غلط ہیں۔ امریکی خفیہ دستاویزات صاف بتا رہی ہیں کہ امریکی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر ایک آزاد ملک کے طور پر وجود میں آئے۔
کشمیری قوم پرستوں کی بیان کی گئی کہانیوں کے برعکس یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر قبائلیوں اور بعد میں پاکستانی فوج نے مداخلت نہ کی ہوتی تو مہاراجا کے وزیراعظم مہر چند مہاجن اور ان کے نائب رام لال بٹرا میرپور، پونچھ اور مظفرآباد میں مسلمانوں کا قتلِ عام کرنے کے لیے تیار تھے، تاکہ جموں کی طرح مسلمانوں کو ان علاقوں سے نکال کر پاکستان دھکیل دیا جائے۔
یہ حقیقت ہے کہ مہاجن کے منصوبے کی وجہ سے جموں کی مسلم اکثریتی آبادی جو ۷۰ فی صد کے قریب تھی، قتل عام کے بعد آدھی رہ گئی۔ یہی سب کچھ مہاجن مظفرآباد، باغ، راولا کوٹ وغیرہ میں کرنا چاہتا تھا، مگر قبائلی دستوں اور پھر پاکستانی فوج کی مداخلت کی وجہ سے آزاد کشمیر کے ان علاقوں کے مسلمانوں کی جانیں بچ گئیں۔ اس نکتے کا ادراک بیش تر کشمیری قوم پرست نہیں کرتے۔
ان حقائق کو پیش کرتے ہوئے معروف کشمیری دانش ور اور صحافی جناب افتخار گیلانی کی مشاورت اور رہنمائی بہت کام آئی۔ انھوں نے کشمیر ٹائمز کی خصوصی رپورٹ کی طرف رہنمائی کی، نہرو کے خط کی تفصیل فراہم کی اور بعض دیگر حقائق بھی آشکار کیے۔
قطر کے دارالحکومت دوحہ کے نواح میں واقع کئی منزلہ عمارت تناؤ اور بے یقینی کا مرکز بن چکی تھی۔ یہ چار دن کے تھکا دینے والے مذاکرات تھے، جہاں وقت کی قید ختم ہو چکی تھی۔رات اور دن کا کوئی فرق باقی نہیں رہا تھا۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبدالرحمان الثانی، مصر کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ عباس کمال، اور امریکی ایلچی بریٹ مکگرک کی موجودگی اور ساتھ ہی نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندے، سٹیو ویٹکوف نقشوں کے پلندے میں اُلجھے ہوئے تھے۔ ہر چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ دوسری منزل پر اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا، داخلی ایجنسی کے افسر رونین بار، اور فوج کے نمائندے نزتان الون تل ابیب سے مسلسل رابطے میں تھے۔
لیکن کہانی کی اصل گتھی تیسری منزل پر تھی، جہاں حماس کے سیاسی بیورو کے نائب سربراہ خلیل الحیہ اپنے وفد کے ساتھ موجود تھے۔ ان کواختیار تھا کہ —امریکی صدر بائیڈن نے گذشتہ سال مئی میں جس سیز فائر پلان کی بنیاد رکھی تھی، اور جس پر بعد میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مُہرثبت کی تھی، اس پر رضامندی ظاہر کریں لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بار بار پوزیشن بدلنے کے سبب بات منزل پہ نہ پہنچتی۔
مذاکرات کی بھٹی میں ہر لمحہ تپش بڑھ رہی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر سفارت کار ایک تجویز تیار کرتے، پھر امریکی وفد اسے پہلی منزل پر اسرائیلی وفد کے سامنے پیش کرتا۔ ادھر قطر اور مصر کے نمائندے اس تجویز کو لے کر حماس کے پاس پہنچتے، جہاں تیسری منزل کی فضا بظاہر پُرسکون تھی۔ اسرائیلی وفد تل ابیب سے مشورے لیتے ہوئے قدم قدم پر نئی شرائط سامنے رکھ رہا تھا، جس سے مذاکرات کا سلسلہ بار بار رُک جاتا۔
مذاکرات میں شریک ایک اہلکار نے راقم کو بتایا کہ ہر قدم پر ایسا محسوس ہوتا جیسے کامیابی کی منزل قریب ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جب امریکی وفد اسرائیلی نمائندوں سے مل کر واپس گراونڈ فلور پر وارد ہوتا تھا توان کے تناؤ بھرے چہرے بتاتے تھے کہ وہ کوئی نئی پیچیدگی لے کر ہی آئے ہیں۔ اس طرح ان چار دنوں میں مذاکرات کاروں نے سینکڑوں بار سیڑھیاں چڑھی اور اُتریں۔ ایک لمحے کو لگتا کہ معاہدہ طے ہونے کو ہے، اور پھر ایسا محسوس ہوتا کہ کچھ نہیں ہورہا۔ منگل اور بدھ کی راتیں طویل اور بے چین تھیں۔ انگریزی کی ڈکشنریوں کے صفحات اُلٹے جا رہے تھے، ہر لفظ کی باریکی پر بحث ہو رہی تھی، لیکن سب بے سود۔
ویٹکوف براہ راست صدر ٹرمپ سے جنھوں نے ابھی عہدہ سنبھالا نہیں تھا، مسلسل رابطے میں تھے۔ ابھی مذاکرات کے دور جاری تھے کہ خبر آئی کہ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر معاہدے کا اعلان کر دیاہے۔ پوری دنیا کے میڈیا میں سمجھوتہ کی خبریں نشر ہونا شروع ہوگئیں۔ مذاکرات کاروں کے مطابق تب تک وہ پیش رفت سے دور تھے۔ مگر ٹرمپ کے اس اعلان نے اسرائیلی وفد کو پیغام بھیجا کہ اب مزید معاملات لٹکانے سےکام نہیں چلے گا۔ اس چیز نے اسرائیلی وفد پر دباؤ ڈالنے کا کام کیا۔ امریکی وفد نے اسرائیلی نمائندوں سے کہا کہ اب سمجھوتے کو آخری شکل دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔
اعصاب شکن مذاکرات ۹۶ گھنٹوں سے مسلسل جاری تھے۔ بالآخر اسرائیلی وفد کو تل ابیب سے اشارہ مل گیا اور دو گھنٹے بعد قطری وزیر اعظم نے دوحہ میں پریس کانفرنس میں سیز فائر معاہدے کے مندرجات کا اعلان کردیا۔ اس کے چند لمحوں کے بعد واشنگٹن میں بائیڈن نے بھی اس کا اعلان کیا، مگر ابھی اس معاہدہ کو اسرائیلی کابینہ کی منظوری نہیں ملی تھی۔ جس کا اجلاس اب اگلے دن یعنی جمعرات کو طے تھا اور نیتن یاہو ایک بار پھر پلٹا کھانے کےلیے پر تول رہے تھے۔ امریکی نمائندے کی سرزنش کے بعد، یعنی معاہدہ کے اعلان کے ۲۴گھنٹے کے بعد اسرائیلی وفد اور حماس کے نمائندوں نے اس پر دستخط کرکے سیزفائر ڈیل کو حتمی اور قانونی شکل دے دی۔
ٹرمپ کے نمائندے نے اس سے قبل سنیچر کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو تل ابیب میں واضح اور سخت پیغام پہنچایا تھا۔ سنیچر یا سبت کے دن اسرائیلی وزیر اعظم کسی مہمان سے ملنے سے گریز کرتے ہیں۔ مگر ویٹکوف نے ان سے مل کر ٹرمپ کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ اگر وہ سیزفائر کےمذاکرات میں تاخیر کرنے کی کوشش کرتےہیں، تو ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور اگلے چار سال وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ ہی سے ڈیل کرنا ہے۔ یاد دلایا گیا کہ اسرائیلی کی سیکیورٹی کی صورت حال مضبوط ہے۔ ایران کا مزاحمتی اتحاد دم توڑ چکا ہے۔ شام اور لبنان کی طرف سے کسی مداخلت کا خطرہ نہیں ہے۔ لہٰذا سیز فائر میں دیر نہیں کی جاسکتی۔
اس دباؤ نے مذاکرات میں نئی رفتار پیدا کی۔ تاہم، ایک اور رکاوٹ اس وقت سامنے آئی، جب حماس نے یہ کہہ کر یرغمالیوں کی فہرست مکمل طور پر فراہم کرنے سے معذوری ظاہر کردی کہ اسرائیل کی مسلسل بمباری کی وجہ سے وہ گراؤنڈ پر اپنے عسکریوں سے رابطہ کرنے میں دشواری محسوس کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو خدشہ تھا کہ یرغمالیوں کی شناخت ظاہر کرنے سے اسرائیل ان کو سیز فائر سے قبل بازیاب کرنے کا آپریشن کرسکتا ہے یا پھر قتل۔ اسرائیلی فوج کو اپنے شہریوں کو قتل کرنے کا حق حاصل ہے۔ حماس کی طرف سے ایک ہفتہ کی مہلت کو اسرائیل نے مسترد کردیا۔ اس موقعے پر امریکی ثالث نے مصر و قطر کو پیغام دیا کہ حماس کو فہرست دینے پر آمادہ کریں۔
اسرائیل-حماس جنگ بندی معاہدہ کی تفصیلات
یہ معاہدہ یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی، جنگ بندی، اور انسانی امداد کی فراہمی جیسے نکات پر مشتمل ہے۔ تمام اختلافات کے باوجود، دوحہ میں اس رات جو طے پایا، وہ نہ صرف سفارت کاری کی ایک کامیاب کہانی تھی بلکہ خطے میں امن کی ایک نئی امید بھی اور اسرائیل کے غرور کے بت کو پاش پاش کرنے کی ابتدا بھی تھی۔
دالیا شینڈلن نے اسرائیلی اخبار ہآرٹز میں لکھا ہے: بہت سے اسرائیلی فوجیوں کے لیے یہ جنگ بندی ایک بڑی راحت کا باعث بنی ہے۔جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک ایک تہائی ریزرو فوجی ۱۵۰ دن سے زیادہ ڈیوٹی کرچکے ہیں۔ تاہم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ ڈیوٹی کے احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر وہ فوجی جو کئی بار طویل مدت تک خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان میں سے کئی کے لیے یہ وقت سیکڑوں دنوں پر محیط ہے۔
آئی ڈی ایف کے مطابق، جنگ کے دوران بلائے گئے۲ لاکھ ۹۵ ہزار ریزرو فوجی ہیں۔ مائیکل ملشٹائن، جو تل ابیب یونی ورسٹی میں فلسطینی اسٹڈیز فورم کے سربراہ اور آئی ڈی ایف انٹیلی جنس کے سابق اہلکار ہیں، کا کہنا ہے کہ کئی ریزرو فوجی اب گھر واپس آنے کے خواہش مند ہیں۔ انھوں نے کہا: ’خاندان اسرائیل کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہیں‘۔
جنگ کے آغاز سے اب تک۷۵ہزار کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن میں سے ۵۹ہزار صرف ۲۰۲۴ء کے دوران بند ہوئے۔ ڈاکٹر شیری ڈینیئلز، جو کہ ایک غیر سرکاری تنظیم کی ڈائریکٹر ہیں، نے کہا کہ ان کی تنظیم کو ۴۰ہزار سے زیادہ مدد کی درخواستیں موصول ہوئیں، جو گذشتہ برسوں کے مقابلے میں ۱۰۰ فی صد اضافہ ظاہر کرتی ہیں۔ دوسری تنظیموں، جیسے ناتال، نے خودکشی کے رجحانات رکھنے والے افراد کی طرف سے رابطوں میں ۱۴۵ فی صد اضافہ رپورٹ کیا۔ آئی ڈی ایف کے مطابق: ۲۰۲۴ء میں ۲۱ فوجیوں نے اپنی جان لے لی۔
ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ جنگ بندی کا برقرار رہنا غیر یقینی ہے، کیونکہ عدم اعتماد اور غیرحل شدہ مسائل کسی بھی وقت کشیدگی کو دوبارہ ہوا دے سکتے ہیں۔ ان حالات میں، کچھ تجزیہ کار چھوٹی کامیابیوں کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ یعقوب کاتز لکھتے ہیں:’’کبھی کبھی ہمارے لوگوں کی واپسی ہی کافی ہوتی ہے‘‘۔ یہ بیان ایک قوم کی تلخ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، جو امن کی خواہش کے باوجود مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہتی ہے۔
غزہ میں انسانی بحران بدستور ایک بڑا المیہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت (WHO) کے مطابق: غزہ میں صحت کے نظام کی بحالی کے لیے اگلے پانچ سے سات برسوں میں کم از کم ۱۰؍ ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ غزہ کے نصف سے کم ہسپتال اس وقت کام کر رہے ہیں، جس کے باعث جنگ بندی کی کامیابی فوری اور پائیدار انسانی امداد پر منحصر ہے۔
بہت سے اسرائیلیوں کے لیے جنگ بندی تنازعے کے طویل اور بے رحم دورانیے کے بعد سکون کا ایک مختصر لمحہ ہے۔ یرغمالیوں کی واپسی نے خاندانوں کے لیے سکون اور عارضی ریلیف کا احساس پیدا کیا ہے۔ اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کےمقصد سے جنگ شروع کی تھی، مگر وہ ہدف حاصل نہیں ہوا۔ امریکا کے سابق وزیرخارجہ انٹونی بلنکن کے مطابق حماس کے جتنے عسکری اسرائیل نے ہلاک کیے، اتنے ہی وہ دوبارہ بھرتی کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ کیا دنیا اب سنجیدگی کے ساتھ مسئلہ فلسطین کوفلسطینی عوام کی خواہشات اور خطے کے اطمینان کے مطابق حل کرنے کی طرف گامزن ہوگی تاکہ ایک پائیدار امن قائم ہوسکے۔
فلسطین کے ممتاز مزاحمتی شاعر محمود درویش [۱۹۴۱ء- ۲۰۰۸ء] نے اپنے اردگرد پھیلے رنج و اَلم کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا:
جنگ ختم ہو جائے گی اور رہنما ہاتھ ملائیں گے، لیکن وہ بوڑھی عورت اپنے شہید بیٹے کا انتظار کرتی رہے گی، وہ لڑکی اپنے محبوب شوہر کا انتظار کرے گی، اور وہ بچے اپنے بہادر باپ کا انتظار کرتے رہیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کس نے وطن بیچا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ قیمت کس نے چکائی۔
غزہ میں جنگ ر ک سکتی ہے، لیکن اس کے چھوڑے گئے زخم نسلوں تک رستے رہیں گے۔ جنگ بندی، ایک ایسا لفظ ہے جو زخموں کے لیے مرہم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ان گہرے زخموں کو بھرنے کے لیے ناکافی ہے جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ یہ جنگ بندی رحم کا عمل نہیں بلکہ بڑھتے ہوئے عالمی غصے کے دباؤ کو کم کرنے کی ایک مجبوری ہے۔ مہینوں کی بے رحمانہ بمباری کے بعد، جب غزہ کو راکھ اور ملبے میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہزاروں افراد، بشمول بچوں کا خون اس کی ریت اور منوں وزنی عمارتی ملبے میں شامل ہوگیا، سوال یہ ہے: اس درندگی کا حساب کون دے گا؟
نیتن یاہو، وہ شخص جس کا نام تاریخ میں ایک ہولناک جنگی مجرم کے طور پر لکھا جائے گا، اسرائیل کی جنگی مشین کا سرغنہ ہے۔ یہ کوئی بے بس جنگی مجرم نہیں، بلکہ ایک ایسا شخص ہے جس نے جنگ کو سیاسی آلے اور اپنی ڈگمگاتی قیادت اور کرپشن اسکینڈلز سے توجہ ہٹانے کے لیے ہنرمندی سے استعمال کیا ہے۔ اس نے اپنے عوام کے خوف اور دنیا کی بے حسی کو ہتھیار بنا کر جدید دور کی سب سے سفاکانہ فوجی مہمات میں سے ایک کو انجام دیا۔
غزہ کی تباہی محض ’ضمنی نقصان‘ نہیں تھی بلکہ یہ جان بوجھ کر کی گئی تھی۔ خاص طور پر ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، پناہ گزین کیمپوں کو مٹی میں ملا دیا گیا، اور پورے خاندانوں کو موت کی نیند سُلا دیا گیا۔ اسرائیل نے ’درست نشانے‘ کا دعویٰ کیا، لیکن پیچھے بے انتہا تباہی چھوڑی۔ شہریوں کو نشانہ بنانا، بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنا، اور محاصرہ، جس نے غزہ کو کھلی جیل میں تبدیل کر دیا، یہ سب منظم جنگی جرائم ہیں۔ نیتن یاہو کی حکومت، اپنے انتہا پسندانہ نظریات کو بین الاقوامی قوانین کی بے حُرمتی کے ساتھ، واضح کر چکی ہے کہ کوئی فلسطینی زندگی محفوظ نہیں، چاہے وہ کتنی ہی کم عمر یا معصوم کیوں نہ ہو۔
لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نیتن یاہو نے اکیلے یہ سب نہیں کیا۔ اس کے بموں پر Made in USA کی مہر تھی۔ وہ ایف-۱۶طیارے جو غزہ کے محلوں کو زمین بوس کر گئے، امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے فراہم کیے گئے۔ امریکا، جو سفارت کاری کا بہانہ کرتا ہے، عشروں سے اسرائیل کو سزا سے بچانے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ امریکی حکومت نے غزہ میں ہونے والے مظالم پر آنکھیں بند کر لیں، اور بار بار اسرائیل کے ’دفاع کے حق‘ کا راگ الاپتی رہی۔
غزہ کے زندہ رہنے کے حق کو چھین لیا گیا۔ ان ہزاروں فلسطینی بچوں کا کیا جرم ہے کہ جو کبھی بڑے نہیں ہو سکیں گے، جن کے خاندانوں کی زندگیاں امریکی بموں نے ختم کر دیں؟ اسرائیل کے لیے امریکا کی خفیہ اور علانیہ حمایت ایک زبردست اخلاقی دیوالیہ پن ہے۔ بین الاقوامی فورمز پر اسرائیل کو جواب دہی سے بچانے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ویٹو کرنے کے ذریعے، امریکا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انصاف اور انسانیت سے اسے کچھ علاقہ نہیں۔
یہ جنگ صرف اسرائیل کی بے رحمی یا امریکا کی شراکت داری کو ظاہر نہیں کرتی، بلکہ اس نے پورے عالمی نظام کے دیوالیہ پن کو بھی بے نقاب کیا۔ نام نہاد بین الاقوامی ادارے، جو انصاف کے محافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، غزہ کے راکھ میں تبدیل ہونے پر محض تماشائی بنے رہے۔ اقوام متحدہ، جو امن کی محافظ ہونے پر فخر کرتی ہے، ’تشویش‘ کے بیانات جاری کرنے تک محدود رہی۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت، جو بظاہر جواب دہی کی علامت ہے، فیصلہ کن کارروائی نہ کرسکی۔
اور پھر وہ ممالک جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علم بردار کے طور پر پیش کرتے ہیں، غزہ کی تکالیف دیکھ کر خاموش رہے، یا دوسرے لفظوں میں بدتر، شریکِ جرم بنے۔ ان کی منافقت تاریخ اور انسانیت کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے۔
لیکن شاید سب سے بڑی غداری مسلم حکمران طبقوں کی جانب سے ہوئی۔ وہ جو اپنے آپ کو اسلام کا محافظ سمجھتے ہیں اور امت کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، سب سے بڑے منافق ثابت ہوئے۔ خلیجی راجواڑوں سے لے کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی دوڑ میں ہلکان حکمرانوں تک، جو خانگی اقتدار کی بھیک کے لیے غزہ پر حملے کو خاموشی سے سراہتے رہے۔ ان کے اقدامات فلسطینیوں ہی نہیں بلکہ ان تمام اصولوں سے سنگین بے وفائی ہے جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی منافقانہ خاموشی، ان کی مجرمانہ شراکت، ان کی بزدلی کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔
اس سب کچھ کے باوجود آج غزہ کے کھنڈرات میں اُمید کی چمک موجود ہے۔ یہ فلسطینی عوام کے عزم اور ان کے ناقابلِ یقین حوصلے میں ہے، جسے انھوں نے بدترین اور انسانیت سوز مظالم کے باوجود برقرار رکھا ہے۔ یہ ان عام لوگوں کی آوازوں میں ایک طاقت ور ترین آواز ہے جنھوں نے دنیا بھر میں رنگ و نسل اور مذہب و طبقہ کی تفریق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یک جہتی کے لیے مارچ کیا اور غزہ کی تکالیف کو بھلانے سے انکار کیا۔
جب ہتھیار خاموش ہو جائیں، تو ہماری اُمید کا مرکز یہ ہدف ہے کہ جنگ بندی مزید تباہی سے پہلے کا ایک وقفہ نہیں، بلکہ ایک طویل عرصے سے واجب احتساب کا آغاز ہو۔ احتساب جنگی مجرموں جیسے نیتن یاہو کا، سہولت کاروں جیسے بائیڈن کا، اور ہر اس ادارے اور رہنما کا، جنھوں نے غزہ سے منہ موڑ لیا۔
ہم اس خطے میں دائمی امن کے لیے دُعاگو ہیں، لیکن امن قبروں اور راکھ پر تعمیر نہیں ہوسکتا۔ یہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کی عزت بحال کرنی چاہیے جنھیں طویل عرصے سے محروم رکھا گیا، اور ان لوگوں کو جواب دہ ٹھیرانا چاہیے جنھوں نے اس ڈراؤنے خواب کو تقویت دی۔ غزہ کے قبرستان اس قیمت کی خوفناک یاد دہانی کے لیے پکارتے، جھنجوڑتے رہیں گے، جو دُنیا میں دھن، دھونس اور اقتدار کے بھوکوں نے فلسطین کو چکانے دی۔
جب غزہ کی محصور فلسطینی سرزمین پر برستی گولیاں عارضی طور پر خاموش ہوئیں، ماہرین اور میڈیا ماہرین نے ترکیہ کے شہر استنبول میں جمع ہو کر فلسطینی موقف اور مقدمے کو تشکیل دینے کے لیے ایک واضح اپیل کی۔ چوتھے فلسطینی انٹرنیشنل میڈیا اینڈ کمیونیکیشن فورم یعنی ’تواصُل‘ نے اُمید اور عزم کی علامت کے طور پر کام کیا، جس کا مقصد یہ امر یقینی بنانا تھا کہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے ہونے والی تباہی عالمی سطح پر گفتگو کا اَٹوٹ حصہ بنی رہے۔
اس فورم نے دنیا بھر سے آوازوں کو اکٹھا کیا تاکہ فلسطینی موقف کو اُجاگر کیا جا سکے اور ان غلط معلومات کا مقابلہ کیا جا سکے، جو ان کی جدوجہد کی حقیقت کو دھندلا دیتی ہیں۔ ۱۸-۱۹ جنوری کو ’فلسطینی موقف: ایک نیا دور‘ کے موضوع کے تحت منعقدہ اس کانفرنس میں ۵۰ سے زائد ممالک سے ۷۵۰ سے زیادہ شرکاء نے شرکت کی، جن میں صحافی، مصنّفین، مدیران، نشریاتی ماہرین، فوٹوگرافر، فن کار اور ماہرینِ تعلیم شامل تھے۔ غزہ میں تباہی اور انسانی بحران کے پس منظر میں اس کانفرنس نے روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا دونوں کا استعمال کرتے ہوئے، فلسطینی موقف فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
افتتاحی تقریب کے دوران، ’تواصُل‘ کے سیکریٹری جنرل احمد الشیخ نے فلسطینیوں کی حالت زار کی درست نمائندگی کی اشد ضرورت پر زور دیا۔ انھوں نے فلسطینیوں کو درپیش خوفناک حالات، – عشروں کے منظم جبر سے لے کر خوراک کی قلت، مسلسل بمباری اور نقل مکانی کی فوری ہولناکیوں تک – کی وضاحت کی۔ انھوں نے ان مظالم کو ’اسرائیلی نسل کشی‘ قرار دینے سے گریز نہیں کیا اور میڈیا ماہرین پر زور دیا کہ وہ سچائی کو اُجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں‘‘۔
الشیخ نے کہا:’’ہمیں فلسطینی مقصد کو روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے حمایت فراہم کرنی چاہیے۔ یہ ایک نئے دور میں انتہائی اہم ہے‘‘۔ انھوں نے فلسطینیوں کے عزم و استقلال کو سراہا، جو شدید مشکلات کے باوجود اپنے حقوق اور شناخت کا دفاع کرتے رہے ہیں۔ کانفرنس کا ایک سنجیدہ لمحہ ان صحافیوں کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کا تھا، جو اس خونیں جنگ کی رپورٹنگ کے دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یاد رہے ۷؍ اکتوبر ۲۰۲۳ء کے بعد سے اب تک غزہ میں ۲۲۰ سے زائد میڈیا پروفیشنلز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جو ان خطرات کی خوفناک یاد دہانی ہے، جن کا سامنا ان افراد کو ہوتا ہے جو مظالم کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کانفرنس میں ان صحافیوں کی تصاویر کی ایک جذباتی نمائش شامل تھی، جن میں سے کئی کو آرٹیفشل انٹیلی جنس کے ذریعے متحرک کیا گیا، تاکہ ان کی آوازیں اور کہانیاں طاقت ور انداز میں گونج سکیں۔
کانفرنس مباحث کے دوران ۱۲ خصوصی ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا، جن میں فلسطینی بیانیے کے نئے دور کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بحث کی گئی۔ ایک خاص طور پر مفید ورکشاپ بعنوان ’فلسطینی بیانیے کی ترقی میں جدید ڈیجیٹل ٹکنالوجیز کا استعمال‘ تمام صحافیوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ ایک اور سیشن میں ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکا اور لاطینی امریکا میں غزہ کی کوریج پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس میں فلسطینی صحافیوں اور فوٹوگرافروں کو درپیش چیلنجوں، ان کے حقوق اور اسرائیلی قبضے کے تحت درپیش رکاوٹوں کو بھی اُجاگر کیا گیا۔
تنظیم کے چیلنجوں اور کامیابیوں پر ’تواصُل‘ کے ڈائرکٹر بلال خلیل نے روشنی ڈالی۔ انھوں نے کہا:’’گذشتہ گیارہ برسوں سے ہم صحافیوں اور اداروں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ فلسطینی مسئلے کو درست طور پر اُجاگر کریں‘‘۔انھوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ: دنیا بھر کے میڈیا آؤٹ لیٹس، بشمول بھارت، فلسطین کے بارے میں سچائی کی رپورٹنگ کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں گے۔ انھوں نے غزہ اور فلسطینی مسئلے پر مستقل اور درست رپورٹنگ کرنے والے آئوٹ لیٹس کی تعریف کی۔ فلسطینی جدوجہد کے تسلسل کے بارے میں انھوں نے کہا کہ فلسطین پر قبضہ ۷۷ سال سے جاری ہے، اور فلسطینی عوام کی جدوجہد آج بھی جاری ہے، جو ایک صدی سے زائد عرصے کی مزاحمت کا مظہر ہے۔ انھوں نے خاص طور پرکہا:’’فلسطینی مسئلہ صرف ایک انسانی بحران نہیں، جہاں ایک قوم کو زبردستی بے گھر کیا گیا اور وہ مدد کی محتاج ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی جدوجہد ہے جو اپنی زمین پر آزادی اور عزّت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں‘‘۔
انھوں نے مزید کہا: ’’جب وہ اپنی آزادی حاصل کر لیں گے، تو وہ دنیا بھر میں ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ لہٰذا، میں بین الاقوامی میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف ہونے والی نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹنگ کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں، اور اُن بین الاقوامی انصاف اور انسانی حقوق کے فریم ورک کی حمایت کریں، جو عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں‘‘۔
جو لوگ اس روح پرور اور انسانیت دوست کانفرنس میں شریک ہوئے، ان کے لیے یہ صرف ایک کانفرنس نہیں تھی، بلکہ یک جہتی کی طاقت اور انسانی روح کی پائیداری کا ایک عالمی ثبوت تھی۔ شرکا کے انہماک اور شوق و جذبے کو دیکھ کر ایک صحافی نے برملا کہا: ’’ہم صرف کہانیاں نہیں سنا رہے؛ ہم ایک ایسی تاریخ کو محفوظ کر رہے ہیں جو کبھی فراموش نہیں ہونی چاہیے‘‘۔
حال ہی میں امریکا کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹیسلا کے چیف ایگزیکٹو اور ٹرمپ کے سیاسی معاون ایلون مسک کے بیانات اور اقدامات نے دنیا بھر میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ سامراجی قوم پرستی پر مبنی ان کے بیانات اور سامراجی عزائم نے نہ صرف عالمی جغرافیائی و سیاسی توازن کو متاثر کیا ہے بلکہ عالمی تعاون اور امن کے لیے خطرہ بھی پیدا کر دیا ہے۔ یہ تبدیلی خاص طور پر خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی سفارت کاری کے میدان میں پیدا ہوئی ہے، جس نے دنیا بھر میں کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ٹرمپ کے اختیار کیے گئے رویے اور ایلون مسک کے ایسے متنازعہ بیانات سے پیدا ہونے والی تشویش کو بہت سے لوگوں نے شدت سے محسوس کیا ہے۔
اپنی صدارت (۲۰۱۶ء-۲۰۲۰ء) کے دوران، ڈونلڈ ٹرمپ پر اکثر الزام لگایا جاتا رہا کہ انھوں نے قوم پرستی کے ایک ایسے انداز کو فروغ دیا، جو امریکی عوام کے ایک خاص طبقے میں مقبول تو ہوا، لیکن سفارتی نزاکتوں کو قتل کرنے کی قیمت پر۔ ان کا نعرہ ’سب سے پہلے امریکا‘، جو بظاہر قومی مفادات کو ترجیح دینے کے لیے تھا، اکثر تنقید کی زد میں رہا کہ اس سے دُنیا کی اقوام میں امریکا کو تنہا کرنے کی تلخی ملی اور قائم شدہ بین الاقوامی اتحادوں کو نقصان پہنچا۔
مزید تشویشناک امر یہ ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے دیرینہ اتحادیوں کے ساتھ اجنبیت بلکہ گاہے دشمنی پر مبنی اور عالمی سطح پر زیادہ جارحانہ پالیسیوں کے مطالبات یا دھونس ہیں۔ گرین لینڈ کی حیثیت، نہر پاناما سے متعلق اشتعال انگیز بیانات، اور کبھی کے بھولے بسرے علاقائی دعوؤں کی بحالی جیسے مسائل پر ٹرمپ کا جارحانہ موقف عالمی برادری کے لیے دھچکے کا باعث بنے ہیں۔ گرین لینڈ، جو ڈنمارک کی خودمختاری کے تحت آتا ہے، پر قبضے کی دھمکیاں اور پاناما نہر ، جو ایک اہم بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے، پر غلبہ جتانے (dominance) ،اپنی برتری اور دعوے نے نوسامراجی (Neo-Imperialist) طرز ِ بیان کو ایک نئی نعرے بازی کا عکاس بنایا ہے، اور مذموم نوآبادیاتی دور کی تلخ یادوں کو تازہ کیا ہے۔
ٹرمپ نے مسلسل امریکا کے روایتی اتحادیوں، مثلاً کینیڈا، برطانیہ، جرمنی اور ڈنمارک کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ اتحادی، جو کبھی امریکی خارجہ پالیسی کے مضبوط ستون سمجھے جاتے تھے، آج غیردوستانہ بیانات اور غیر معمولی مطالبات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ ٹرمپ کا یہ دورِاقتدار بین الاقوامی تعلقات میں اپنے اتحادیوں کے لیے ہمدردی کے فقدان سے داغ دار ہوگا۔
ان کی حکومت کا بین الاقوامی تنازعات، جیسے یوکرین اور امریکا-روس کشیدگی کے بارے میں موقف ایک غیرسنجیدہ رویے کی عکاسی کرتا ہے، جو بین الاقوامی سفارت کاری کی پیچیدگیوں کو نظرانداز کرتا ہے۔ وہ تجزیہ کار جو امید کر رہے تھے کہ ٹرمپ کی صدارت کشیدگی میں کمی اور بین الاقوامی مسائل سے دستبرداری کا باعث بنے گی، وہ اس طرزِعمل اور طرزِ فکر سے غلط ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہے۔
ایلون مسک، جو ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک اربوں ڈالر کے اجارہ دار سرمایہ دار ہیں، وہ بھی تنازعے کا ذریعہ بنے ہیں۔ مسک کے اشتعال انگیز بیانات نے، جن میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اسلاموفوبک ہیں، دُنیا بھر میں مسلم معاشروں اور برادریوں کے لیے شدید پریشانی پیدا کی ہے۔ ان کے تبصروں نے جو بعض اوقات تضحیک پر مبنی ہوتے ہیں، انھوں نے سماجی سطح پر نشانہ بننے والے مسلمانوں میں ردعمل پیدا کیا ہے۔
ایلون مسک کی شخصیت، جسے ان کے بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا اثر و رسوخ نے مزید مضبوط بنایا ہے، موجودہ تلخیوں کو بڑھاوا دیتی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں، ایلون مسک نے برطانوی سیاست میں مداخلت کی ہے، اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X کو استعمال کرتے ہوئے برطانیہ کے وزیراعظم اور ان کی حکومت کے دیگر اراکین کے بارے میں غیر مصدقہ افواہیں پھیلائیں۔ ۲۱کروڑ ۱۰لاکھ فالورز میں پھیلائے گئے، ان کے اشتعال انگیز بیانات میں، مسک نے وزیراعظم اور لیبر پارٹی کے دیگر قانون سازوں پر برطانیہ کے نام نہاد ’گرومنگ گینگز‘ کو معاونت فراہم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ اصطلاح ایک اسکینڈل کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں کئی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیسز شامل تھے، جہاں مختلف شہروں میں لڑکیوں کو مردوں کے گروہوں نے نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ زیادتی کی۔ ان مجرموں کی اکثریت مبینہ طور پر برٹش نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ ایلون مسک کی پوسٹوں میں بے شمار غلطیاں موجود ہیں، جنھوں نے ایک انتہائی مشہور مسئلے کو ایسے پیش کیا ہے جیسے یہ حال ہی میں دریافت ہوا ہو۔ ان تبصروں نے برطانیہ میں نسل پرستی، امیگریشن، اور استحصال سے متعلق شدید مباحثے کو دوبارہ جنم دیا ہے اور اُس تکلیف دہ اسکینڈل پر توجہ مرکوز کی ہے، جو پہلے ہی معاشرتی تقسیم، تضاد اور گاہے تصادم کا باعث بن چکا ہے۔
عالمی اہمیت کے مسائل، جیسے غزہ کی جنگ اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایلون مسک کے موقف کو خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور مسلم ممالک میں شدید تنقید کا سامنا ہے۔ ان کی بیان بازی نے امریکا اور مسلم دنیا کے درمیان پولرائزیشن اور کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے، جس سے سفارت کاری اور بین الثقافتی ہم آہنگی کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔
ایسے وقت میں جب دنیا کو ثقافتی اور قومی سرحدوں سے بالاتر ہو کر تعاون کی اشد ضرورت ہے، مسک کے متنازعہ بیانات اور اقدامات امریکا اور اس کے بین الاقوامی شراکت داروں کے درمیان تقسیم کو مزید پھیلا بھی رہے ہیں اور گہرا بھی کر رہے ہیں۔ ’فلسطین-اسرائیل تنازع‘ جیسے حساس مسئلے پر ان کا غیرسنجیدہ رویہ اور خطے کی پیچیدہ تاریخ کو نظر انداز کرنے کی بظاہر لاپروائی نے صورتِ حال کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ ان بیانات نے نہ صرف موجودہ دشمنیوں کو بڑھایا ہے بلکہ مسلم دُنیا کے ساتھ معاملات میں امریکا کی ساکھ کو بُری طرح کمزور کیا ہے۔
ٹرمپ اور مسک دونوں کے اقدامات ییل یونی ورسٹی کے تاریخ دان پال کینیڈی کی مشہور کتاب The Rise and Fall of the Great Powers میں پیش کیے گئے نظریے کی عکاسی کرتے ہیں۔ کینیڈی کا ’امپیریل اوور اسٹریچ‘ کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ’’تاریخ میں عظیم طاقتیں اکثر اپنی فوجی اور اقتصادی صلاحیتوں کو قابلِ برداشت حد سے زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ یہ عمل ان کے عالمی اثر و رسوخ میں کمی کا باعث بنتا ہے کیونکہ وہ تنازعات میں اُلجھ کر عالمی غلبے کی ضروریات اور اندرونی استحکام کو برقرار رکھنے کے درمیان توازن قائم کرنے میں ناکام رہتی ہیں‘‘۔
ٹرمپ کی قوم پرستی اور علاقائی دعوؤں کو جتانا، ساتھ ہی دیگر ممالک کے خلاف جارحانہ رویہ اپنانے کا اعلان کرنا، اس تصور کی جدید شکل ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے امریکی اثر و رسوخ کو جارحانہ اقدامات کے ذریعے بڑھانے کی کوشش، چاہے وہ ’گرین لینڈ‘ یا ’پاناما نہر‘ جیسے علاقائی تنازعات ہوں یا ان کی عمومی خارجہ پالیسی، امریکا کو طاقت کے حد سے تجاوز کرنے کے ایک خطرناک مقام پر لے آئے ہیں۔ ان اقدامات نے دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، خاص طور پر امریکی اتحادیوں میں، جو اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ ’امریکی سلطنت‘ اپنی طاقت کو بدمست ہاتھی کی طرح بروئے کار لانے کی راہ پر چلنا چاہتی ہے۔
جان میرشائمر، ایک ممتاز سیاسی سائنس دان، اور جیفری ساکس، ایک مشہور ماہرِ اقتصادیات، نے ایسی تشریحات پیش کی ہیں، جو ٹرمپ اور مسک جیسے لیڈروں کی پالیسیوں میں اصلاحی نقطۂ نظر فراہم کرتی ہیں۔ میرشائمر کے بین الاقوامی تعلقات پر کام میں بے قابو طاقت کے اظہار کے خطرات اور عظیم طاقتوں کی عالمی معاملات کو قابو کرنے کی صلاحیت کو سمجھنے کے رجحان پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق: ’’امریکی خارجہ پالیسی کو طاقت کے توازن پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات کو منظم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ غلبے کی خواہش میں خود کو حد سے زیادہ بڑھائے‘‘۔
دوسری طرف، جیفری ساکس نے اس بات کو مسلسل اُجاگر کیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی، اقتصادی عدم مساوات، اور تنازعات کے حل جیسے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کثیرالجہتی تعاون کی ضرورت ہے۔ان کا موقف سفارت کاری اور بین الاقوامی شراکت داریوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جو اکثر ٹرمپ کی بیان بازی اور مسک کے بیانات میں نظرانداز کی جاتی ہے۔ ساکس نے اس تصور کو چیلنج کیا ہے کہ یک طرفہ اور جارحانہ خارجہ پالیسیاں طویل مدتی امن یا استحکام کا باعث بن سکتی ہیں۔
یہ اسکالرز ٹرمپ اور مسک کی ’جارحانہ نو سامراجیت‘ کے مقابلے میں ایک متوازن نقطۂ نظر کی وکالت کرتے ہیں۔ وہ عالمی معاملات کے لیے ایک زیادہ معتدل اور تعاون پر مبنی طریقۂ کار کی حمایت کرتے ہیں، جو طاقت کی حدود کو تسلیم کرتا ہے اور شراکت داریوں کو دشمنیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ڈونلڈ ٹرمپ کے فروغ دیے گئے قوم پرستانہ اور سامراجی عزائم، جنھیں ایلون مسک نے مزید تقویت دی ہے، عالمی امن اور استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں۔
اطلاع ہے کہ ’پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ‘ نے نہم جماعت کے لیے سات کتابوں کا نیا نصاب تیار کر لیا ہے، اب طلبہ اپنی مرضی سے اردو یا انگریزی میں نصاب پڑھ سکیں گے۔ خبر کے مطابق پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے تمام تعلیمی اداروں اور بورڈز کو کتابوں کی تبدیلی کے حوالے سے آگاہ کردیا ہے۔جولائی۲۰۱۹ء میں حکومت پنجاب نے ذریعۂ تعلیم کو انگریزی سے تبدیل کر کے اردو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے پنجاب کے محکمۂ تعلیم نے بائیس اضلاع میں اساتذہ، طلبہ اور والدین کا سروے کروایا تھا، جس کے مطابق ہر طبقے سے ۸۵ فی صد افراد نے اردو کو ذریعۂ تعلیم بنانے کے حق میں رائے دی۔ اس کے باجود ذریعۂ تعلیم میں زبان کی دورنگی جاری رہی۔ یہ خبر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ حیرت ہے کہ جو بات ’ایسٹ انڈیا کمپنی‘ کو ۱۸۳۷ء میں معلوم ہو گئی تھی، جب انھوں نے اردو کو سرکاری زبان بنانے کا فیصلہ کیا تھا وہ بات ہمارے منصوبہ سازوں کو اب تک کیوں معلوم نہیں ہو سکی ہے؟ برطانوی دورِ حکومت میں ہندستان کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک ہی بڑی یونی ورسٹی، کلکتہ یونی ورسٹی تھی، جس کا ذریعۂ تعلیم انگریزی تھا۔ انگریزی کو یہ منصب فارسی سے چھین کر دیا گیا تھا، جس نے سات سو سال تک ہندستان کے نظام تعلیم پر حکمرانی کی تھی۔ خطے کی تہذیبی اور تعلیمی زبان سے اس کا منصب چھین کر ایک اجنبی زبان کو دیے جانے کے نتائج اسی دورمیں آنا شروع ہو گئے تھے۔
حیرت ہے کہ ہمارے اربابِ حل و عقد آج تک ان نتائج سے بے خبر ہیں۔ ہم کوئی تبصرہ کیے بغیر انگریزوں ہی کے قائم کردہ دہلی کالج کے ایک پرنسپل ای ولموٹ کی ۱۳دسمبر ۱۸۶۷ء کی رپورٹ کی جانب توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ یہ رپورٹ آج بھی ’محکمہ پنجاب آرکائیوز‘ میں موجودہے۔ ای ولموٹ، کیمبرج یونی ورسٹی کے ممتاز ماہر تعلیم تھے۔ انھوں نے انگریزی کو ذریعۂ تعلیم بنانے والی کلکتہ یونی ورسٹی کے حاصل کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا:’’ہمارے فاضلین کی اکثریت نہایت سطحی علم کے سوا کچھ حاصل نہیں کر پاتی، خواہ وہ انگریزی ہو یا اس زبان میں حاصل کیے جانے والے دوسرے علوم۔ اس لیے عمومی طور پر اس سے جو ذہنی تربیت ہو رہی ہے، وہ خالص نقالی کے سوا کچھ نہیں‘‘۔
سطحیت ،نقالی اور تحصیلِ علوم میں زبان کی اجنبیت کے باعث پیدا ہونے والی رکاوٹ جیسے عوامل کواسی عہد میں جس اعلیٰ ترین سطح تک محسوس کیا گیا اس کا بڑا ثبوت اورینٹل کالج، پنجاب یونی ورسٹی اور گورنمنٹ کالج لاہور کے بانی ڈاکٹر جی ڈبلیو لائٹنر کے خیالات ہیں، جو انھوں نے ہندستان آنے اور یہاں اعلیٰ ترین تعلیمی عہدوں پر فائز ہونے کے بعد ظاہر کیے۔ یہی احساس تھا، جس نے ۱۸۶۵ء میں انجمن پنجاب کی تشکیل کی اور ڈاکٹر جی ڈبلیو لائٹنر نے اس نیم علمی، ادبی، سماجی انجمن کے مقاصد میں یہ بات شامل کروائی کہ ’’اس انجمن کے ذریعے قدیم مشرقی علوم کا احیا کیا جائے گا اور اس ملک کے باشندوں کو مقامی زبانوں کے ذریعے تعلیم دے کر ان میں مفید علوم کی اشاعت کی جائے گی‘‘۔ اس کے نتیجے میں جہاں لاہور سے اردو اخبارات ورسائل جاری ہوئے، وہاں اورینٹل اسکول بھی قائم ہوا۔ ’انجمن پنجاب‘ کی رپورٹوں کے مطابق قیام انجمن کے پہلے ہی سال ۱۱ستمبر ۱۸۶۵ء کو منعقد ہونے والے اجلاس میں ڈاکٹر لائٹنر نے اورینٹل یونی ورسٹی کے قیام کا تخیل بھی پیش کیا، جس کے نتیجے میں بعد ازاں ۱۸۸۲ء میں پنجاب یونی ورسٹی کا قیامِ عمل میں آیا۔
تاریخ کے طالب علم کے لیے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ تہذیبی تفاوت کے جس المیے کا رونا آج رویا جاتا ہے، اسے سب سے پہلے ان لوگوں نے محسوس کر لیا تھا جنھیں ہماری تہذیب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آج ہم مسٹر میکلوڈ کا نام صرف لاہور کی ایک سڑک کی نسبت سے جانتے ہیں۔بہت کم لوگوں کو معلوم ہو گا کہ سر ڈونلڈ فریل میکلوڈ ۱۸۶۵ء سے ۱۸۷۰ء تک پنجاب کے گورنر رہے۔ جب اہلِ پنجاب کی جانب سے مشرقی علوم کی ایک یونی ورسٹی کے قیام کے مطالبے پر مشتمل ایک محضر نامہ انھیں پیش کیا گیا، تو انھوں نے اس حوالے سے لکھا تھا کہ غیر ملک کی زبان میں تعلیم دینے سے تعلیم کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ مسئلے کو تاریخی تناظر میں دیکھتے ہوئے مسٹرمیکلوڈ نے یہ بھی لکھا کہ خود انگلستان میں جہاں شائستگی کے حصول کے لیے لاطینی اور یونانی زبانوں کی تحصیل ضروری سمجھی جاتی ہے، عام تعلیم کے لیے دیسی زبان یعنی انگریز ی ہی کو موزوں سمجھا جاتا ہے‘‘۔
مسٹر میکلوڈ کی یہ تحریر اپنے اندر بصیرت کا خاصا سامان رکھتی ہے۔ اس تحریر میں اعتراف کیا گیا کہ نئے نظامِ تعلیم نے اردو اور ہندی کی ترقی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ صرف یہی نہیں اس نظام سے کوئی اچھا انگریزی دان بھی نہیں نکلا بلکہ اس نظام کا حاصل فقط وہ لوگ ہیں جو سرکاری ملازمت کے حصول کے لیے محض انگریزی بول چال سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے طلبہ کا فقدان ہے، جو تعلیمی اداروں سے حصولِ علم کی خاطر منسلک ہوتے ہوں۔ گورنر نے اس طریقۂ تعلیم کو ناقص او ر افسوس ناک قرار دیا۔ سر ڈونلڈ میکلوڈ نے اورینٹل یونی ورسٹی کی اس تجویز پر کلکتہ کالج کے پرنسپل میجر ناسائو لیز\سے بھی مشورہ کیا۔ ناسائولیز نے یہ کہتے ہوئے کہ ’’اس نظامِ تعلیم نے صرف کلرک پیدا کیے ہیں، علمی خوبیوں کا حامل کوئی فرد پیدا نہیں کیا‘‘، گورنر پنجاب کے خیالات کی تائید کی۔
اجنبی زبان میں تعلیم کے ان نتائج سے آگاہ ہو جانے پر انگریز حکام نے مقامی باشندوں کو مقامی زبانوں ہی میں تعلیم دینے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں پنجاب یونی ورسٹی قائم ہوئی۔ پنجاب یونی ورسٹی کے ایک کانووکیشن میں جب وائس چانسلر نے خطبۂ استقبالیہ انگریزی میں پیش کیا تو وائسرائے ہند نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے مقامی یونی ورسٹی کے وائس چانسلر کو اردو میں خطاب کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ بنیادی اور اصولی بات جس سے انگریز واقف تھے، ہم نجانے کیوں اب تک اس سے واقف نہیں ہو سکے؟ ذریعۂ تعلیم کی بار بار تبدیلی سے نئی نسلوں کا جو نقصان ہوتاہے اور معاشرتی تفاوت کی جو راہیں کھلتی ہیں، ہم اس سے بے خبرہیں یا بے نیاز؟ پچھلے دنوں ایک دوست نےیہ بتا کر حیران کر دیا کہ اب ہمارے سرکاری دفاتر اور ٹیلی فون کمپنیوں میں اردو پیغام رسانی کے لیے رومن حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔ توجہ دلانے پر کہا جاتا ہے: ’’پالیسی یہی ہے‘‘! یاللعجب؟ زبان کے بعد رسم الخط بھی ہاتھ سے جاتا رہا۔ دکانوں کے بورڈ ہوں یا گاڑیوں کے نمبر ہمارے ہاں انگریزی میں لکھے جاتے ہیں، حالانکہ ملک میں انگریزی جاننے والے عوام کی تعدادآٹے میں نمک کے برابر ہے۔ پھرکیا یہ طریق کار ابلاغ کے اصولوں پر بھی پورا اترتا ہے؟ آپ جن لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، کم از کم درجے میں زبان اور حروف تو وہ استعمال کیجیے، جوان کی سماعتوں اور نگاہوں کے لیے مانوس ہوں۔
معقول حد کے اندر اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد آدمی کے پاس اس کی حلال طریقوں سے کمائی ہوئی دولت کا جو حصہ بچے اسے خود اِن کاموں پر صرف کرنا چاہیے:
اس خرچ کو قرآن نہ صرف یہ کہ ایک بنیادی نیکی کہتا ہے بلکہ تاکیداًوہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسا نہ کرنے میں معاشرے کی مجموعی ہلاکت ہے:
(سیّدابوالاعلیٰ مودودی، ترجمان القرآن، جلد۶۲،عدد۶، فروری ۱۹۶۵ء، ص۳۹-۴۱)