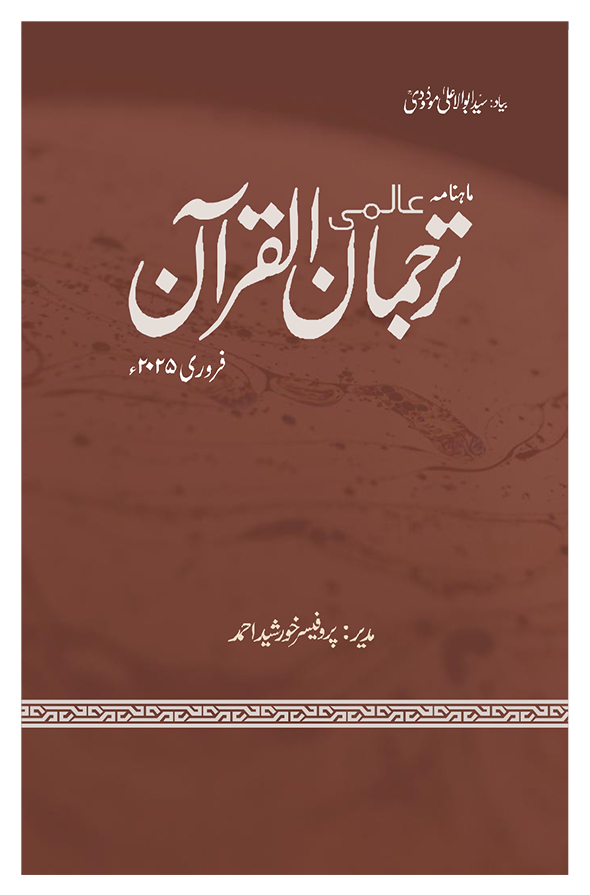
مقاصد شریعہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اجتہادی عمل کے ذریعے معاشرے کے پیش آمدہ مسائل اور درپیش مشکلات کو حل کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی کم از کم اتنی تربیت ضرور ہو، کہ ان میں باہم وحدت و اجتماعیت کا شعور پیدا ہو، تاکہ لوگوں کا اپنے اعتقاد، نظریے اور تہذیب کے ساتھ تعلق مضبوط بنیادوں پر قائم ہو۔ جب معاشرے کے عام لوگوں میں اپنے نظریہ کا شعور اُجاگر ہوتا ہے، تو ان کا اپنے دور کے ان اہلِ علم و دانش کے ساتھ بھی قلبی تعلق پیدا ہوجاتا ہے، جو اپنے دور کے مسائل کو حالات کے تناظر میں سمجھتے ہوں اور ان کا حل اجتماعی یا شورائی اجتہاد کے ذریعے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ عوام اور اہلِ علم و دانش کے مابین تعلق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو بھی معاملات اور ان کے حل کے لیے اجتماعی کوششوں کو سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس اجتماعی شعور کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف نہ صرف قانون سازی کا عمل بہتر ہوتا ہے بلکہ قانون نافذ ہونے کے بعد اس پر عمل درآمد کی صورت بھی بہتر ہوجاتی ہے۔
کسی ملک اور قوم کے حالات میں مثبت اور تعمیری تبدیلی اسی وقت ممکن ہوتی ہے، جب لوگ خود فکر کی بلندی اور اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عظیم الشان کام ملک کے اہل علم و دانش اور قائدانہ صلاحیت رکھنے والے افراد انجام دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:
اِنَّ اللہَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِہِمْ۰ۭ (الرعد۱۳: ۱۱) حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔
اس آیت مبارکہ میں فطرت کا ایک اصول یہ بیان کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنے انعامات سے اس وقت تک محروم نہیں کرتا، جب تک وہ خود اپنے آپ کو علم و شعور اور ان اخلاقی اقدار سے محروم نہ کر لیں جو انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقاء اور کامیابیوں کے لیے ضروری ہیں۔ اس مفہوم کی وضاحت اور بھی بہت سی آیات میں بیان ہوئی ہے۔
ان آیات مبارکہ میں انسانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے عروج و زوال کا ایک اصول اور ضابطہ مقرر کیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں بہت سی فطری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، خیر کی صلاحیتیں بھی ودیعت کی ہیں اور شر کی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں۔ خیر کی صلاحیتوں کو اُجاگر کرنے اور انھیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے باقاعدہ انبیا علیہم السلام کو بھیجا، تاکہ وہ خیر و شر کے فرق کو سمجھا کر انسان کو فلاح و سعادت کے راستہ پر گامزن کریں۔ اب اگر انسان خیر کی صلاحیتوں کو بھلائی کے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ عروج و کمال کو حاصل کر لے گا اور اگر خواہشاتِ نفس کی پیروی کرتے ہوئے شر کی طرف مائل ہوگا، تو اس کے اپنے تخریبی کرتوت اسے زوال اور مصائب میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانونِ فطرت ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا مستحق بننے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے اور وہ کون سا راستہ ہے جو زوال و تباہی کی طرف دھکیل دیتا ہے، جس سے ہر صورت بچنا چاہیے؟
اصل موضوع پر گفتگو سے قبل یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہجِ اصلاح و دعوت پر روشنی ڈال لیں تاکہ مسائل کے حل میں رسولؐ اللہ کا طرزِعمل اور آپؐ کی رہنمائی اچھی طرح واضح ہوجائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہذب اور منظم معاشرے کی تشکیل کے لیے دوچیزوں کی طرف توجہ فرمائی: ایک انسانی فکر کی اصلاح اور دوسری انسانی رویے کی اصلاح۔ اصلاحِ فکر کے لیے حصولِ علم کو فرض قرار دیا اور توحید کی بنیاد پر عقیدہ کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ انسان ہر قسم کی توہم پرستی اور شرک کی ہر صورت سے محفوظ ہوجائے۔ انسانی رویوں کی اصلاح کے لیے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی اور فارمولا نہیں ہوسکتا۔ اخلاقی اصول، عالمی صداقتوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی صحیح الفطرت انسان ان کی خوبیوں کا انکار نہیں کرسکتا۔ اخلاقِ حسنہ اپنے اندر بےپناہ قوت اور دور رس تاثیر رکھتے ہیں۔ دُنیوی زندگی کا کوئی شعبہ اخلاقی اصولوں کو نظر اندازکرکے کامیابی کی شاہراہ پر آگے نہیں بڑھ سکتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بنیادی ستونوں پر اسلامی معاشرے کی تشکیل فرمائی: علم، ایمان اور اخلاق___ یہ تینوں ستون اس قدر اہم ہیں کہ ان میں کوئی ایک ستون بھی منہدم ہوجائے تو سارا معاشرہ زوال کا شکار ہوجاتا ہے۔ تہذیب و تمدن کے استحکام اور ارتقاء کے لیے تینوں لازمی بنیادوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔
سرفہرست بنیادی ستون علم ہے۔ علم محض معلومات کو جمع کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اشیاء کی حقیقت کے ادراک اور اس فہم کا نام ہے، جو معلومات کو منظم انداز میں ترتیب دے کر ان سے نتائج اخذ کر سکے اور اپنے اندر استدلال و استنباط کی صلاحیت کو مضبوط کر سکے۔
علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں علم کی دولت عطا فرماکر بھیجا۔ حضرت آدمؑ جب تک جنت میں رہے ملائکہ کی صحبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی عبادت اور تسبیح و تقدیس کا علم حاصل کیا۔ پھر دنیا میں بھیجا تو وہ علوم بھی عطا فرمائے، جن کی دُنیوی زندگی میں ضرورت پڑ سکتی تھی۔یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کی دُنیوی زندگی کا آغاز وحی الٰہی کی رہنمائی اور علم کی روشنی میں ہوا۔
دنیا میں نسلِ انسانی کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اسے حصولِ علم کے وسائل (Tools) بھی عطا فرمائے تاکہ وہ سمع و بصر، عقل و حواس، مشاہدے اور تجربہ سے اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرتا رہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے پہلا سبق یہی پڑھایا گیا کہ وہ اپنی تمام تر توجہ حصولِ علم پر مرکوز کر دے۔ سورۂ علق کی ابتدائی پانچ آیات پر غور کیجیے۔ وحی کا آغاز ہی صیغۂ امر سے ہو رہا ہے۔ ‘إقرأ’ پڑھیے، ان پانچ آیات کے اسلوبِ بیان کو دیکھیے کہ حصولِ علم کو کس قدر زورِ بیان کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان کا پڑھائی، کتاب و قلم، تعلیم و تعلم اور بحث و تحقیق کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔
صحابہ کرامؓ جو عربی زبان کی بلاغت اور اسلوبِ بیان سے اچھی طرح واقف تھے، انھوں نے ان آیات کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھا۔ انھیں اس بات کا ادراک تھا کہ ایمان و عبادت کی حقیقت کو سمجھنے، زندگی کے انفرادی اور اجتماعی امور کو طے کرنے اور درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر انسان نہ دُنیوی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ اُخروی زندگی ہی میں نجات و فلاح پاسکتا ہے۔
علم ایک بحرِ بےکراں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح انسان کے حالات اور مسائل بھی گونا گوں ہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے میں نئے نئے مسائل اُبھرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر دور اور ہر زمانے میں علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور و فکر سے کام لیا جائے تو علوم و فنون کے نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں، اور انھی میں اپنے مسائل اور درپیش تحدیات کا حل بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ علم بھی عطا فرمایا جو قطعی اور یقینی ہے۔ یہ علم وحی کے ذریعے انبیا علیہم السلام پر نازل ہوا ہے۔
اُمتِ مسلمہ کے پاس علومِ وحی کا سرمایہ قرآنِ حکیم اور سنت نبویؐ کی صورت میں محفوظ ہے، لہٰذا مسلمان اہلِ علم کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ان تصوراتِ علم کو جنھیں وہ اپنی عقل اور حواس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں علومِ وحی کی روشنی میں پرکھ لیں، اس لیے کہ عقل و حواس کے ذریعے جو رائے قائم ہوتی ہے وہ ظنی کہلاتی ہے، اس میں خطا اور غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ ظن و تخمین پر مبنی رائے کو پرکھنے کے لیے علمِ قطعی کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنِ حکیم کے مضامین اور احکام کی وضاحت اور تشریح کا حکم دیا ہے۔ (النحل۱۶: ۴۴)
اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے اُمتِ مسلمہ کو اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہےکہ وہ اپنی عقل اور حواس کو استعمال کرکے وہ علوم اور تربیت ضرور حاصل کریں، جو نہ صرف اُمتِ مسلمہ کی فلاح و سعادت کے لیے ضروری ہیں بلکہ ساری انسانیت کے امن و سکون کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ان علوم کا تعلق تزکیۂ نفس، احسان اور اخلاقِ کریمہ سے ہے۔ جس قوم کی تعلیم و تربیت تزکیۂ نفس اور احسان کے ذریعے کی گئی ہو اور جس کا مزاج اعلیٰ اخلاقی قدروں کے مطابق ڈھل گیا ہو، وہ قوم ایسے اُمور، فن کاری یا فتنہ کی طرف توجہ نہیں دیتی، جس کا مقصد ہی تخریب کاری یا فتنہ و فساد پھیلانا ہو۔
آج کے دور میں تخریب کاری اور دہشت گردی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اس فتنے میں صرف چند پراگندہ ذہنیت کے لوگ ہی ملوث نہیں بلکہ بعض بڑی بڑی حکومتیں بھی تخریب کاری کے عمل کو منظم کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کی قائم کردہ خفیہ ایجنسیوں، مثلاً ’سی آئی اے‘ ، ’موساد‘ اور ’را‘ (RAW) وغیرہ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔
مسلم اُمہ کو دیگر اقوام کے ساتھ مل کر بیرونی اور اندرونی، ریاستی اور اداراتی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مسلم امت اجتماعی طور پر یا پھر کوئی ایک مسلم مملکت یہ فریضہ اس وقت انجام دے سکتی ہے، جب کہ وہ نہ صرف علوم و فنون میں نمایاں حیثیت حاصل کرلے بلکہ سیاسی اور معاشی طور پر بھی مستحکم ہو۔ فکری استحکام کے لیے علمی وسعت کے ساتھ راسخ ایمان و اعتقاد بھی ضروری ہے۔ ایسا ایمان، جو اسلامی معاشرے کا دوسرا بنیادی ستون ہے۔ ایمان تصدیقِ قلبی کا نام ہے، جو یقینِ کامل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ایمان دل و دماغ میں راسخ ہوتا ہے تو انسان کی عملی اور اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
ایمانیات میں تین عقیدے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت___ باقی عقائد انھی تین کا حصہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ذات تو پردۂ غیب میں ہے۔ انسان کو جو کچھ علم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و تقدس، اس کا کائنات کی ہر چیز پر اقتدار، اس کا وسیع و جامع علم، اس کی گرفت اور حساب و کتاب پر قدرت کے بارے میں جب غور کرتےہیں تو انسانوں کے دل خشیتِ الٰہی سے لبریز ہوجاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفاتِ رحمت، عفو و درگزر اور اس کے انعامات و احسانات پر غور کرتے ہیں، تو اہل ایمان کے دلوں میں بےپناہ جذبۂ محبت پیدا ہوتا ہے۔ ان کے قلوب میں شکر و امتنان کے جذبات کا سیلاب اُمنڈ آتا ہے۔ نتیجتاً بندہ مؤمن نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیمِ خم کر دیتا ہے۔
انبیا علیہم السلام جس خطہ اور جس قوم میں مبعوث ہوئے، ان کی زبان و ادب پر انھیں عبور حاصل تھا۔ ان کے حالات اور سماج سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ تہذیب و اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ابلاغ کا فريضہ انجام دیتے تھے۔ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے منصب ِنبوت پر فائز کیا، انھیں یہ تمام صلاحیتیں عطا فرمائیں، پھر انھیں معلم و مربی کی حیثیت میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا منصب عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے معلم و مربی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دنیا بھر کے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قیادت و سیادت کا فريضہ صحیح طور پر وہی انجام دے سکتا ہے، جس کی اپنی زندگی، اپنا کردار اور اپنے اعمال بنی نوع انسان کے لیے مثالی نمونہ ہوں۔
مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور تقریرکے ذریعے جو دین ہم تک پہنچا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ اسی لیے دین کی تعلیمات، اس کے عطا کردہ احکام اور اصول و قواعد میں تقدس اور عظمت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یہی وہ عنصر ہے جو لوگوں کے دلوں میں دینی احکام کے لیے احترام کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور اہل ایمان کو احکام و قوانین پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی جذبہ معاشرے کو تہذیب و اخلاق کے دائرے میں رکھنے اور عملی زندگی میں احکام و قوانین پر آمادۂ عمل کرنے میں ایک قوی محرک کے طور پر کام کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا بھر کے انسانوں کے لیے محض نظری یا تصوراتی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سراسر عملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو پیغام دیا ہے، سب سے پہلے اس پر خود عمل پیرا ہوکر عملی نمونہ بھی پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی پیش کی، یہاں تک کہ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی مثالی نمونہ کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش فرمائی:
فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُـرًا مِّنْ قَبْلِہٖ۰ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۱۶(یونس ۱۰: ۱۶) میں نے نبوت سے پہلے بھی تمھارے درمیان رہ کر زندگی گزاری ہے کیاتم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟
عقیدۂ آخرت کوئی فلسفیانہ تصور نہیں ہے، بلکہ فطرت اور عقلِ سلیم کے مطابق ہے۔ آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو کر اپنی دُنیوی زندگی کے اعمال کا حساب دینے کا یقین، دُنیوی زندگی سے متعلق انسان کا نقطۂ نظر مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ اس عقیدے کو تسلیم کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو پوری طرح ذمہ دار سمجھتا ہے، اور وہ دُنیوی زندگی سے متعلق فیصلے کرتے ہوئے آخرت کی دائمی زندگی کو نظر انداز نہیں کرتا۔
مومن کی زندگی میں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک، احساسِ شکر و امتنان، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا کے حصول کا شوق اور جنت کی نعمتوں اور پُرسکون زندگی کی کشش اسے اعمالِ صالحہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے اعمال کا محاسبہ، اللہ کی ناراضی کا ڈر اور عذابِ جہنم کی شدت انسان کو منکر، فحشا، فتنہ و فساد اور بغی و ظلم سے روکتی ہے۔
اس دُنیا میں انسان کا قیام عارضی ہے۔ انسانی تاریخ میں ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ ہر آنے والا انسان موت کا شکار ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ہر فرد ایک مختصر زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ دنیا کا نظام کچھ ایسا ہے کہ یہاں نہ تو انسان کو اس کے اچھے اعمال کی پوری پوری جزا مل سکتی ہے اور نہ بُرے اعمال کی پوری سزا مل سکتی ہے۔ باقی وقتی طور پر مکافاتِ عمل کے لیے کچھ قوانین جزا و سزا طے کر لیے جاتےہیں تاکہ دُنیوی معاشرہ میں امن و سلامتی کی صورت حال برقرار رکھی جاسکے۔ لیکن ان قوانین اور ضابطوں کے باوجود بھی ایسے جرائم وقوع پذیر ہوتے ہیں، جن کا ارتکاب کرنے والے قانون اور جرائم کو کنٹرول کرنے والے اداروں کی گرفت میں نہیں آپاتے، اور انھیں کوئی سزا نہیں ملتی۔ حقیقت یہی ہے کہ دُنیوی اعمال کی حقیقی پوری جزا و سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عدالت سے مل سکتی ہے۔ آخرت پر ایمان ہی انسان کو منکرات سے روک کر تعمیر و اصلاح اور معروف کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔
علم و ایمان کے ساتھ تیسرا بنیادی ستون اخلاق ِ حسنہ ہے۔ جس طرح اسلام میں علم اور ایمان و عقیدہ کو اہمیت حاصل ہے اسی طرح کریمانہ اخلاق کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خیر و شر، نیکی اور بدی کی پہچان رکھی، اچھے اور بُرے کے درمیان امتیاز کرنے کی حِس بھی رکھی ہے۔ یہ فطری صلاحیت بہت قدر و قیمت رکھتی ہے۔ انبیا علیہم السلام اپنی تعلیمات اور تربیت کے ذریعے اس حِس کو اس قدر طاقت ور کر دیتے ہیں کہ ان کا تربیت یافتہ انسان شر سے پوری کراہت کے ساتھ اجتناب کرتا ہے اور خیر کو صحیح جذبہ اور ذوق شوق کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت کا فريضہ تو اعلانِ نبوت کے بعد شروع فرمایا، لیکن اخلاقیات کی تعلیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نو عمری ہی سے دیتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی بالادستی کا سارا عرب معترف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظمت کا کبھی کسی دشمن نے بھی انکار نہیں کیا۔قرآن حکیم نے اس کی شہادت دی:
وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ۴ (القلم۶۸: ۴) اور آپ ؐیقیناً اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔
انبیا علیہم السلام انسانوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز اصلاحِ قلب اور تزکیۂ نفس سے کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں وہ ان امراض کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ان امراض میں نفاق، بغض، حسد، کینہ، حرص و لالچ، تعصب، نفرت و حقارت اور تکبر وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ایسے امراض ہیں جو انسان کے رویے، عادات و اطوار اور کردار کو بُری طرح بگاڑ دیتے ہیں۔ معاشرے کے یہی بگڑے ہوئے لوگ سارے معاشرے اور معاشرتی اداروں میں آلودگی اور فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں انبیاء علیہم السلام انسانی قلوب کو رذائل سے پاک صاف کرتےہیں، پھر فضائلِ اخلاق کی آبیاری کرتے ہیں، جن میں خاص طور پر اخلاص، صدق و امانت، تقویٰ، صبر و شکر، توکّل، ایثار و تواضع، رحم دلی وغیرہ جیسی اعلیٰ صفات کی جڑیں انسانی دماغ اور رویوں میں نہایت مضبوطی کے ساتھ پیدا کرتے ہیں۔
ان میں سے بعض اخلاقی فضائل بڑی جامعیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اخلاص کی صفت اخلاقیات میں سر فہرست ہے۔ یہ ایسی جامع صفت ہے جو صدق و امانت کے وسیع مفہوم کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ قلب ِمومن جب اخلاص کی صفت سے متصف ہوتا ہے تو اس کے ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا ہوتی ہے۔
اسلامی ادب میں تقویٰ بھی ایک جامع صفت ہے۔ قرآن حکیم میں تقویٰ کا لفظ مختلف صیغوں کے ساتھ بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اہل ایمان کے تمام اعمال، اخلاق، کردار اور رویوں کا محور تقویٰ ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو قلب و دماغ میں معروف اور خیر کے امور کو پرکھنے اور سمجھنے کا شعور پیدا کرتی ہے۔ تقویٰ کی صفت اہل ایمان میں تعمیر اور تخلیقی صلاحیتوں کو اُجاگر کرتی ہے، جن کا مظاہرہ وہ میدانِ عمل، تعلیم و تربیت، نظمِ مملکت و حکومت، خاندانی نظم، معیشت و معاشرت اور علوم و فنون کی ترویج میں کرتے ہیں:
يٰٓاَيُّھَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللہَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا (الانفال۸: ۲۹) اے ایمان والو! اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمھیں وہ کسوٹی عطا فرمائیں گے جس کی بنیاد پر تم حق و باطل کے درمیان فرق کر سکو گے۔
تقویٰ کی صفت انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نکال کر کامیابی اور سکون و خوش حالی کی شاہراہ پر رواں کرتی ہے:
وَمَنْ يَّـتَّقِ اللہَ يَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا۲ۙ وَّيَرْزُقْہُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۰ۭ (الطلاق۶۵: ۲، ۳) جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات سے نجات کی راہیں پیدا کر دیتے ہیں، اور ان پر رزق کے ایسے در کھول دیتے ہیں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔
وَمَنْ يَّتَّقِ اللہَ يَجْعَلْ لَّہٗ مِنْ اَمْرِہٖ يُسْرًا۴ (الطلاق۶۵: ۴) جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں سہولت پیدا کر دیتے ہیں۔
وَمَنْ يُّطِعِ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ وَيَخْشَ اللہَ وَيَتَّقْہِ فَاُولٰۗىِٕكَ ہُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ۵۲ (النور۲۴: ۵۲) جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔
ہمارے معاشرے میں عام طو رپر خطبا اور علما تقویٰ کی تشریح و تعبیر ذکر و اذکار، تسبیح و تہلیل، اعتکاف و تنہائی پسندی اور صوم و صلوٰۃ میں انہماک سے کرتے ہیں۔ یقیناً یہ سب چیزیں انسان کی تربیت اور تعلق مع اللہ کے لیے مفید ہیں۔ لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام امور کے ساتھ تقویٰ کی واضح جھلک خاندانی معاملات، تجارت، معاشرتی اُمور، ملکی نظم و نسق اور بین الاقوامی امور حل کرتے ہوئے بھی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ خلفائے راشدینؓ اور صحابہ کرامؓ کے حالات کا مطالعہ کیجیے تو وہاں بھی تقویٰ لوگوں کی تخلیقی اور تعمیری و رفاہی کاموں میں انہماک پیدا کرنے والی صفت کے طور پر نظر آتا ہے۔ گویا تقویٰ معاشرہ میں خیر خواہی کے جذبہ کے ساتھ فلاح و بہبود کے کاموں میں متحرک رکھنے والی طاقت و صفت ہے، جو ذکر و اذکار، تسبیح و تلاوت کے ساتھ لوگوں کے باہمی معاملات، نظمِ معیشت اور سیاست و حکومت میں بھی مؤثر ذریعہ ہے۔
مذکورہ تینوں عناصر اسلامی معاشرہ کے قیام و استحکام کے لیے بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی اعلیٰ تہذیب وجود میں نہیں آسکتی۔ جب تک معاشرے میں کوئی ایسی تہذیب وجود میں نہیں آتی، جو علم، ایمان اور اعلیٰ اقدار و روایات پر قائم نہ ہو ملک اور معاشرے میں آئین و دستور اور قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوسکتی، نہ کوئی مستحکم معاشرہ تکمیل پاسکتا ہے۔
اس ملک پر حکمرانی کرنے والوں نے ہمیشہ مذکورہ تینوں عناصر کو بری طرح نظر انداز کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے تقریباً سبھی ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ رشوت، چور بازاری، دھوکا بازی اور بےراہ روی کا دور دورہ ہے۔ ہر ادارہ اور ہر شعبہ بدعنوانی کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔
اس اہم کام کے لیے حکومت کا کردار اپنی جگہ لیکن یہ کام اپنی سطح پر کرنا ہوگا۔ اگر دینی مدارس اور مساجد کے ذمہ داران اجتماعی طور پر ایک منظم تحریک کی صورت میں کام کریں تو یقیناً اس کے مثبت اثرات جلد ظاہر ہونے لگیں گے۔
تعلیم اور تربیتِ اخلاق کا کام ملک کے سارے لوگوں کے لیے بہت منظم تحریک کی صورت میں انجام دیا جاسکتا ہے۔ سرکاری نظم میں چلنے والے تعلیمی ادارے تو تقریباً ناکامی کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ نجی شعبہ میں اکثر کے پیش نظر محض دولت کمانا یا کچھ تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، لیکن مجموعی طور پر تربیت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔
ملک کے خیر خواہ اور صاحبِ استطاعت لوگوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے اور اعلیٰ معیار کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینا ہوگی، اور ملک کے ہر شہری کو حصولِ علم اور تربیتِ اخلاق کی سہولت مہیا کرنا ہوگی، البتہ مسلمان طلبہ کے لیے ایمان و عقیدہ اور فہم دین کی تعلیم کا خصوصی انتظام ہرصورت میں کرنا ہوگا۔ ملک میں بہت سے رفاہی کام کرنے والے ادارے، مثلاً یتیم خانے، ہسپتال، غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے بعض ادارے بھی اس تحریک میں شامل ہو کر اسے مزید مؤثر بنا سکتے ہیں۔
حُسن معاشرت، تمدن کی روح ہے۔ اس کا دارومدار معاشرے میں قائم ایک اعلیٰ تہذیب پر منحصرہے۔ انسانی معاشرے میں وہی تہذیب پائیدار ہوتی ہے، جو علمِ نافع، ایمانِ راسخ اور اخلاقِ کریمہ کی بنیادوں پر قائم ہو۔ محض آئین اور قانون کی بنیاد پر نہ کوئی تہذیب قائم ہوتی ہے، نہ تمدن آگے بڑھتا ہے، البتہ اگر مذکورہ اصولوں کی بنیاد پر کوئی تہذیب وجود پا چکی ہو اور ملک و معاشرہ میں تمدن ارتقائی مراحل طے کرنے لگا ہو، تو ایسے معاشرے میں دستور اور قانون بھی مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آئین و قانون کی پشت پر علم و ایمان اور اخلاق کی قوت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ قوت معاشرے کے افراد کے رگ و پے میں رچی بسی ہوتی ہے۔
اگر ہم مذکورہ تین عناصر کو معاشرے میں متعارف کرا سکیں اور ایک اسلامی تہذیب کی بنیاد ڈال دیں، تو پھر تمام مسائل کا حل بھی نکل آئے گا اور ترقی کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ ان شاء اللہ، وھو المستعان۔