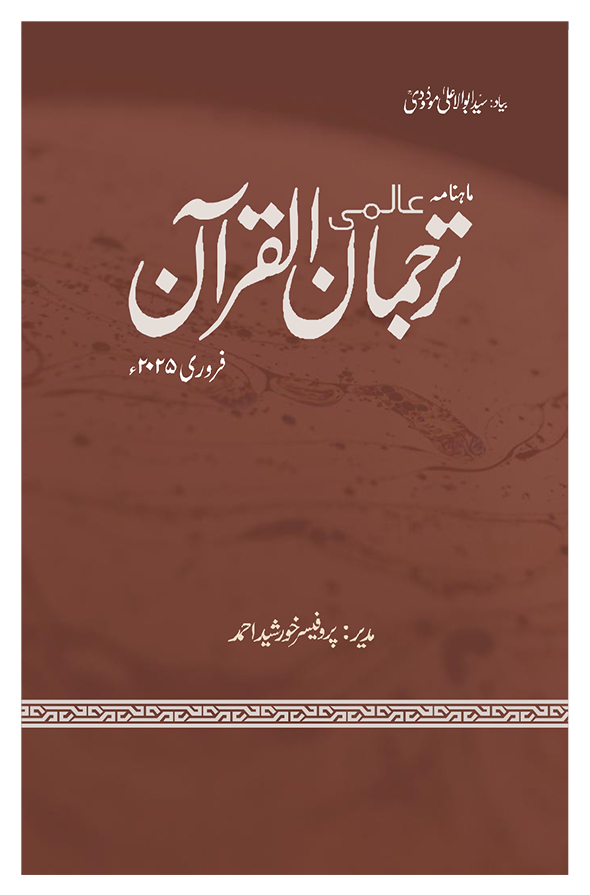
دین اسلام کا تیسرا بنیادی ستون زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر ایمان کے بعد صرف دو اعمالِ صالحہ کا تذکرہ آیاہے: ایک نماز کا،دوسرا زکوٰۃ کا۔ یعنی جب ایک معیاری مومن کا تصور سامنے لانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوۃَ لَھُمْ اَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّـہِمْ۰ۚ (البقرہ ۲:۲۷۷)بلاشبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنھوں نے صالح اعمال کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کے ربّ کے پاس اجر ہوگا۔
حالانکہ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ایسے بہت سے اچھے اعمال و اخلاق ہیں جن کا اہتمام معیاری مومن و مسلم بننے کے لیے ضروری ہے۔ پھر قرآن حکیم ایسا اندازِ بیان کیوں اختیار فرماتا ہے؟ اور معیاری مومن و مسلم کا تصور دلانے کے لیے اکثر ایمان کے بعد صرف نماز اور زکوٰۃ ہی کا نام لے کر خاموش کیوں ہوجاتا ہے؟ دوسری نیکیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟
ظاہرہے کہ گفتگو کا یہ انداز اس نے بلاوجہ تو اختیار نہیں کیا ہے۔ غور کیجیے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہ مل سکے گی کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نماز اور زکوٰۃ یہی دو چیزیں دین کی اصل عملی بنیادیں ہیں۔ جس نے ان دونوں فرائض کو اچھی طرح ادا کرلیا، اس نے گویا پورے دین پر عمل کرنے کی پکی ضمانت اور عملی شہادت فراہم کردی اور اب اس سے اس بات کا کوئی واقعی اندیشہ باقی نہیں رہا کہ دوسرے احکامِ شریعت سے بے نیازی کا برتائو کرے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس بات کا جواب آپ کو ایک طرف دین کی اور دوسری طرف نماز وزکوٰۃ کی حقیقتوں اور غایتوں پر نظر ڈالتے ہی مل جائے گا۔ احکامِ دین کی اصولی تقسیم کیجیے تو ان کی دو ہی قسمیں ہوسکیں گی۔ ایک قسم ان احکام کی ہوگی جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے۔ دوسری قسم ان احکام کی ہوگی جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ اس طرح دین کی پیروی دراصل اس بات کا نام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق دونوں سے عہدہ برآ ہوجائے۔
نماز انسان کو اللہ اور آخرت کی طرف لے جاتی ہے تو زکوٰۃ اسے دُنیا کی طرف لڑھک جانے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ اگر کڑی چڑھائی کا راستہ ہے تو یہ دونوں چیزیں اس راستے پر سفر کرنے والے انسانی عمل کی گاڑی کے دو انجن ہیں۔ نماز کا انجن اسے آگے سے کھینچتا ہے اور زکوٰۃ کا انجن اسے پیچھے سے دھکیلتا ہے اور اس طرح یہ گاڑی اپنی منزل کی طرف برابر بڑھتی رہتی ہے۔ جب صورتِ واقعہ یہ ہے تو ان دونوں چیزوں (نماز اور زکوٰۃ) کو یہ حق لازماً پہنچنا چاہیے کہ انھیں دین کی اصل عملی بنیادیں قرار دیا جائے۔
آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ کلمۂ شہادت کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے محنت ہورہی ہے ۔ نماز کی اقامت اور اس کی ادائیگی کا اہتمام ہورہا ہے۔ نہ صرف فرائض بلکہ نوافل میں تہجد، چاشت اور صلوٰۃ التسبیح وغیرہ پر بھی زور دیا جارہا ہے۔ لیکن ایتائے زکوٰۃ جو دراصل ملّت کے فقراء و مساکین کا حق ہے ، اس کی طرف توجہ کم ہے۔ حالانکہ قرآنِ حکیم اور سنت ِ رسولؐ کی تعلیمات کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں نماز کے ساتھ ہمیشہ زکوٰۃ کا مکلف بھی بنایا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان گہرا ربط ہے اور ایک مسلمان کے اسلام کی تکمیل ہی ان دونوں سے ہوتی ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے دین کی ساری عمارت کو منہدم کردیا۔ اور زکوٰۃ اسلام کا پُل ہے جو اس پر سے گزر گیا، وہ نجات پاگیا اور جو اس سے اِدھر اُدھر ہوگیا وہ ہلاکت میں جاپڑا۔
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: مَنْ لَمْ یُؤَدِّ الزَّکٰوۃَ فَلَا صَلَاۃَ لَہٗ (مصنف ابن ابی شیبۃ) ’’جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی‘‘۔
چنانچہ قرآن کا صریح حکم ہے کہ کسی فرد کے اسلام لانے کو اسی وقت معتبر مانا جائے گا، جب وہ نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے:
فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوۃَ فَخَــلُّوْا سَـبِيْلَہُمْ۰ۭ (التوبہ ۹:۵) اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کرلیں، نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔
آگے چل کر پھر فرمایا:
فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوۃَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ۰ۭ (التوبہ ۹:۱۱) سو اگر یہ لوگ توبہ کرلیں، نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو اب وہ تمھارے دینی بھائی ہوں گے۔
کلام اللہ کی یہ صراحتیں بتاتی ہیں کہ کسی غیرمسلم کا مسلمان قرار پانا کلمۂ شہادت ادا کرنے کے بعد بھی دو باتوں پر موقوف ہے: ایک یہ کہ وہ نماز قائم کرے، دوسرے یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جب تک وہ ایسا نہیں کرتا اس کا مسلمان ہونا قابلِ تسلیم نہیں ہوسکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر سے تائب ہوکر دائرۂ اسلام میں آنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ایک ضروری علامت اور لازمی شرط ہے۔ اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:
اُمِرْتُ اَنْ اُقاتَلَ النَّاسَ حَتّٰی یَشْھَدُوا اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللہِ وَیُقِیْمُوا الصَّلَاۃَ وَیُؤْتُوْا الزَّکٰوۃَ فَاِذَا فَعَلُوْہُ عَصَمُوا مِنِّی دِمَائَھُمْ وَاَمْوَالَھُمْ وَحِسَابھُمْ عَلَی اللہ ِ (مسلم، کتاب الایمان) مجھے حکم دیا گیا کہ ان لوگوں (اہل عرب) سے جنگ کرتا رہوں، یہاں تک کہ وہ اللہ ہی کے معبود ہونے اور محمدؐ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دے دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تبھی مجھ سے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ پاسکیں گے اور اس کے بعد ان کا حساب لینا اللہ کا کام ہے۔
نہ صرف یہ کہ اسلام کے کسی منکر کا مسلمان ہونا ادائے زکوٰۃ کے بغیر معتبر نہ سمجھا جائے گا بلکہ جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں،وہ بھی اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کردیں تو اسلامی حکومت ان کے خلاف بھی تلوار اُٹھائے گی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے زمانۂ خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو آپؓ نے ان کے خلاف اعلانِ جنگ کردیا اور جب حضرت عمرؓ نے ان کے اس اقدام کے درست ہونے میں تردّد کا اظہار کیا تو آپؓ نے فرمایا:
واللہ لاُقاتِلَنَ من فرق بین الصلٰوۃ والزکٰوۃ (مسلم، کتاب الایمان) بخدا میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا ، جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں۔
دورِ نبویؐ میں زکوٰۃ کا نظام کیا تھا؟ اس پر غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے باقاعدہ ایک نظم قائم کیا جس کے چند اہم شعبے یہ تھے:
۱- عمال الصدقات یا عاملین صدقات: زکوٰۃ وصول کرنے والے افسران
۲- کاتبین صدقات: حساب کتاب کے انچارج
۳- خارصین: باغات میں پھلوں کی پیداوار کا تخمینہ لگانے والے
۴- عمال علی الحمٰی: مویشیوں کی چراگاہ سے محصول وصول کرنے والے
۱- عاملین صدقات: عاملین صدقات کے لیے آپؐ نے بڑے بڑے صحابہ کا انتخاب فرمایا جن میں امانت و دیانت، احساسِ ذمہ داری اور اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں ہوتی تھیں اور آپؐ نے انھیں مختلف قبیلوں کی طرف بھیجا، مثلاً حضرت عمرؓ کو مدینہ کے اطراف، حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ کو بنوکلب، حضرت عمرو بن عاصؓ کو قبیلہ فزارہ، حضرت عدی بن حاتمؓ کو قبیلہ طے اور حضرت ابوعبیدہ بن جراحؓ کو مزینہ اور کنانہ قبیلے کی طرف۔ یہ عاملین ان قبیلوں کے مزاج اور نفسیات سے بھی واقفیت رکھتے تھے اور ان کی مدد کے لیے مقامی عاملین بھی متعین تھے۔ ان عاملین صدقات کو ایک پروانۂ تقرر بھی ملتا تھا اور وصولی کرنے کے لیے ہدایات (Code of conduct) بھی۔ مثلاً زکوٰۃ میں عمدہ مال وصول نہ کریں، زکوٰۃ دینے والوں کے مقام پر جاکر وصول کریں اور وصول یابی کے بعد ان کے لیے دُعائے خیر کریں۔ مذکورہ قبیلے کو بھی ہدایت کی جاتی تھی کہ وصول کنندہ جب ان کے پاس آئے تو حُسنِ سلوک کریں تاکہ وہ خوشی سے واپس جائے۔ آپؐ نے یہ ارشاد فرمایا:
اَلْعَامِلُ عَلَی الصَّدَقَۃِ بِالْحَقِّ کَالْغَازِیْ فِیْ سَبِیْلِ اللہِ حَتّٰی یَرْجِعَ اِلٰی بَیْتِہٖ (ابوداؤد، کتاب الخراج) حق و انصاف کے ساتھ زکوٰۃ کا وصول کرنے والا اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے کے مانند ہے یہاں تک کہ وہ عامل اپنے گھر کو لوٹ جائے۔
اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا محاسبہ کرتے اور ان کی تنخواہ یا مشاہرہ مقرر فرماتے۔ امام بخاریؒ نے کتاب الزکوٰۃ میں ایک باب والعاملین علیھا میں محاسبۃ المصدقین مع الامام کا ذکر کیا ہے۔
۲- کاتبین صدقات: مالی نظام کے حساب کا باقاعدہ شعبہ دورِ نبویؐ میں موجود تھا۔ حضرت زبیر بن عوامؓ اسلامی ریاست کے صدقات کے کاتب تھے اور وہی سارا حساب کتاب رکھا کرتے تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں حضرت جہیم بن صلتؓ اور حضرت حذیفہ بن الیمانؓ صدقات کی آمدنی کے ذمہ دار تھے۔
۳- خارصین (پیداوار کا تخمینہ لگانے والے عاملین):عہدنبویؐ میں ایک عہدہ ’خارصین‘ یعنی افسران برائے تخمینۂ پیداوار کا تھا، جو اپنی خداداد صلاحیتوں کی بناپر کھجور وغیرہ کے باغوں کی پیداوار کا اندازہ لگاتے کہ باغ کی کُل پیداوار کتنے وسق ہوگی اور اس میں زکوٰۃ کی واجب مقدار کتنی ہوگی؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ماہر خراص تھے۔ غزوئہ تبوک کے سفر میں آپؐ نے ایک مسلمان خاتون کے باغ کی پیداوار کا تخمینہ لگایا تھا کہ اس کی پیداوار دس وسق ہوگی اور آپؐ کا تخمینہ بالکل درست ثابت ہوا (بخاری)۔صحابہ کرامؓ میں حضرت عبداللہ بن رواحہؓ ماہر خراص شمار کیے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انھیں ہرسال خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔
۴- عاملین علی الحِمٰی: دورِ نبویؐ میں مختلف قبیلوں سے مویشیوں کی زکوٰۃ کی وصول یابی کے لیے عاملین مقرر تھے، مثلاً حضرت ذرین بن ابی ذرؓ قبیلہ غفار کے لیے، حضرت ابورافعؓ ذوالجدر کے لیے، حضرت سعد بن ابووقاصؓ قریش اور زہرہ کے لیے، حضرت بلال بن حارثؓ مزینہ قبیلے کے لیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دورِ خلافت میں چند قبیلوں نے زکوٰۃ مدینہ کے مرکزی بیت المال میں بھیجنے سے انکار کیا تو آپؓ نے فرمایا: ’’اللہ کی قسم! اگر یہ لوگ مالِ زکوٰۃ میں سے ایک اُونٹ باندھنے کی رسّی یا بکری کا بچہ بھی روک لیں گے تو مَیں ان سے جنگ کروں گا۔ خدا کی قسم! میں ہر اُس شخص سے جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا‘‘۔ (الشوکانی، نیل الاوطار)
علامہ یوسف القرضاوی لکھتے ہیں: ’’حضرت ابوبکرؓ کا مانعینِ زکوٰۃ سے جنگ کرنا غالباً اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی حکومت و ریاست معاشرے کے کمزور افراد اور فقراء و مساکین کے حقوق انھیں دلانے کے لیے آمادئہ جنگ ہوئی، جب کہ تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ سماج کے طاقت ور طبقے کمزور طبقوں کو کھاتے رہے اور حکام و امراء نے کبھی غلاموں اور بے کسوں کی پشت پناہی نہیں کی بلکہ اکثر و بیش تر حکومت ِ وقت نے دولت مند طبقے کی حمایت کی‘‘۔ (فقہ الزکوٰۃ، ص ۱۱۵)
حضرت عمر فاروقؓ کے دورِ خلافت میں زکوٰۃ کی صورتِ حال کیا تھی؟ اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے یمن سے جب زکوٰۃ کا ایک تہائی حصہ بھیجا تو حضرت عمرؓ نے لینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا: میں نے تم کو ٹیکس یا جزیہ وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں کے تمام اغنیاء سے زکوٰۃ وصول کرکے ان ہی کے فقراء میں تقسیم کردو۔ حضرت معاذؓ نے کہا: یہاں زکوٰۃ لینے والے کسی شخص کو محروم کرکے میں نے آپ کے پاس یہ مال نہیں بھیجا ہے۔ پھر دوسرے سال حضرت معاذؓ نے نصف زکوٰۃ بھیج دی۔ اس موقع پر بھی دونوں طرف سے اسی طرح کی گفتگو ہوئی۔ پھر تیسرے سال حضرت معاذؓ نے کُل زکوٰۃ بھیجی۔حضرت عمرؓ نے اس موقع پر بھی یہی بات کہی جو اس سے پہلے کہہ چکے تھے۔ اس کے جواب میں حضرت معاذؓ نے کہا: ’’یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں‘‘۔ (ابوعبید ،کتاب الاموال)
حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور میں مصر کے گورنر نے انھیں لکھا کہ صدقہ وزکوٰۃ کی رقم لینے والا وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ مالِ زکوٰۃ کا اب کیا کریں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے جواب دیا: غلاموں کو خرید کر آزاد کرو، شاہراہوں پر مسافروں کے لیے آرام گاہیں تعمیر کرو اور ان نوجوان مردوں اور عورتوں کی مالی امداد کرو جن کا نکاح نہیں ہوا ہے۔
علامہ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ خلیفہ نے ایک شخص کا خصوصی طور پر تقرر کیا تھا، جو شہر کی گلیوں میں ہر روز یہ اعلان کرتا تھا: کہاں ہیں وہ لوگ جو مقروض ہیں اور قرض ادا نہیں کرسکتے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں ہیں محتاج و حاجت مند اور کہاں ہیں یتیم اور بے سہارا؟ یہ معاملہ چلتا رہا کہ سوسائٹی میں تمام لوگ مال دار ہوگئے اور غربت و افلاس کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ (ابوعبید، کتاب الاموال)
خلفائے راشدین کے بعد اُموی دور میں نظامِ خلافت بدل گیا اور حکام ظلم و تشدد پر اُتر آئے تو بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زکوٰۃ کیسے دی جائے اور انھیں زکوٰۃ کا امین کیسے بنایا جائے؟ لیکن صحابہ کرامؓ نے یہی فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ انھی کو دینی چاہیے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ خود اپنے طور پر خرچ کر ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ایک شخص نے پوچھا: اب زکوٰۃ کسے دیں؟ کہا: وقت کے حاکموں کو۔ اس نے کہا: وہ زکوٰۃ کا روپیہ اپنے کپڑوں اور عطروں پر صرف کرڈالتے ہیں۔ فرمایا: اگرچہ ایسا کرتے ہوں، مگر دو انھی کو،کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ بغیر نظام کے قائم نہیں رہ سکتا۔
واقعہ یہ ہے کہ صدرِ اوّل سے لے کر عہد ِ عباسیہ تک یہ نظام بلااستثناء قائم رہا، لیکن ساتویں صدی ہجری میں تاتاریوں کا سیلاب تمام اسلامی ممالک میں اُمنڈ آیا اور نظامِ خلافت معدوم ہوگیا، تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ فقہائے حنفیہ کے فتوے اسی دور میں یا اس کے بعد لکھے گئے۔ اس وقت پہلے پہل اس بات کی تخم ریزی ہوئی کہ زکوٰۃ کی رقم بطور خود خرچ کرڈالی جائے کیونکہ غیرمسلم حاکموں کو نہیں دی جاسکتی، مگر ساتھ ہی فقہاء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جن ملکوں میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہے اور حالت کا اعادہ فوراً ممکن نہیں، وہاں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کسی اہل مسلمان کو اپنا امیر مقرر کرلیں تاکہ اسلامی زندگی کا نظام قائم رہے، معدوم نہ ہوجائے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا مسلمانوں میں یہ غلط فہمی یقین کی صورت اختیار کرتی گئی کہ جن ملکوں میں اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں زکوٰۃ کا اجتماعی نظم اور بیت المال کا قیام ناممکن ہے۔
عام طور پر عوام اور خواص کا ایک بڑا طبقہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ فقراء کو یا اپنے مستحق رشتہ دار کو چند سو روپے، چند کلو اناج یا چند گز کپڑے دے دیئے جائیں۔ اس سے وہ چند دن یا زیادہ سے زیادہ چند مہینے اپنی ضروریات پوری کرلیتا ہے اور اس کے بعد وہ فاقہ کش اور تہی دست رہتا ہے اور ہمیشہ مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے ۔ کیا اس سے زکوٰۃ دینے کا مقصد پورا ہوجاتا ہے؟
ملت کے اندر بڑے پیمانے پر یہ بیداری اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی دینِ اسلام کی اہم ترین بنیادوں میں سے ایک ہے اور دورِ نبویؐ اور دورِ خلفائے راشدین میں کس طرح اجتماعی نظمِ زکوٰۃ جاری و ساری تھا۔ اس کے علاوہ خاص طور پر قرآن حکیم سورئہ توبہ کی آیات (آیت۶۰ اور ۱۰۳) کو اُجاگر کرنا چاہیے جن میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں اور زکوٰۃ کو وصول کرنے اور اس کی تقسیم کی ذمہ داری کس پر اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے؟
قرآن حکیم نےآٹھ قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے:
اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۗءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْہَا وَالْمُؤَلَّفَۃِ قُلُوْبُہُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللہِ وَابْنِ السَّبِيْلِ۰ۭ فَرِيْضَۃً مِّنَ اللہِ ۰ۭ وَاللہُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۶۰(التوبۃ ۹:۶۰) صدقات (یعنی زکوٰۃ) اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے فقراء کے لیے ، مساکین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ وصول و تقسیم پر مقرر ہیں اور ان کے لیے جن کی تالیف ِ قلب مقصود ہو اورگردن چھڑانے کے لیے اور قرض داروں کے لیے اور راہِ خدا اور مسافروں کے لیے۔ اللہ بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
زکوٰۃ کے جن آٹھ مصارف کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہیں:
۱-فقراء غریب
۲- مساکین:نادار
۳-عاملین:زکوٰۃ کو اکٹھا اور تقسیم کرنے والے
۴-تالیفِ قلب :جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے
۵-رقاب:غلاموں کو چھڑانے کے لیے
۶-غارمین:قرض دار
۷-فی سبیل اللہ:اللہ کی راہ میں
۸-ابن السبیل:مسافروں کے لیے
قرآنِ حکیم کا فرمان ہے:
خُذْ مِنْ اَمْوَالِہِمْ صَدَقَـۃً تُطَہِّرُھُمْ وَتُزَكِّيْہِمْ بِہَا (التوبۃ ۹:۱۰۳) اے نبیؐ ! تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انھیں پاک کرو اور (نیکی کی راہ میں) انھیں بڑھائو۔
دراصل زکوٰۃصرف انفرادی طور پر صدقات اور خیرات کو تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے اور نہ اس کی تقسیم کو امیروں کی صوابدید پر چھوڑدیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک سماجی اور فلاحی ادارہ ہے جس کی نگرانی حکومت ِ وقت کرے گی اور اس کے انتظام و انصرام کے لیے ایک عوامی ادارہ حکومت کے تحت وجود میں آئے گا۔ قرآن حکیم میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کن لوگوں پر اور کن مَدات پر خرچ کی جائے ، وہاں محکمۂ زکوٰۃ کے سرکاری کارندوں (وَالْعٰمِلِیْنَ عَلَیْھَا) کا ذکر بھی ایک مستقل حیثیت سے کیا گیا ہے۔
مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ’’ان کے مالوں میں سے صدقہ حاصل کرو اور انھیں پاک کرو اور ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو بڑھائو‘‘۔ اس میں خُذْ (حاصل کرو) کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ حیثیت سربراہِ مملکت کے ہے اور اس پر عمل خلیفۂ راشد حضرت ابوبکرؓ نے بہ حیثیت خلیفۂ رسولؐ کیا، اور اس پورے عمل کو جاری وساری رکھا۔ زکوٰۃ کی وصولی، عمال کا تقرر اور اس کی تقسیم کا پورا ڈھانچہ باقی اور برقرار رکھا۔ علما وفقہا نے تصریح کی ہے کہ خُذْ کا اطلاق اوّلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا اور آپؐ کے بعد ہراُس شخص پر ہے جو ملّت کا ذمہ دار ہے۔
چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے یمن روانہ فرمایا تو کہا: تُوخَذُ مِن اَغْنِیَائِھِمْ وَتُرَدُّ اِلٰی فُقَرَائِھِمْ (بخاری)’’زکوٰۃ ان کے دولت مندوں سے وصول کی جائے اور پھر ان کے فقرا اور محتاجوں میں لوٹائی جائے‘‘۔ اس طرح زکوٰۃ کے آٹھ حق داروں میں اوّلین مستحقین فقراء اور غرباء ہیں۔
آیئے زکوٰۃ کے مستحقین کی مختصر تفصیل ملاحظہ فرمائیں:
مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمیداللہ کے مطابق: فقر اء سے مراد غریب اور نادار مسلمان ہیں اور مسکین سے مراد غریب اور نادار غیرمسلم ہیں اور اس کے لیے انھوں نے امام ابویوسفؒ کی تالیف کتاب الخراج کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ حضرت عمرؓ اپنی خلافت کے زمانے میں زکوٰۃ کی آمدنی سے یہودیوں کی بھی مدد کرتے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ’’یہ اہل کتاب کے مساکین میں سے ہے، اس لیے زکوٰۃ سے اس کو رقم دی جائے‘‘۔
دیگر اصحابِ رسولؐ مثلاً زید بن ثابت، ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ کی رائے کا ذکر امام طبریؒ نے کیا ہے کہ زکوٰۃ غیرمسلموں کو دی جاسکتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فقراء سے مراد مسلمانوں کے فقراء اور مساکین سے مراد غیرمسلم رعیت کے فقیر ہوں گے۔
فقراء اور مساکین کے بعد ایک اہم مَد، عاملین زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ یہ اس بات کا بیّن ثبوت ہے کہ زکوٰۃ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی شکل میں اداکرنی چاہیے۔ نظامِ حکومت یا مسلم سوسائٹی کا عمل دخل اس میں ہونا چاہیے۔ اس کام کے لیے ایک الگ اور متحرک شعبہ یا ایک ادارہ عوامی سطح پر مختص ہونا ضروری ہے۔ عاملین زکوٰۃ میں نہ صرف زکوٰۃ وصول کرنے والے آتے ہیں بلکہ ایک پورا انتظامی شعبہ اور اس کے کارندے مراد ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے، اس کا حساب کتاب کرنے، مستحقین کے اعداد و شمار جمع کرنے، اس کو تقسیم کرنے اور اس پورے کام کے انتظام و انصرام کے عمل میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس کام میں خواتین سے بعض مخصوص کاموں میں مدد لی جاسکتی ہے، مثلاً بیوائوں اور معذوروں کی دیکھ بھال اور ان کی نگرانی وغیرہ۔
ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی حمایت کے لیے یا اسلام کی مخالفت سے روکنے کے لیے رقم دینے کی ضرورت پیش آئے۔ نیز ان میں وہ نومسلم بھی داخل ہیں جنھیں مطمئن کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی قوم کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آملنے کی وجہ سے بے روزگار یا تباہ حال ہوگیا ہو تو اس وقت اس کی مدد کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن اگر وہ مال دار ہو تب بھی اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے تاکہ اس کا دل اسلام پر جم جائے۔ بعض علما نے مؤلّفۃ القلوب پر تفصیل سے لکھا ہے، مثلاً ابویعلٰی الفرا حنبلی نے اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں جو امام ماوردی کے معاصر ہیں، اس کی چار قسمیں بیان کی ہیں:
پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کو رقم اس لیے دی جائے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے، جن کو رقم اس لیے دی جائے کہ وہ مسلمانوں کو مضرت پہنچانے سے باز رہیں۔ عام حالات میں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو رقم دے دی جائے، تو مثلاً جنگ کے زمانے میں وہ غیر جانب دار رہیں گے، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تیسری قسم، ان لوگوں کی ہے جن کو رقم اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے قبیلے کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ اسلام قبول کریں۔ اس فہرست کے بعد وہ ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں کہ یہ رقم مسلمان اور غیرمسلم کسی کو بھی دی جاسکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کی تالیف ِ قلب کرنی ہو یا کسی کو، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے رقم دی جانی ہو، تو وہ غیرمسلم ہی ہوگا۔ لیکن وہ صراحت سے کہتے ہیں کہ چاہے وہ غیرمسلم ہو یا مسلم، اس کو مؤلّفۃ القلوب کے تحت زکوٰۃ کی آمدنی سے رقم دی جاسکتی ہے۔ (ڈاکٹر حمیداللہ کی بہترین تحریریں، ص ۲۰۲، مرتب: سیّد قاسم محمود)
عام طور پر ملک کے علما کا یہ خیال ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانے کے بعد اسلام کو غلبہ واستحکام حاصل ہوچکا ہے اس لیے مال کے ذریعے تالیف ِ قلب کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ لیکن وہ علما جو اس دعوتی کام میں سرگرم ہیں ان کا خیال ہے کہ اسلام آج حضرت عمرؓ کے دور کی طرح مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے اس مَد میں خرچ کے ذریعے نہ صرف نومسلموں کی اعانت اور مدد کرنی چاہیے بلکہ ان طبقات کو جو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت و مزاحمت میں پیش پیش ہیں، اس کے منفی رویہ و عمل میں کمی یا اس کے خاتمے کے لیے اور بعض افراد اور جماعتوں کو دینِ رحمت کی طرف راغب کرنے کے کاموں میں اس مَد کے ذریعے خرچ کرنے کی گنجائش باقی ہے اور یہ وقت کا اہم تقاضا بھی ہے۔
مصارفِ زکوٰۃ کا ایک حصہ گردنوں کو آزادکرنے میں صرف ہوگا یعنی اس حصہ سے غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرایا جائے گا لیکن آج اس قسم کے غلام اور باندی نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں فقہاء کا کہنا ہے کہ اگر اس کو عام مفہوم میں لیا جائے تو اس سے ان قیدیوں کو جو جیلوں میں جرمانہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید ہیں، ان کو رہا کرانے یا ان کے مقدموں کی پیروی کرکے انھیں آزاد کرانے کے کاموں میں خرچ کیا جاسکتا ہے۔
طبقات ابن سعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا ایک خط جو انھوں نے یمن کے گورنر کے نام لکھا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ جتنی رعایا دشمن کے ہاتھ قید ہو اس کو چھڑانے کے لیے سرکاری خزانے سے رقم خرچ کی جائے اس صراحت کے ساتھ کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا ذمی ہو۔ گویا رقاب کے سلسلے میں اسلامی رعیت کو دشمن کی قید سے رہائی دلانے کے لیے جو فدیہ دیا جاتا ہے اس میں بھی مسلم اور غیرمسلم کا امتیاز نہیں ہے۔ جس طرح فقراء اور مساکین کے سلسلے میں حضرت عمرؓ کی رائے میں زکوٰۃ کی رقم سے غیرمسلم کی مدد کی جاسکتی ہے۔
قرض دار جس پر اتنا قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس مقدارِ نصاب سے کم مال بچتا ہو، اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ البتہ فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی فضول خرچیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے قرض دار ہو، اس کو زکوٰۃ دینا مکروہ ہے۔ لیکن قرض دار کو زکوٰۃ سے حصہ دیا جائے تو ایک طرف تو قرض سے نجات کا ذریعہ بنے گا، دوسری طرف ان کو صاف ستھری باعزّت زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا۔حضرت عمرؓ کے زمانے میں غارمین سے ایک نئی چیز کا استنباط ہمیں ملتا ہے اور وہ سرکاری خزانے سے لوگوں کو امداد نہیں بلکہ قرض دینا ہے۔ اس طرح عہدفاروقی میں زکوٰۃ کی رقم سے بلاسودی قرض دینے کا ثبوت ملتا ہے۔
یہ ایک عام لفظ ہے جو تمام نیک کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن خاص طور پر اس سے مراد دینِ حق کا جھنڈا بلند کرنے کی جدوجہد میں مدد کرنا ہے۔ بعض فقہاء کا خیال ہے کہ فی سبیل اللہ کا لفظ مجاہدین کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جس سے خدا کی رضا مقصود ہو وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ ڈاکٹریوسف قرضاوی نے لکھا ہے کہ فی سبیل اللہ کے حصۂ زکوٰۃ کو دینی، تربیتی اور اشاعتی جہاد پر صرف کرنا زیادہ بہتر ہے بشرطیکہ یہ جدوجہد خالصتاً اسلام کے لیے ہو، مثلاً: دعوتی مراکز قائم کرنا، صلاحیت کے حامل مخلص افراد کی صلاحیتوں کومزید ترقی دینا (Human Resources Development) وغیرہ۔
اگرچہ مسافر کے پاس اس کے وطن میں کتنا ہی مال ہو، لیکن حالت ِ سفر میں اگر وہ محتاج ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ بعض علما کا خیال ہے کہ ابن السبیل کی تعریف کے تحت آج کل کے مہاجرین بھی آجاتے ہیں جو جنگ، غارت گری اور ظلم و جَور کے باعث بے گھر ہوجاتے ہیں۔ جو کچھ مال و دولت ان کے پاس تھا وہ وہیںرہ جاتا ہے اور اب ان کے لیے اس سے استفادہ ممکن نہیں رہ جاتا۔
مصارفِ زکوٰۃ کی آٹھ مدات کی تفصیلات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام نظامِ زکوٰۃ کےذریعے ایک Sharing & Caring (باہمی ہمدردی اور ایک دوسرے سے تعاون) سوسائٹی کا قیام چاہتا ہے جہاں پر ہرشخص کی بنیادی ضرورتیں:غذا، لباس، رہائش، حفظانِ صحت، اس کے لیے گھریلو سازوسامان اور سواری کی سہولتیں کم از کم مہیا ہوں اور ایک معتدل اور متوازن زندگی گزار سکے جو اِکرامِ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح معاشرہ کے تمام افراد میں دولت گردش کرتی رہے اور صرف امیروں کے درمیان گھومتی نہ رہے۔ عام طور پر مسلم سماج میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ستون ہے جس کے ذریعے سے نادار اور غریب زکوٰۃ کی رقم حاصل کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی اہمیت دین میں اس لیے بھی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سماج کے ضرورت مند طبقے کو خوش حال طبقہ بناتا ہے اور انھیں لینے کی پوزیشن سے نکال کر دینے کی پوزیشن میں لاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والوں کا طبقہ اسی وقت پیدا ہوگا جب سوسائٹی کا ہرفرد مضبوط اور مالی طور پر مستحکم ہوگا اورمعاشرے کے کمزور اور کچلے ہوئے طبقے دینے والے بنیں گے۔
اجتماعی نظام زکوٰۃ کے ذریعے ایک ایسے سماج اور سوسائٹی کے قیام کی کوشش ہوتی ہے، جس کے تمام افراد بالخصوص ایک بڑا طبقہ معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور کمزور اور بے سہارا افراد کو ان کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ؒ کے دور میں جب یہ نظامِ رحمت قائم تھا تو زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے لیکن سوسائٹی میں زکوٰۃ لینے والے موجود نہیں تھے۔
زکوٰۃ کی رقم زیادہ تر غریب عوام کی فوری ضرورتوں کی تکمیل میں استعمال ہوتی ہے لیکن اگرچھوٹے صنعت کاروں اور تاجروں کو چھوٹے پیمانے پر بنیادی سرمایہ (Seed money) فراہم کرکے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ دیاجائے تو اس سے غربت بتدریج ختم ہوسکتی ہے اور مستحقینِ زکوٰۃ چند برسوں میں زکوٰۃ دینے والے بن سکتے ہیں۔ دُنیا کے مختلف ملکوں میں مائیکروفنانس کے ذریعے ایسے کامیاب تجربے کیے جارہے ہیں۔ ملک عزیز میں بھی اس قسم کے اداروں کے ذریعے چھوٹے تاجروں اور ہنرمندوں کی امداد کی جاسکتی ہے۔
بہت سے علما کا موقف یہ ہے کہ اموالِ زکوٰۃ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے:
الف: اموالِ ظاہرہ: غلّہ، مویشی وغیرہ ، جنھیں آسانی کے ساتھ معلوم اور متعین کیا جاسکتا ہے۔
ب: اموالِ باطنہ: سونا، چاندی اور تجارتی سامان وغیرہ
اموالِ ظاہرہ کو حکومت یا سماجی ادارہ حاصل کرکے اجتماعی طور پر تقسیم کرسکتا ہے لیکن اموالِ باطنہ کو اس کے مالک کی صوابدید پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ خود اس کی تقسیم زکوٰۃ کی مدات میں کرے، اس لیے کہ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنیؓ نے اپنے دورِ خلافت میں ایسا ہی کیا تھا۔
اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت راشدہ ؓ کے زمانے میں چند قبیلوں کو جو رخصت دی گئی تھی کہ وہ خود غریبوں میں اپنی زکوٰۃ تقسیم کریں ، وہ اَزخود نہیں تھی، بلکہ حکومت نے اس کی اجازت دی تھی۔ یہ صورت بھی دراصل حکومت ہی کے ذریعے زکوٰۃ کی جمع و تقسیم کا ایک خاص انتظام تھا، جو مصلحتوں اور سہولتوں کی خاطر اختیار کرلیا گیا تھا۔
ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ حضرت عثمانؓ کے دور میں حضور اکرمؐ کی وفات کے صرف پندرہ سال بعد اُمت تین براعظموں: یورپ، افریقہ اور ایشیا میں پھیل گئی تھی اور کہیں کہیں ایک سو مربع میل میں ایک سے زائد مسلمان نہیں تھا۔اس وجہ سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ہرمسلمان کے مکان پر کارندوں کو بھیجنا اور حساب مانگنا مشکل تھا، اور اس کے لیے ایک کثیر عملے کی ضرورت پیش آتی تھی جس میں مصارف زیادہ اور آمدنی کم ہوسکتی تھی۔ اس لیے اس طرح کی آبادی کے صاحب ِ نصاب مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ وہ ہرسال زکوٰۃ کی رقم خود ہی احکامِ قرآنی کے مطابق نکال کر تقسیم کردیا کریں۔
بہرحال علمائے کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے حالات کے تناظر میں فیصلہ کریں کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام کیا ہو اور اموالِ باطنہ کو انفرادی طور پر اور ظاہرہ کو اجتماعی طور پر جمع کرکے تقسیم کرنے کا نظم کریں۔
ڈاکٹر یوسف القرضاوی فرماتے ہیں: ’’زکوٰۃ حکام کو دیتے وقت ایک تہائی یا ایک چوتھائی اپنے پاس روک لے، تاکہ اس کو اپنی جان پہچان، اڑوس پڑوس اور غریب رشتہ داروں میں تقسیم کرسکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک چوتھائی یا ایک تہائی زکوٰۃ دینے والوں کے ہاتھ میں رہنے دیں تاکہ وہ خود تقسیم کرسکیں‘‘۔ (فقہ الزکوٰۃ، ج۲)
دورِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کے قیام کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے مخلص اور باصلاحیت افراد جن میں سماجی خدمت کا جذبہ ہو اور جن کی قابلیت پر اعتماد کیا جاسکتا ہو، وہ ہرچھوٹے بڑے شہر میں ایک اجتماعی شکل اختیار کریں اور زکوٰۃ کا ایک اجتماعی نظم قائم کرنے کی سعی و جہد کریں اور اس کے لیے ایک مہم چلائیں۔ آج سے چند سال پہلے مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ نے میوات سے کلمہ اور نماز کے لیے ایک مخلصانہ مہم چلائی تھی جس کی وجہ سے نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دُنیا میں کلمہ پر محنت اور نماز کے قیام اور مسجدوں کے آباد کرنے کی کوشش شروع ہوئی۔ اسی طرح معاشرے کے ہرطبقہ میں اجتماعی نظمِ زکوٰۃ کی ہمہ گیر مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ ان شاء اللہ چندبرسوں میں اس کے مفید اور مؤثر نتائج سامنے آئیں گے اور اس طرح اقامت ِالصلوٰۃ اور ایتاء الزکوٰۃ سے ایک متوازن اور متمول اسلامی معاشرہ ملک میں وجود میں آئے گا جو اپنی مثال آپ ہوگا اور خیراُمت کی حیثیت سے یہ دوسرے معاشروں کے لیے بھی دعوتِ دین کا باعث ہوگا۔