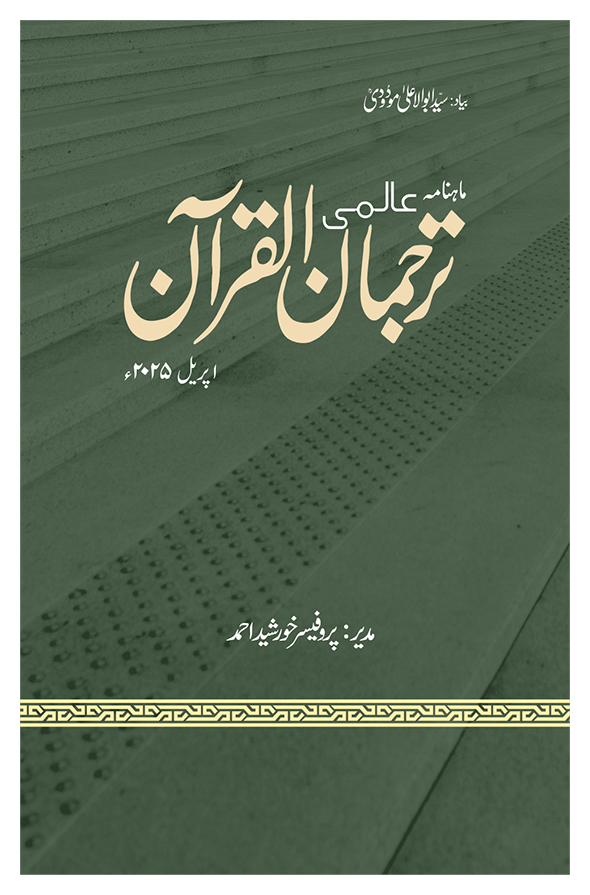
ایک فرد کی وہی زندگی بابرکت ہے جس میں اس بات کا جائزہ لیا جاتا رہے کہ اس نے گزرے ہوئے اوقات اور شب و روز کیسے گزارے؟کیا غلطی اور کوتاہی ہوئی؟ کیا جرم ہوا اور گناہ سرزد ہوا؟ کسی کی حق تلفی تو نہیں کی گئی؟ پھر انفرادی زندگی سے بلند ہوکر اجتماعی زندگی میں معاشروں اور اجتماعیتوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی اجتماعیت کو متوازن اور خوب صورت بنانے، مثالی اور شان دار بنانے میں کسی کوتاہی کا شکار تو نہیں ہوئے؟
ایک فرد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی ذاتی، علمی اور تہذیبی ومعاشرتی شخصیت کی ترقی کا ایک جائزہ لے کر دیکھے کہ ایک سال قبل قرآن کریم کے فہم میں کہاں کھڑا تھا اور اس پہلو سے آج کہاں کھڑا ہے ؟ اور اس کی تعلیمات کے نفاذ کے مراحل میں کہاں کھڑا ہے ؟ اور اس دوران میں کتنے فی صد ترقی ہوئی یا وہ جہاں تھا وہیں کھڑا ہے؟ دوسرا اہم سوال اس کی فوری اخلاقی اور قانونی ذمہ داری کی ادائیگی کا ہے۔
ہر فرد اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے جس خاندان کی سربراہی یا خاندان میں ایک فرد کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا رکھی ہے، یعنی وہ کسی کا بیٹا یا بیٹی یا کسی کا شوہر یا بیوی ہے، کسی کا بھائی یا بہن ہے، کسی کا برادر نسبتی ہے ،چچا زاد اور خالہ زاد اور پھوپھی زاد بھائی یا بہن ہے، غرض خاندان میں اس کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کا کیا حق ادا کیا گیا؟اس نے ایک مرتبہ بھی یہ سوچا کہ اس کا کوئی چچا،ماموں ،تایا یا اس کا چچازاد بھائی ہے، اس کا اپنا حقیقی چھوٹا یا بڑا بھائی یا بہن،جس سے اس نے تین ماہ میں بھی ایک مرتبہ نہ ملاقات کی نہ اس کا حال پوچھا۔ حتیٰ کہ اپنے پاس رابطے کے مواقع کے باوجود کبھی رابطہ تک نہیں کیا۔کیا آیندہ بھی یہی صورتِ حال رہے گی یا اس کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی؟ رشتوں کا قائم رکھناایمان کا حصہ ہے اور قطع رحمی سخت ناپسندیدہ فعل ہے۔
کیا گزرے ہوئے عرصے کے دوران ایک کارکن نے اپنی تحریکی ذمہ داریوں کو جیسا کہ ان کا حق تھا ،ادا کیا؟ یا محض قانونی پابندی کی حد تک تو اجتماعات میں شرکت کی ،لیکن نہ وقت کی پابندی کی ،نہ ذہن کو حاضر رکھ کر کچھ سنا ، نہ اس پر تنقیدی نگاہ ڈال کر اپنی رائے کا اظہار کیا؟ خود آگے بڑھ کر کون سے دعوتی کام کیے ؟یا ہدایات کے مطابق صرف کسی اجتماعی سرگرمی میں شرکت کرنے کو سب کچھ سمجھ لیا؟غائب دماغی کے ساتھ درس میں شرکت کر لی یا جو درس سنا اس کے کوئی عملی اثرات زندگی کے معاملات میں نظر آئے؟ یا سنی اَن سنی کر کے محض سماجی دبائو کے تحت حاضری دے دی؟
اسی طرح ایک کارکن کی حیثیت سے یا ایک ذمہ دار کی حیثیت سے تحریکی مقاصد کے حصول کے لیے اپنی تنظیمی صلاحیت، مالی ایثار و قربانی ،وقت کی فراہمی، اپنے اہل خانہ اور اہل خاندان، پڑوسی اور مسجد میں آنے والے نمازیوں تک تحریکی دعوت اپنے عملی رویے یا زبانی طور پر پہنچائی؟ کیا اپنی تحریکی فکر کو بہتر بنانے کے لیے تحریک کے بنیادی لٹریچر میں سےکم از کم چھ کتب کا مطالعہ کیا یا سال بھر بغیر کسی فکری تجدید کے اپنے سابقہ مطالعے کے دھندلے نقوش ہی کو کافی جانا؟ اس عرصے میں اپنی قریبی مسجد میں کتنی نمازیں باجماعت اس طرح ادا کیں کہ اقامت سے پہلے مسجد میں موجود ہو اور نماز کے بعد نمازیوں سے سلام اور مصافحہ کیا ہو؟ کیا یہ کوشش بھی کی کہ قریبی مسجد میں امام کے اعتماد کے ساتھ نماز کے بعد درسِ قرآن یا درسِ حدیث یا کوئی بھلی بات لوگوں تک پہنچائی ہو؟
اس بات کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کسی موقعے پر جب کوئی ذمہ داری سامنے آئی تو کیا اس کی خواہش دل میں پیدا ہوئی اور اسے قبول کرنے میں خوشی محسوس کی؟ حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ جس نے کسی عہدےکی طلب کی تو ہم اسے وہ عہدہ نہیں دیں گے ۔جب مجبور کیے جانے پر کسی ذمہ داری کو قبول کیا تو پھر کیا اس کا حق اپنا وقت، مال، صلاحیت لگا کر ادا کیا ؟اس دوران کتنے مواقع پر تحریکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی اور اپنے مالی اور سیاسی معاملات میں حق اور عدل کا مظاہرہ کیا؟ کیا ظلم کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی اور اختلافات سے قطع نظر حق گوئی کا موقف اختیار کیا؟ معاشرتی فلاح ،عدل کے کن کاموں میں پہل کی اور غیر تحریکی افراد کو ساتھ ملا کر حصولِ مقصد کی جدوجہد کی؟ معاشرے کی بے اعتدالیوں کے خلاف کیا اقدامات کیے؟ مسلمان اور غیر مسلم مستحقین کی فلاح کے لیے کن کاموں میں حصہ لیا؟ خود اپنے گھر میں ملازمین کے ساتھ یا کاروبار میں ملازمین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ اپنے معیار زندگی کو کم کر کے یا بڑھانے میں کتنا وقت اور مال صرف کیا ؟اپنےا عزا اوردوستوں کو کتنی مرتبہ مدعو کیا یا ان سے جا کر ملاقات کی؟
یہ وہ بنیادی کام ہیں جن کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ ہر آگے بڑھنے والا قدم زیادہ بھلائی کا ہونا چاہیے اور جب تک ماضی کے اقدامات کا تنقیدی جائزہ نہ لیا گیا ہو ،آگے قدم بڑھانے سے کوئی مفید نتائج نہیں نکل سکتے۔
ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے سال کے آغاز کا اوّلین اہم پہلو بظاہر موروثی تصورِ تاریخ کی جگہ اخلاقی تصورِ تاریخ کی ترویج ہے ۔اقوام عالم عموماً اپنے سال کے آغاز کو اپنی کسی اہم شخصیت سے وابستہ کرنا مناسب خیال کرتی رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسٰی علیہ السلام کی مناسبت سے عیسوی سال کو نہ صرف عیسائیت کے ماننے والوں نے بلکہ جہاں کہیں بھی یورپی سامراج کے قدم پہنچے، ان اقوام کو ان کی تاریخ سے کاٹ کر عیسوی سال ان پر مسلط کر دیا گیا۔ عالمی تجارتی منڈی ہو یا بین الاقوامی ادارے، سب جگہ عیسوی سال کو رواج دیا گیا۔
اسلام کے تصورِ تاریخ اور اسلامی نظم مملکت ، اسلامی معاشرہ ،اسلامی معیشت و اخلاق اور اسلامی قانون کی انفرادیت کے پیشِ نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرتِ مدینہ کو سنگ میل قرار دے کر تاریخ کے نظریاتی اور اخلاقی تصور کو متعارف کرایا گیا۔ اسی طرح نظامِ عدل کے قیام کو تاریخ کا سنگ میل قرار دے کر اس اہم انقلابی تاریخ ساز موقع سے تاریخ کو شمار کرنے اور تمام جاہلی دور کو جس کی بنیاد نسل پرستی ، مادہ پرستی ، شرک پرستی پر تھی، ایک طرف رکھتے ہوئے تاریخ انسانی کے نئے انقلابی دور سے سنہ ہجری کا آغاز کیا گیا۔
اگر غور کیا جائے تو ہجرت بطور ایک دعوتِ عمل اپنا اہم مقام رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ہجرت اس بات کی علامت تھی کہ تیرہ سال تک شب و روز کی مسلسل جدوجہد اور ہر قسم کی تکلیف، تعذیب اور تضحیک کے باوجود مسلسل دعوتی عمل میں مصروف رہنے کے بعد جب مالکِ کائنات خود یہ حکم دے کہ اب اس محاذ کی جگہ دوسرے محاذ پر اپنی قوت صرف کرو تو بغیر کسی تاخیر کے اللہ کے حکم کی پیروی کی جائے ۔ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اپنی جائے پیدائش، جوانی گزارنے کی جگہ، خاندانی وابستگیوں، دعوتی یادوں سب کو خیرباد کہہ کر صرف اللہ کی رضا اور اجازت سے اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک نئی جگہ کو دعوت کا مرکز بنا کر کام کو جاری رکھا جائے۔
یہ محض مکہ کو چھوڑنا نہیں تھا بلکہ مکہ میں دی جانے والی دعوتِ توحید کے دائرے کو وسیع کرنا تھا۔یہ ابتلاوآزمائش سے بچنا نہیں تھا بلکہ اس سے زیادہ کٹھن ایک نئی روایتِ عدل، معاشرتی فلاح، سیاسی حاکمیت اور اخلاقی اور قانونی فضا کا قیام تھا۔ یثرب جو صدیوں سے یہودی روایات کا احترام کرتا آیا تھا اسے مدینۃ الاسلام میں تبدیل کرنے کا تاریخ ساز کام تھا۔یہ کام اس مسلسل جہاد سے کم نہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ مکہ میں تیرہ سال تک مصروف رہے تھے۔ یہ توحید کی دعوت اور اخلاقی طرزِ حیات کو عملی شکل میں قائم کرنے کا عظیم کارنامہ تھا۔ نظامِ شرک کی جگہ نظامِ توحید کا نفاذ اس بات کا متقاضی تھا کہ اس واقعے کو تاریخ کا آغاز قرار دیا جائے۔
بعد میں آنے والے ادوار اور اشخاص کے لیے اس عظیم ہجرت الی الحق اورا سلام پر عمل کرنے کا آسان طریقہ حدیث نبوی کی شکل میں سمجھا دیا گیا کہ اگر ایک شخص ہجرت جسمانی ہو یا ذہنی، اس غرض سے کرتا ہے کہ وہ نئے مقام پر زیادہ مالی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، یا اپنے ذاتی اختیارات میں اضافہ کر سکتا ہے، تو یہ ہجرت صرف انھی مقاصد کے لیے ہے۔ لیکن اگر وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر عمل اور اسے قائم کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو یہ ہجرت اقامت دین کے لیے ہے ۔حدیث صحیح کے اس مفہوم کی روشنی میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیش نظر ہجرت کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟
کیا ہجرت اپنی ذات کی ترقی، کسی برتر عہدہ کے حصول یا مالی فائدہ کے لیے ہے، یا ہماری منصوبہ بندی میں اولین اہمیت دعوت الی القرآن ،دعوت الی السنہ، دعوت الی الحق، دعوت الی الخیر کی ہے؟ کیا ذاتی جائزہ کے بعد ماضی کے مقابلے میں دینی فہم میں مزید اضافہ ہوا؟ اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے کوئی نئی اور مؤثر حکمت عملی تیار کی ؟ کیا اپنے نفس کے بہکاووں پر قابو پانے اور نفس مطمئنہ کے حصول کے لیے کوئی تربیتی نظام بنایا ہے؟ کیا تحریکی مقصد یعنی اقامت ِدین کی جدوجہد کے لیے کوئی سوچا سمجھا عملی منصوبہ تیار کیا ہے؟ کیا دیگر تحریکات کے تجربات کی روشنی میں کوئی نئی حکمت عملی تیار کی ہے یا ماضی کے آزمائے ہوئے طریقوں کو کافی سمجھ لیا ہے؟ کیا قیادت اور کارکن دونوں کی تربیت اور تحریکی فکر میں اضافے کا کوئی منصوبہ بنایا ؟
اگر اس شعور اور فکر کے ساتھ ان منصوبوں کے مطابق وسائل اور جدید وسائل کا استعمال کرنا پیش نظر ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ تجدید عہد کرتے ہوئے اقامت دین کی جدوجہد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عزم بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہٗ و تعالیٰ انسان کی نیت اور نیت کی تصدیق کرنے والے عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی مغفرت کسی پیمانے سے نہیں ناپی جا سکتی۔ وہ لامحدود ہے اور اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اپنے بندوں کے ہرنیک عمل پر انھیں بڑھ چڑھ کر اجر دے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے جائزہ، تجزیہ اور ارادہ کو مستحکم اور اللہ کے توکل کے ساتھ اپنی تمام قوت کو اس منصوبۂ عمل پر لگا دیا جائے ۔اللہ کی نصرت اور تائید ان تمام ارادوں کو کامیاب کرتی ہے جو خلوصِ نیت اور بے غرض ہو کر کیے جائیں۔
یہ مضمون ٹائپ شدہ صورت میں پروفیسر خورشید احمد صاحب کے ذاتی کاغذات سے ہمیں ملا، مگر اس پر مضمون نگار کا نام درج نہیں تھا، البتہ ایک لفظ لکھا تھا ’مولانا محترم‘۔ راقم نے اندازے سے اس کو مولانا مودودیؒ سے منسوب کرکے دسمبر۲۰۱۶ء کے ترجمان میں شائع کیا۔ لیکن اب ماہ نامہ فاران ، کراچی (مدیر: ماہرالقادریؒ) کی ورق گردانی کر رہا تھا تو دیکھا کہ یہ تو مولانا امین احسن اصلاحیؒ کی تقریر تھی، جو انھوں نے ’بین الاقوامی سیرت کانفرنس‘، کراچی میں پڑھی تھی، اور پھر ماہ نامہ فاران (اپریل۱۹۵۹ء) میں شائع ہوئی تھی۔(س م خ)
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دُنیا کے لیے جو دین بھیجا، وہ جس طرح ہماری انفرادی زندگی کا دین ہے، اسی طرح ہماری اجتماعی زندگی کا بھی دین ہے۔ جس طرح وہ عبادت کے طریقے بتاتا ہے، اسی طرح وہ سیاست کے آئین بھی سکھاتا ہے، اور جتنا تعلق اس کا مسجد سے ہے، اتنا ہی تعلق اس کا حکومت سے بھی ہے۔
اس دین کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اور سکھایا بھی، اور ایک وسیع ملک کے اندر اس کو عملاً جاری و نافذ بھی کر دیا۔ اس وجہ سے آںحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح بحیثیت ایک مزکیِ نفوس اور ایک معلّمِ اخلاق کے ہمارے لیے اُسوہ اور نمونہ ہے، اسی طرح بحیثیت ایک ماہرِ سیاست اور ایک مدّبرِ کامل کے بھی اسوہ اور مثال ہے۔
آج کی اس صحبت میں، اس کانفرنس کے محترم داعیوں کے ارشاد کی تعمیل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسی پہلو سے متعلق چند باتیں مَیں عرض کرنا چاہتا ہوں:
اس امرِواقعی سے آپ میں سے ہرشخص واقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب قوم سیاسی اعتبار سے ایک نہایت پست حال قوم تھی۔ مشہور مؤرخ علّامہ ابن خلدون نے تو ان کو ان کے مزاج کے اعتبار سے بھی ایک بالکل غیرسیاسی قوم قرار دیا ہے۔ ممکن ہے ہم میں سے بعض لوگوں کو اس رائے سے پورا پورا اتفاق نہ ہو، تاہم اس حقیقت سے تو کوئی شخص بھی انکار نہیں کرسکتا کہ اہلِ عرب اسلام سے پہلے اپنی پوری تاریخ میں کبھی وحدت اور مرکزیت سے آشنا نہ ہوئے، بلکہ ہمیشہ ان پر نراج اور انارکی کا تسلّط رہا۔ پوری قوم جنگ جُو اور باہم نبردآزما قبائل کا ایک مجموعہ تھی، جس کی ساری قوت و صلاحیت خانہ جنگیوں اور آپس کی لُوٹ مار میں برباد ہوتی تھی۔ اتحاد، تنظیم، شعور، قومیت اور حکم و اطاعت وغیرہ جیسی چیزیں، جن پر اجتماعی اور سیاسی زندگی کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں، ان کے اندر یکسر مفقود تھیں۔
ایک خاص بدویانہ حالت پر صدیوں تک زندگی گزارتے گزارتے ان کا مزاج نراج پسندی کے لیے اتنا پختہ ہوچکا تھا کہ ان کے اندر وحدت و مرکزیت پیدا کرنا ایک امرِمحال بن چکا تھا۔ خود قرآن نے ان کو قَوْمًا لُّدًّا (مریم۱۹:۹۷) کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، جس کے معنی جھگڑالو قوم کے ہیں، اور ان کی وحدت و تنظیم کے بارے میں فرمایا کہ: لَوْاَنْفَقْتَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوْبِھِمْ (الانفال۸:۶۲) ’’اور اگر تم زمین میں جو کچھ ہے، سب خرچ کرڈالتے ہو تو بھی ان کے دلوں کو باہم نہ جوڑ سکتے ‘‘۔
لیکن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳برس کی قلیل مدت میں اپنی تعلیم و تبلیغ سے اس قوم کے مختلف عناصر کو اس طرح جوڑ دیا کہ یہ پوری قوم ایک بنیانِ مرصوص بن گئی۔ یہ صرف متحد اور منظم ہی نہیں ہوگئی، بلکہ اس کے اندر سے صدیوں کے پرورش پائے ہوئے اسباب نزاع و اختلاف بھی ایک ایک کر کے دُور ہوگئے۔ یہ صرف اپنے ظاہرہی میں متحد اور مربوط نہیں ہوگئی بلکہ اپنے باطنی عقائد و نظریات میں بھی بالکل ہم آہنگ اور ہم رنگ ہوگئی۔ یہ صرف خود ہی منظم نہیں ہوگئی بلکہ اس نے پوری انسانیت کو بھی اتحاد و تنظیم کا پیغام دیا۔ اور اس کے اندر حکم و اطاعت دونوں چیزوں کی ایسی اعلیٰ صلاحیتیں اُبھر آئیں کہ صرف استعارے کی زبان میں نہیں بلکہ واقعات کی زبان میں یہ قوم شتربانی کے مقام سے جہاں بانی کے مقام پر پہنچ گئی، اور اس نے بلااستثنا دُنیا کی ساری قوموں کو سیاست اور جہاں بانی کا درس دیا۔
اس تنظیم وتالیف کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک بالکل اصولی اور انسانی تنظیم تھی۔ اس کے پیدا کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو قومی، نسلی، لسانی اور جغرافیائی تعصبات سے کوئی فائدہ اُٹھایا، نہ قومی حوصلوں کی انگیخت سے کوئی کام لیا، نہ دُنیوی مفادات کا کوئی لالچ دلایا، نہ کسی دشمن کے ہوّے سے لوگوں کو ڈرایا۔ دنیا میں جتنے بھی چھوٹے بڑے مدبّر اورسیاست دان گزرے ہیں، انھوں نے ہمیشہ اپنے سیاسی منصوبوں کی تکمیل میں انھی محرکات سے کام لیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں سے فائدہ اُٹھاتے، تو یہ بات آپؐ کی قوم کے مزاج کے بالکل مطابق ہوتی۔ لیکن آپؐ نے نہ صرف یہ کہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں اُٹھایا، بلکہ ان میں سے ہرچیز کو ایک فتنہ قرار دیا، اور ہرفتنے کی خود اپنے ہاتھوں سے بیخ کنی فرمائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو صرف خدا کی بندگی اور اطاعت، عالم گیر انسانی اخوت، ہمہ گیر عدل و انصاف، اعلائے کلمۃ اللہ اور خوفِ آخرت کے محرکات سے جگایا۔ یہ سارے محرکات نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ تھے۔ اس وجہ سے آپؐ کی مساعی سے دُنیا کی قوموں میں صرف ایک قوم کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ ایک بہترین اُمت ظہور میں آئی، جس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے:
کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ
(اٰلِ عمرٰن ۳:۱۱۰) تم بہترین اُمت ہو جو لوگوں (کی راہ نمائی) کے لیے مبعوث کیے گئے ہو، معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور حضوؐر کے تدبّر کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپؐ جن اصولوں کے داعی بن کر اُٹھے، اگرچہ وہ جیسا کہ مَیں نے عرض کیا: فرد، معاشرہ اور قوم کی ساری زندگی پر حاوی تھے، انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہرگوشہ ان کے احاطے میں آتا تھا۔ لیکن آپؐ نے اپنے کسی اصول کے معاملے میں کبھی کوئی لچک قبول نہیں کی، نہ دشمن کے مقابل میں، نہ دوست کے مقابل میں۔ آپؐ کو سخت سے سخت حالات سے سابقہ پیش آیا، ایسے سخت حالات سے کہ لوہا بھی ہوتا تو ان کے مقابل میں نرم پڑجاتا، لیکن آپؐ کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپؐ نے کسی سختی سے دب کر کسی اصول کے معاملے میں کوئی سمجھوتا گوارا نہیں کیا۔
اسی طرح آپؐ کے سامنے پیش کشیں بھی کی گئیں، اور آپؐ کو مختلف قسم کی دینی و دنیوی مصلحتیں بھی سمجھانے کی کوششیں کی گئیں مگر ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ آپؐ جب دُنیا سے تشریف لے گئے تو اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپؐ کی زبانِ مبارک سے نکلی ہوئی ہربات اپنی اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر کی طرح ثابت و قائم تھی۔ دُنیا کے مدبّروں اورسیاست دانوں میں سے کسی ایسے مدبّر اور سیاست دان کی نشان دہی آپ نہیں کر سکتے، جواپنے دوچار اصولوں کو بھی دُنیا میں برپا کرنے میں اتنا مضبوط ثابت ہوسکا ہو، کہ اس کی نسبت یہ دعویٰ کیا جاسکے کہ اس نے اپنے کسی اصول کے معاملے میں کمزوری نہیں دکھائی، یا کوئی ٹھوکر نہیں کھائی۔ لیکن آںحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا نظامِ زندگی کھڑا کر دیا، جو اپنی خصوصیات کے لحاظ سے زمانے کے مذاق اوررجحان سے اتنا بے جوڑ تھا کہ وقت کے مدبرین اور ماہرینِ سیاست اس انوکھے نظام کے پیش کرنے کے سبب سے آںحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذباللہ دیوانہ کہتے تھے، لیکن حضوؐ ر نے اس نظامِ زندگی کو عملاً دُنیا میں برپا کرکے ثابت کردیا کہ جو لوگ آپؐ کو دیوانہ سمجھتے تھے، وہ خود دیوانے تھے۔
صرف یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذاتی مفاد یا مصلحت کی خاطر اپنے کسی اصول میں کوئی ترمیم نہیں فرمائی، بلکہ اپنے پیش کردہ اصولوں کے لیے بھی اپنے اصولوں کی قربانی نہیں دی۔ اصولوں کے لیے جان اور مال اور دوسری تمام محبوبات کی قربانی دی گئی۔ ہر طرح کے خطرات برداشت کیے گئے، اور ہر طرح کے نقصانات گوارا کیے گئے، لیکن اصولوں کی ہرحال میں حفاظت کی گئی۔ اگر کوئی بات صرف کسی خاص مدت تک کے لیے تھی، تو اس کا معاملہ اور تھا۔ وہ اپنی مدت پوری کر چکنے کے بعد ختم ہوگئی یا اس کی جگہ اس سے بہتر کسی دوسری چیز نے لے لی۔ لیکن باقی رہنے والی چیزیں ہرحال اور ہرقیمت پر باقی رکھی گئیں۔ آپؐ کو اپنی پوری زندگی میں یہ کہنے کی نوبت کبھی نہیں آئی کہ میں نے دعوت تو دی تھی فلاں اصول کی، لیکن اب حکمت ِعملی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر فلاںبات بالکل اس کے خلاف اختیار کرلی جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اس اعتبار سے بھی دُنیا کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے کہ آپؐ نے سیاست کو عبادت کی طرح ہرقسم کی آلودگیوں سے پاک رکھا۔
آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں وہ بہت سی چیزیں مباح بلکہ بعض حالات میں مستحسن سمجھی جاتی ہیں، جو شخصی زندگی کے کردار میںمکروہ اور حرام قرار دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے جھوٹ بولے، چال بازیاں کرے، عہدشکنیاں کرے، لوگوں کو فریب دے، یا ان کے حقوق غصب کرے، تو اگرچہ اس زمانے میں اقدار اور پیمانے بہت کچھ بدل چکے ہیں، تاہم اخلاق بھی ان چیزوں کو معیوب ٹھیراتا ہے اور قانون بھی ان باتوں کو جرم قرار دیتا ہے۔
لیکن اگر ایک سیاست دان اور ایک مدبّر یہی سارے کام اپنی سیاسی پارٹی یا اپنی قوم یا اپنے ملک کے لیے کرے، تو یہی سارے کام اس کے فضائل و کمالات میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی میں بھی اس کے اس طرح کے کارناموں پر اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اورمرنے کے بعد بھی انھی کمالات کی بناپر وہ اپنی قوم کا ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ سیاست کے لیے یہی اوصاف و کمالات عرب جاہلیت میں بھی ضروری سمجھے جاتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو لوگ ان باتوں میں شاطر ہوتے تھے وہی لوگ اُبھر کر قیادت کے مقام پر آتے تھے۔
لیکن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی زندگی سے دُنیا کو یہ درس دیا کہ ایمان داری اور سچائی جس طرح انفرادی زندگی کی بنیادی اخلاقیات میں سے ہے، اسی طرح اجتماعی اور سیاسی زندگی کے لوازم میں سے بھی ہے۔ بلکہ آپؐ نے ایک عام شخص کے جھوٹ کے مقابلے میں ایک صاحب ِ اقتدار اور ایک بادشاہ کے جھوٹ کو جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، کہیں زیادہ سنگین قرار دیا ہے۔
آپؐ کی پوری سیاسی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اس سیاسی زندگی میں وہ تمام مراحل آپؐ کو پیش آئے ہیں،جن کے پیش آنے کی ایک سیاسی زندگی میں توقع کی جاسکتی ہے۔ آپؐ نے ایک طویل عرصہ نہایت مظلومیت کی حالت میں گزارا اور کم و بیش اتنا ہی عرصہ آپؐ نے اقتدار اور سلطنت کا گزارا۔ اس دوران میں آپؐ کو حریفوں اور حلیفوں دونوں سے مختلف قسم کے سیاسی اور تجارتی معاہدے کرنے پڑے، دشمنوں سے متعدد جنگیں کرنی پڑیں، عہدشکنی کرنے والوں کے خلاف جوابی اقدامات کرنے پڑے، قبائل کے وفود سے معاملے کرنے پڑے، آس پاس کی حکومتوں کے وفود سے سیاسی گفتگوئیں کرنی پڑیں، سیاسی گفتگوئوں کے لیے اپنے وفود ان کے پاس بھیجنے پڑے، اور بعض بیرونی طاقتوں کے خلاف فوجی اقدامات کرنے پڑے۔
یہ سارے کام آپؐ نے انجام دیے، لیکن دوست اور دشمن، ہرشخص کو اس بات کا اعتراف ہے کہ آپؐ نے کبھی کوئی وعدہ جھوٹا نہیں کیا، اپنی کسی بات کی غلط تاویل کرنے کی کوشش نہیں فرمائی، کوئی بات کہہ چکنے کے بعد اس سے انکار نہیں کیا، اور کسی معاہدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی۔ حلیفوں کا نازک سے نازک حالات میں بھی ساتھ دیا اور دشمنوں کے ساتھ بدتر سے بدتر حالات میں بھی انصاف کیا۔
اگر آپ دُنیا کے مدبّرین اور اہلِ سیاست کو اس کسوٹی پر جانچیں، تومَیں پورے اعتقاد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی آپ اس کسوٹی پر کھرا نہ پائیں گے۔ پھر یہ بات بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ سیاست میں عبادت کی سی دیانت اور سچائی قائم رکھنے کے باوجود حضوؐر کو اپنی سیاست میں کبھی کسی ناکامی کا تجربہ نہیں کرنا پڑا۔ اب آپ اس چیز کو چاہے تدبّر سے تعبیر کیجیے یا حکمت ِ نبوت!
آںحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور حضوؐر کے تدبّر کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ آپؐ نے عرب جیسے ملک کے ایک ایک گوشے میں امن و عدل کی حکومت قائم کردی۔ کفّار و مشرکین کا زور آپؐ نے اس طرح توڑ دیا کہ فتح مکہ کے موقعے پر فی الواقع انھوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہود کی سیاسی سازشوں کا بھی آپؐ نے خاتمہ کر دیا، رومیوں کی سرکوبی کے لیے بھی آپؐ نے انتظامات فرمائے۔ یہ سارے کام آپؐ نے کرڈالے، لیکن پھر بھی انسانی خون بہت کم بہا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تاریخ بھی شہادت دیتی ہے اور آج کے واقعات بھی شہادت دے رہے ہیں کہ دُنیا کے چھوٹے چھوٹے انقلابات میں بھی ہزاروں لاکھوں جانیں ختم ہوجاتی ہیں اور مال و اسباب کی بربادی کا تو کوئی اندازہ نہیں کیاجاسکتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جو انقلاب برپا ہوا، اس کی عظمت اوروسعت کے باوجود شاید ان نفوس کی تعداد چندسو سے زیادہ نہیں ہوگی، جو اس جدوجہد کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے شہید ہوئے یامخالف گروہ کے آدمیوں میں سے قتل ہوئے۔
پھر یہ بات بھی غایت درجہ اہمیت رکھتی ہے کہ دُنیا کے معمولی معمولی انقلابات میں بھی ہزاروں لاکھوں آبروئیں فاتح فوجوں کی ہوس کا شکارہوجاتی ہیں۔ اس تہذیب و تمدن کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فاتح ملک کی فوجوں نے مفتوح ملک کی سڑکیں اورگلیاں حرام کی نسلوں سے بھر دی ہیں۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اربابِ سیاست اس صورتِ حال پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرنے کے بجاے اس کو ہر’انقلاب کا ایک ناگزیر‘ نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دُنیا میں جو انقلاب رُونما ہوا، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کوئی ایک واقعہ بھی ہم کو ایسا نہیں ملتا کہ کسی نے کسی کے ناموس پر دست درازی کی ہو۔
اہلِ سیاست کے لیے طمطراق بھی سیاست کے لوازم میں سے سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ عوام کو ایک نظام میں پرونے اور ایک نظم قاہر کے تحت منظم کرنے کے لیے اُٹھتے ہیں، وہ بہت سی باتیں اپنوں اور بیگانوں پر اپنی سطوت جمانے اور اپنی ہیبت قائم کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ان کی سیاسی زندگی کے لازمی تقاضوں میں سے ہیں۔ اگر وہ یہ باتیں نہ اختیار کریں گے تو سیاست کے جو تقاضے ہیں، وہ ان کو پورا کرنے سے قاصر رہ جائیں گے۔
اسی طرح کے مقاصد کے پیش نظر جب وہ نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے جلو میں چلتے ہیں، جہاں وہ ظاہر ہوتے ہیں ان کے نعرے بلند کرائے جاتے ہیں، جہاں وہ اُترتے ہیں ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسوں میں ان کے حضور میں ایڈریس [سپاس نامے] پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔
جب وہ مزید ترقی کرجاتے ہیں تو ان کے لیے قصرو ایوان آراستہ کیے جاتے ہیں، ان کو سلامیاں دی جاتی ہیں، ان کے لیے بَری و بحری اورہوائی خاص سواریوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ جب کبھی وہ کسی سڑک پر نکلنے والے ہوتے ہیں تو وہ سڑک دوسروں کے لیے بند کردی جاتی ہے۔ موجودہ زمانے میں ان چیزوں کے بغیر نہ کسی صاحب ِ سیاست کا تصور دوسرے ہی لوگ کرتے ہیں اور نہ کوئی صاحب ِ سیاست، ان لوازم سے الگ خود اپنا کوئی تصور کرتا ہے۔
لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی دُنیا کے تمام اہلِ سیاست سے الگ رہے۔ جب آپؐ اپنے صحابہ میں چلتے تو کوشش فرماتے کہ سب کے پیچھے چلیں، مجلس میں تشریف رکھتے تو اس طرح گھل مل کر بیٹھتے کہ یہ امتیاز کرنا مشکل ہوتا کہ محمدؐ رسول اللہ کون ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو دوزانو ہوکر بیٹھتے اور فرماتے کہ ’’میں اپنے ربّ کا غلام ہوں اورجس طرح ایک غلام کھانا کھاتا ہے، اس طرح مَیں بھی کھانا کھاتا ہوں۔‘‘ ایک مرتبہ ایک بدّو اپنے اس تصور کی بنا پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے ذہن میں رہا ہوگا، سامنے آیا تو حضوؐر کو دیکھ کر کانپ گیا۔ آپؐ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ’’ڈرو نہیں، میری ماں بھی سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ یعنی جس طرح تم نے اپنی ماں کو بدویانہ زندگی میں سوکھا گوشت کھاتے دیکھا ہوگا، اسی طرح کا سوکھا گوشت کھانے والی ایک ماں کا بیٹا مَیں بھی ہوں‘‘۔ نہ آپؐ کے لیے کوئی خاص سواری تھی، نہ کوئی خاص قصر و ایوان تھا، اور نہ کوئی خاص باڈی گارڈ تھا۔ آپؐ جو لباس دن میں پہنتے، اسی میں شب میں استراحت فرماتے۔ملکی اور غیرملکی وفود اور سفراء سے مسجد نبویؐ کے فرش پر ملاقاتیں فرماتے، اور وہیں تمام اہم سیاسی امور کے فیصلے فرماتے۔
یہ خیال نہ کیجیے کہ اس زمانے کی بدویانہ زندگی میں سیاست اس طمطراق اور بس ٹھاٹھ باٹ سے آشنا نہیں ہوئی تھی، جس طمطراق اور جس ٹھاٹھ باٹ کی وہ اب عادی ہوگئی ہے۔ جولوگ یہ خیال کرتے ہیں ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ سیاست اور اہلِ سیاست کی تانا شاہی ہمیشہ سے یہی رہی ہے۔ فرق اگر ہواہے تو محض بعض ظاہری باتوں میں ہوا ہے۔ البتہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے طرز کی سیاسی زندگی کا نمونہ دُنیا کے سامنے رکھا۔ جس میں دنیوی کرّوفر کے بجائے خلافت ِالٰہی کا جلال اور ظاہری ٹھاٹھ باٹ کی جگہ خدمت اور محبت کا جمال تھا۔ لیکن اس سادگی اور اس فقرودرویشی کے باوجود اس کے دبدبے اوراس کے شکوہ کا یہ عالم تھا کہ روم و شام کے بادشاہوں پر اس کے تصور سے لرزہ طاری ہوتا تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور آپؐ کے تدبّر کا ایک اور پہلو بھی خاص طور پر قابلِ ذکر ہے، کہ آپؐ نے اپنی حیاتِ مبارکہ میں ہی ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تربیت کر کے تیار کر دی، جو آپؐ کے پیدا کردہ انقلاب کو اس کے اصلی مزاج کے مطابق آگے بڑھانے، اس کو مستحکم کرنے اور اجتماعی و سیاسی زندگی میں اس کے تمام مقتضیات کو بروئے کار لانے کے لیے پوری طرح اہل تھے۔
چنانچہ اس تاریخی حقیقت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کرسکتا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس انقلاب نے عرب سے نکل کر آس پاس کے دوسرے ممالک میں قدم رکھ دیا۔ اور دیکھتے دیکھتے اس کرئہ ارض کے تین براعظموں میں اس نے اپنی جڑیں جمالیں، اور اس کی اس وسعت کے باوجود اس کی قیادت کے لیے موزوں اشخاص و رجال کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے جن تین براعظموں کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کے متعلق یہ حقیقت بھی ہرشخص جانتا ہے کہ ان کے اندر وحشی قبائل آباد نہیں تھے، بلکہ وقت کی نہایت ترقی یافتہ، جبار و قہار شاہنشاہتیں تھیں۔ لیکن اسلامی انقلاب کی موجوں نے جزیرئہ عرب سے اُٹھ کر اُن کو ان کی جڑوں سے اس طرح اُکھاڑ پھینکا، گویا زمین میں ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ اور ان کے ظلم و جَور کی جگہ ہرگوشے میں اسلامی تہذیب و تمدن کی برکتیں پھیلا دیں، جن سے دُنیا صدیوں تک متمتع ہوتی رہی۔
دُنیا کے تمام مدبّرین اور اہلِ سیاست کی پوری فہرست پر نگاہ ڈال کر غور کیجیے، کہ ان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نظر آتا ہے، جس نے اپنے دوچار ساتھی بھی ایسے بنانے میں کامیابی حاصل کی ہو، جو اس کے فکروفلسفہ اور اس کی سیاست کے ان معنوں میں عالم اور عامل رہے ہوں، جن معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے عالم و عامل ہزاروں صحابہؓ تھے؟
آخر میں ایک بات بطور تنبیہ عرض کردینا ضروری سمجھتا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی مرتبہ اورمقام یہ ہے کہ آپؐ نبیِ خاتم اور پیغمبرِعالمؐ ہیں۔ سیاست اور تدبّر اس مرتبۂ بلند کا ایک ادنیٰ شعبہ ہے۔ جس طرح ایک حکمران کی زندگی پر ایک تحصیل دار کی زندگی کے زاویے سے غور کرنا ایک بالکل ناموزوں بات ہے، اس سے زیادہ ناموزوں بات شاید یہ ہے کہ ہم سیّدکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک ماہرِ سیاست، یا ایک مدبّر کی زندگی کی حیثیت سے غور کریں۔
نبوت اور رسالت ایک عظیم عطیۂ الٰہی ہے۔ جب یہ عطیہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بخشتا ہے تو وہ سب کچھ اس کو بخش دیتا ہے، جو اس دُنیا میں بخشا جاسکتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ خاتم الانبیا ؐ تھے، صرف رسول ہی نہیں تھے بلکہ سیّدالمرسلؐ تھے، صرف اہلِ عرب ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور آپؐ کی تعلیم و ہدایت صرف کسی خاص مدت تک ہی کے لیے نہیں تھی بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی تھی۔
اوریہ بھی ہرشخص جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ’دینِ رہبانیت‘ کے داعی بن کرنہیں آئے تھے، بلکہ ایک ایسے دین کے داعی تھے، جو روح اور جسم دونوں پر حاوی اور دُنیا و آخرت دونوں کی حسنات کا ضامن تھا۔ جس میں عبادت کے ساتھ سیاست، اور درویشی کے ساتھ حکمرانی کا جوڑ محض اتفاق سے نہیں پیدا ہوگیا تھا بلکہ یہ عین اس کی فطرت کا تقاضا تھا۔ جب صورتِ حال یہ ہے تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سیاست دان اور مدبّر اور کون ہوسکتا ہے؟ لیکن یہ چیز آپؐ کا اصلی کمال نہیں بلکہ جیسا کہ مَیں نے عرض کیا، آپؐ کے فضائل و کمالات کا محض ایک ادنیٰ شعبہ ہے۔
بدقسمتی سے یہ بات مشہور ہوگئی ہے کہ قرآن ایک مشکل کتاب ہے، اس کو سیکھنے کے لیے بہت سے علوم درکار ہیں ، اس کا سیکھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ علما کاکام ہے۔
کیا قرآن سیکھنا واقعی مشکل ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۂ قمر کی آیت ۱۷میں دے دیا ہے: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَہَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ۱۷’’اوریقیناً ہم نےاس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے ، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنےوالا؟‘‘
مفسرین کرام اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں :’’قرآن کریم نے اپنے مضامین عبرت و نصیحت کو ایسا آسان کر کے بیان کیا ہے کہ جس طرح بڑے سے بڑا عالم و ماہر، فلسفی اور حکیم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح ہر عالم اور بے علم جس کو علوم سے کوئی مناسبت نہ ہو وہ بھی عبرت و نصیحت کے مضامین قرآنی کو سمجھ کر اس سے متاثر ہوتا ہے۔’’اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کررکھا ہے،کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟‘‘،اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید آسان تو بے شک ہے، لیکن صرف عبرت وتذکیر، ترغیب و ترہیب کے اعتبار سے،تاہم استنباطِ مسائل بجائے خود ایک مستقل ودقیق فن ہے ، جو کہ خصوصی مہارت اور تحقیق کا محتاج ہے۔
علمائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کو معنی ا ور مضامینِ عبرت و نصیحت کے اعتبار سے عام لوگوں کے لیے بھی سمجھنا آسان ہے، البتہ مسائل اور احکام کا استنباط و اجتہاد صرف علمائے کرام ہی کاکام ہے جس کے لیے علوم قرآن وحدیث اور دوسرے کئی علوم کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔
سورئہ قمر میں یہ آیت چار مرتبہ دہرائی گئی ہے اورہربار اس سے پہلے فرمایا گیا ہے: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ۱۶ (القمر۵۴:۱۶)’’دیکھ لو، کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات‘‘ ، یعنی اگر اس آسان کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو پھر میرے عذاب کے لیے تیار رہو۔
یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ عام آدمی کی حیثیت ایک طالب علم کی ہے اور وہ تذّکر(زندگی گزارنےکے لیے احکام و نصیحت) کی حد تک قرآن کو سیکھے گا۔ تذکّر سے مراد قرآن کو اتنا سمجھنا ہے جس سے ہم زندگی گزارنے کے عمومی اوامر(DOs۔احکامات) و نواہی (DONTs -ممنوعات)کو جان لیں۔یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، ویسے تو ہر مسلمان کو قرآن پر تدبر کرنا چاہیے لیکن یہاں تدبّرسے مراد قرآن پر ایسے غور و فکر کرنا ہےجس سے عصری دینی مسائل کا استنباط یا اجتہاد کیا جائے اور فقہی مسائل معلوم کیے جائیں۔یہ صرف علمائےکرام و فقہائےعظّام کا کام ہے جس کے لیے علومِ قرآن اور دین کی مجموعی تعلیم اورتفہیم ضروری ہے، یہ ہر کسی کا کام نہیں۔ اس بات کو قرآن حکیم میں یوں بیان کیا گیا ہے:كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰہُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِہٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ۲۹ (صٓ۳۸:۲۹)’’یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو (اے محمدؐ!) ہم نے تمھاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر والے اس سے سبق لیں‘‘۔ اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق روزِ قیامت تک اس کی تشریح و تفسیر ہوتی رہے گی اور اس کے مطالب ختم نہیں ہوں گے۔
قرآن سیکھتے وقت یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم اسے کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا اہم ہے کہ قرآن کے اسرارو رُموز پر تدبر کرنا ، علم میں اضافہ کرنا، اس کے ادبی اعجاز پر سردھننا، سائنسی علوم کی روشنی میں آیات کی تکوینی تشریحات سے لطف اندوزہونا یا اس میں بیان کردہ عقائد، معاشرتی،سماجی ، معاشی، معاملات پرغور وفکر کرنے میں اس کتاب کے برحق ہونے کے دلائل ہیں لیکن یہ اس کے ضمنی فوائد ہیں۔قرآن کا اصل مقصدیہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑپر اس سے عملی راہنمائی حاصل کی جائے تاکہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں،جس کا ذکرسورئہ فاتحہ میں بیان ہوا اورہم نماز میں روزانہ کم ازکم ۳۲ مرتبہ اللہ سے یہی درخواست کرتے ہیں۔
قرآن نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کی کایا پلٹ دی اس لیے کہ ان کا قرآن سیکھنا ’علم برائے عمل‘ تھا۔ابی عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ سے مروی مسند احمد کی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ’’ایک صحابی سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس دس آیات پڑھتے تھے اور اگلی دس آیات اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ پہلی دس آیات میں علم و عمل سے متعلق چیزیں اچھی طرح سیکھ نہ لیتے ،یوں ہم نے علم وعمل کو حاصل کیا ہے‘‘۔
قرآن سے ہماری زندگی اسی لیے تبدیل نہیں ہو رہی کہ عام طور پر قرآن پڑھتے یا سیکھتے وقت یہ مقصد نہ ہمارے ذہن میں واضح ہوتا ہے اور نہ ہمارے عمل سے اس کا اظہار۔ قرآن کو ’علم برائے عمل‘کے مقصد سے پڑھنے اور سیکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر ہر آیت میں اپنی زندگی کےلیےعملی نکات تلاش کرنے کی کوشش کریں اور ان کو ترجیحاً اپنی انفرادی زندگی میں نافذکریں اور ساتھ ہی اجتماعی زندگی میں اس کے نفاذ کی جد و جہد کا حصہ بنیں۔
یہ بات یاد رکھنا بھی انتہائی اہم ہےکہ اجتماعی نظام، افراد کے مرہون ِ منت ہے۔ انفرادی عقائد و تصورات میں کمزوری ،اجتماعی نظام کی پوری عمارت کو کمزور کرنے یا گرانے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ اصول اجتماعی جدوجہد کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ افراد کی اپنی فکر اوردین کا منہج صحیح نہ ہو تو اجتماعی اصلاح کا تصور خیالِ خام کے سوا کچھ نہ ہوگا ؎
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ
اس لیے اقامت دین کی اجتماعی جدوجہد میں ہمیں انفرادی حیثیت میں قرآن فہمی کو اپنی ترجیح بنانا ہوگا۔
قرآن سیکھنے کے لیے چند اہم باتوں کی طرف توجہ ضروری ہے:
اللہ تعالیٰ نے سورۂ آل عمران میں فرمایا ہے :ھُوَالَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْہُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ ھُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِہٰتٌ۰ۭ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِہِمْ زَيْـغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَہَ مِنْہُ ابْتِغَاۗءَ الْفِتْنَۃِ وَابْتِغَاۗءَ تَاْوِيْلِہٖ۰ۚ۬ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَہٗٓ اِلَّا اللہُ ۰ۘؔ (اٰلِ عمرٰن ۳:۷)’’وہی خدا ہے، جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں: ایک محکمات، جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
شیطان محکمات کی بجائے انسان کو متشابہات اور عملی زندگی کے لیےغیرضروری مباحث میں اُلجھا دیتاہے ۔ اقبالؒ نےشیطان کے اس حربے کو شیطان کی زبانی یوں بیان کیا ہے ؎
ہے یہی بہتر الہٰیات میں اُلجھا رہے
یہ کتابُ اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے
خلاصۂ کلام یہ ہے کہ اوّلین ترجیح اور بہتر صورت یہی ہے کہ قرآن کریم استاد سے سیکھیں ، استاد میسر نہ ہو تو انفرادی طور پر کسی تفسیر کا مطالعہ کریں ( زیادہ مناسب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ تفاسیر پیشِ نظر رکھیں)۔ بہتر یہ ہو گا کہ گروپ بنا کے مطالعہ کریں اور یہ اصول ہمیشہ پیش نظر رکھیں جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کردیا ہے : ’’جس نے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے‘‘۔ (ترمذی)
عربی زبان سیکھنا ایک احسن کام ہے، لیکن اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو یہ قرآن نہ سیکھنے کا بہانہ نہیں ہوسکتا۔ الحمد للہ! ہمارے علمائے کرام کا ہم پر بہت احسان ہے کہ آج تقریباً ہر زبان میں قرآن کے تراجم اور تفاسیرموجود ہیں جن سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عربی سمجھنا فی نفسہٖ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں جب ہم قرآن مجید کو سمجھ جائیں تو اس پر عمل کی فکر کریں۔ کیا ابولہب، ابوجہل ، مغیرہ بن ولید، عمرو بن یکرب جیسے ادیب اور لبید جیسے شاعر کو عربی نہیں آتی تھی؟لیکن جب ان کا مقصد قرآن کو سمجھ کر اسے دل میں اتارنا اور اس پر عمل کرنا نہیں تھا تو ’عربی دان‘ ہونے کے باوجود گمراہ ہی رہے۔ان کی عربی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ یہی حالت مستشرقین کی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھتے تو ہیں لیکن اس کے نتیجے میں انھیں ہدایت نہیں ملتی کیونکہ قرآن سے ہدایت لینا ان کا مقصد ہی نہیں ہوتا ۔البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم اتنی عربی سیکھنے کی کوشش ضرور کریں کہ جب تلاوت ہورہی ہو تو ہم اسے سمجھ رہے ہوں اور اگر زبان میں مزید مہارت حاصل کرلی تو یہ قرآن کی تاثیر کوبھی مزید بڑھائے گی اور ہم قرآن پر تدبر اور اس کے رُموز و اسرار سے لطف اندوز بھی ہو سکیں گے۔
نماز کے معیار کو اللہ تعالیٰ نے سورۂ عنکبوت کی آیت۴۵میں یوں بیان فرمایا ہے: اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْہٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ۰ۭ ’’بے شک نماز بےحیائی سے اور فحش کاموں سے باز رکھتی ہے‘‘، یعنی نماز کا اصل معیار (standard) یہ ہے کہ اس کا ایک مسلمان پر یہ اثر ہو کہ وہ فحاشی اور بےحیائی سے رُک جائے۔ ہمیں اپنی نماز کو اس معیار کا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔
اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ایک مسلمان قرآن پڑھے تو اس پر قرآن کے کچھ اثر ات ہونے چاہئیں:
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللہُ وَجِلَتْ قُلُوْبُہُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْہِمْ اٰيٰتُہٗ زَادَتْہُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰي رَبِّہِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ۲ۚۖ (الانفال۸:۲)سچے اہلِ ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سُن کر لرز جاتے ہیں اورجب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنےربّ پر اعتماد رکھتے ہیں۔
اَللہُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِہًا مَّثَانِيَ۰ۤۖ تَــقْشَعِرُّ مِنْہُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّہُمْ۰ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُہُمْ وَقُلُوْبُہُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللہِ۰ۭ ذٰلِكَ ہُدَى اللہِ يَہْدِيْ بِہٖ مَنْ يَّشَاۗءُ۰ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللہُ فَمَا لَہٗ مِنْ ہَادٍ۲۳ (الزمر۳۹:۲۳) اللہ نے بڑا اچھاکلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوجاتےہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے اس کے ذریعے وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ۔
وَاِذَاسَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓي اَعْيُنَہُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَـقِّ۰ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰہِدِيْنَ۸۳(المائدہ۵:۸۳) جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسولؐ پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوجاتی ہیں،اور کہتےہیں کہ ’’پروردگار ! ہم ایمان لے آئے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے ‘‘۔
یہ ہے قرآن پڑھنے اصل معیارِ مطلوب کہ جب مسلمان قرآن پڑھیں تو ان کے دل کی کیفیت ایسی ہو جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے، یعنی ان کےدل لرز جائیں،رونگٹے کھڑے ہوجائیں، بدن نرم پڑ جائیں اورکانپنے لگیں، آنکھوں سے آنسو امڈ پڑیں اورایمان مزیدمضبوط ہوجائے۔ کسی مسلمان کے دل پر قرآن کا ایسا اثر ہو تو وہ تبدیل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب قرآن سمجھ کر پڑھا جائے ۔
یہ بات تو پہلےبیان کی جاچکی ہے کہ اتنا قرآن سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس سے وہ اپنی روزمرہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے۔ اگر استاد میسر ہو تو اس سے سیکھنا افضل ہے لیکن اگر کسی وجہ سے استاد میسر نہ ہو،تو سیکھنے کا ایک نہایت فائدہ مند طریقہ اجتماعی قرآن کلاس ہے۔ اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ایسے گوشے سامنے آجاتے ہیں جو انفرادی مطالعہ میں اکثر کھل کر سامنے نہیں آتے۔
یہ بات ضروری ہے کہ شرکاء دل کی دنیا صاف کرکے شریک ہوں تاکہ قرآن کی امانت اٹھانے کے لیے دل میں صلاحیت پیدا ہو اوربیان کردہ مطلوبہ اثرات مرتب ہوں۔ شرکاء میں یہ ذہنی ہم آہنگی ہو کہ ہم قرآن کا مطالعہ اپنے فائدے اور عمل کےلیے کررہے ہیں۔کلاس سے پہلے ہر فرد اپنے زیر مطالعہ تفسیرسے سیکھنےکی کوشش کرے اور صرف دوسرے شرکاء کی گفتگو اور علم پر اکتفا نہ کرے۔ اس طرح اجتماعی مطالعہ کرنے کی افادیت بہت بڑھ جاتی ہے۔درج ذیل سطورمیں قرآن کلاس کی ترتیب بیان کی گئی ہے:
کلاس کی ابتدا میں ایک فرد(جس کا تعین پہلےسے گذشتہ کلاس میں ہوچکا ہوگا اور جو عمومی طور پر میزبان ہی ہوگا)، اپنی مقررکردہ تفسیر سے رکوع کی تلاوت، رواں ترجمہ، الفاظ کے معانی اور رکوع کا عمومی پیغام بیان کرے ۔
متعلقہ فرد کی تشریح کے بعد ہر ممبر اپنی زیر مطالعہ تفسیر سے اس رکوع میں فکر و عمل کے حوالے سے پیغام سے شرکا کو آگاہ کرے ۔پھر تمام شرکا بحث میں حصہ لیں تاکہ رکوع کا پیغام کھل کر سامنے آجائے،البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک فرد کی طرف سے بیان شدہ تفصیلات دوبارہ بیان نہ کی جائیں تاکہ وقت کا بہتر استعمال ہو سکے۔
عصری حالات کے تناظر میں رکوع کے پیغام پر غور و فکر کریں اور اہم نکات نوٹ کرلیں۔ مطالعہ میں جو نکات تفصیل طلب رہ جائیں اور جن کا جواب زیر مطالعہ تفاسیر میں موجود نہ ہو تو اپنے طور پر کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہ کیا جائے بلکہ ہر فرد بعد میں ان نکات کی تفصیل اور وضاحت کے لیے علمائے کرام سے رجوع کرے اور ان کی بتلائی ہوئی تشریح اگلی میٹنگ میں بیان کرے اور ان آراء کے مطابق حتمی تشریح پر اتفاق کیاجائے ۔
بہتر ہے کہ قرآن کلاس مسجد میں ہو ، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو باری باری ساتھیوں کے گھروں یا کسی متعین جگہ پر بھی کلاس ہو سکتی ہے۔ہر کلاس میں اگلی کلاس کے وقت اور مقام کا تعین کرلیا کریں۔ کھانے پینے سے حتی الوسع اجتناب کیا جائے یا بندوبست میں لازماً سادگی کااہتمام کیا جائے۔
سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے سمجھیں اور جوجو حکم سمجھ آتا جائے اس کے مطابق عمل کرتے جائیں۔ یہی وہ بات تھی جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کی کایا پلٹ دی۔ایک اُجڈ اور جاہل عرب قوم دنیا کی مہذب ترین قوم بن گئی اور ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا جو چشم فلک نے نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں دیکھ سکی۔ جب قرآن کی آیات نازل ہوتیں تو صحابہؓ فوراً عمل کی سوچتے تھے۔ انھوں نے قرآن کو اپنے لیے سمجھا اور اسی لیے ان کی زندگی تبدیل ہوئی۔ اگرمسلمان قرآن اسی طرح پڑھیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنھم پڑھتے اورسمجھتے تھے تو آج بھی ویسی ہی تبدیلی آسکتی ہے جیسے ان کی زندگیوں میں آئی۔صاحبِ تفہیم القرآن نے یہی بات یوں بیان فرمائی ہے:’’اسے تو پوری طرح آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ اسے لے کر اٹھیں اور دعوت الی اللہ کا کام شروع کریں اور جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی ہے اسی طرح قدم اٹھاتے جائیں۔ قرآن کے احکام، اس کی اخلاقی تعلیمات، اس کی معاشی اور تمدّنی ہدایات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اس کے بتاۓ ہوۓ اصول و قوانین آدمی کی سمجھ میں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتے جب تک وہ عملاً ان کو برت کر نہ دیکھے، نہ وہ فرد اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی انفرادی زندگی کو اس کی پیروی سے آزاد رکھا اور نہ وہ قوم اس سے آشنا ہو سکتی ہےجس کے سارے ہی اجتماعی ادارے اس کی بنائی ہوئی روش کے خلاف چل رہے ہوں‘‘ (مقدمہ تفہیم القرآن، جلداول،ص ۳۴-۳۵)
قرآن کلاس کےدرج بالا طریقۂ کار کے مطابق ذیل میں سورئہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی تشریح بطور مثال دی جاتی ہے:
اللہ فرماتا ہے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لے آؤ گے اورپھر یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ ایک دھماکا خیز بیان ہے کہ صرف زبانی کلامی ایمان سے کام نہیں چلے گا۔ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں اچھے اور بُرے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ ایمان لانے کے فوراً بعد آزمائش شروع ہو جاتی ہے اور دین پر قائم رہنے میں مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں۔ اللہ کو تمھارے سب اعمال کا پہلے ہی سے علم ہے لیکن وہ چاہتا ہے تم پر حجّت تمام ہو جائے اور تمھاری اصلیت بھی کھل کر سامنے آجائے کہ مشکلات کے وقت تم اللہ کے کتنے وفادار ہو؟
مومنین کا امتحان، دشمنوں کے مقابلے میں مادی وسائل کی کمی، جسمانی، جذباتی، اور روحانی تکالیف، دنیاوی لالچوں اور بہت سی دوسری مشکلات سے ہوتا ہے۔ غربت، نفسانی خواہشات، دنیا کی کشش ،اقتدار اورشہوانی لذات کی شدت بھی وہ مشکلات ہیں جو دنیا میں پیش آتی ہیں۔موجودہ زمانے میں ایک بہت اہم معاملہ حلال و حرام کی پہچان اور حرام سے بچنا ہے۔ ان سب کا مقابلہ صبر اور استقامت سے تب ہی کیا جا سکتا ہے جب انسان میں اس کے مقابلے کی قوّت موجود ہو۔ یہاں بتا دیا گیاہے کہ وہ قوت اللہ پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے، جس سے وہ زمین پر انفرادی اور اجتماعی طور پر اقامت دین کی جدوجہدکا حق ادا کرنے کے قابل ہوجاتا ہے۔ایمان صرف قولی اقرار نہیں بلکہ اس کا عملی اظہار بھی ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کو پرکھا جا سکے۔ کمزور مسلمانوں اور منافقین پر کوئی مشکل آئے تو وہ ڈگمگا جاتےہیں۔ اللہ لوگوں کے اعمال دیکھ کر ان کو سزا و جزا دیتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی،البتہ یہ اس کا کلّی اختیار ہے کہ کسی کے ساتھ کیا سلوک کرتاہے۔
انسان اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں ہوتا جب تک اس کے اعمال سے یہ واضح نہ ہوجائے کہ وہ اس کا مستحق ہے اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں گیا۔ انصاف وہی ہے جونظربھی آئے، ورنہ اللہ کو تو سب کچھ پہلے ہی سے علم ہے کہ کس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم ہے۔اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ برے اعمال کر کے اللہ کی گرفت سے بچ جائے گا تو یہ ایک انتہائی احمقانہ سوچ ہے، وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بھاگ سکتا۔ بے شک اللہ سننےاور ہرچیز کا علم رکھنے والا ہے، البتہ ایمان کے قولی اور عملی اظہار کے بعد اگر مومنوں سے بشری کمزوریوں کے سبب کوئی گناہ ہوجائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور ان کی نیکیوں کا اجر دیتا ہے۔
ان آیات میں مشرک ہونے کے باوجود والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے،البتہ اگروہ پورا زور لگائیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ تواس کا انکار کیاجائے گا۔وہ ایسی بات کسی دلیل یا علم کی بنیاد پر نہیں کہتے۔ والدین سے حسن سلوک کے بارے آیات سےیہ نکتہ بھی واضح ہے کہ جب اللہ کی محبت اور اطاعت کی بات آئےتو وہ نسب کے قریب ترین رشتوں پر بھی غالب ہوگی۔
آیت۱۰ میں فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد تمھارے پاس آگئی ہے، حالانکہ بظاہر ایسا نہیں تھا اور مسلمان مکہ میں انتہائی مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ یہ قرآن کا منفردطرز استدلال اور اعجازِ بیان ہے کہ وہ چیزوں کو ماضی میں بیان کردیتا ہے جس کا مطلب قطعی یقین کا اظہار ہوتا ہے کہ گویا یہ تو ہوکر رہے گا ۔ علما نے فرمایا کہ یہ دراصل آنے والی مدد(غزوہ بدر اور دوسری فتوحات وغیرہ) کے بارے میں پیشن گوئی تھی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ اللہ زمان و مکان کی قید سے مبّراہے اور اسے ماضی، حال اور مستقبل کی سب حقیقتوں کا علم ہے۔
دورِ نبویؐ میں ایسے بدقسمت اور احمق کفاربھی تھے جو لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ہماری (شرک و کفرمیں) اتباع کرلو ،قیامت کے دن ہم تمھاری جگہ جواب دےدیں گے کہ ہم نے انھیں ایسا کرنے کوکہاتھا اور اس کی سزا ہمیں دی جائے۔ بدقسمتی سےآج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دنیاوی مفادات یا دوسرے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کو اسی طرح کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانےکے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنھیں انھوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں اور ان کی شیطانی چالوں میں نہ آئیں۔
مسلمان مشکلات و مصائب سے مایوس نہ ہوں۔ یاد رکھیں دنیا میں مشکلات مؤمنوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ انھیں کندن بنانے اور اجر دوبالا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہر حال اور مشکل میں دعوت و اقامت دین کا کام جاری رکھیں۔
مسلمان حق پر استقامت سے قائم رہیں تو بالآخر اللہ ان کو دنیا میں فتحیاب کرتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم اس زمانے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بعض اوقات نزدیک ترین لوگ بھی دین میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ان کو کھلم کھلا بتا دیا جائے کہ دین کی بنیادوں پرکوئی سمجھوتا نہیں ہوسکتا ،چاہےوہ ناراض ہوجائیں۔
یہ بڑی تسلی کی بات ہے کہ مؤمنوں سے بشری کمزوری کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہوجائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے،البتہ کوشش کی جائے کہ گناہ سے اجتناب کیا جائے او ر توبہ و استغفار کی طرف توجہ دی جائے۔
کسی کی ایسی کوئی بات گناہ کا سبب نہ بنے کہ وہ قیامت میں آپ کے گناہ کا ذمہ دارہوگا۔ یہ انتہائی احمقانہ اور خطرناک طرزِعمل ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ایسی شیطانی باتوں سے بچ کر رہیں۔
چند مجوزہ تفاسیر: ان کے علاوہ دوسری تفاسیر سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے:
جدید تفاسیر(عصری مسائل): تدبّر قرآن(مولانا امین احسن اصلاحیؒ)،تفہیم القرآن (سید ابوالاعلیٰ مودودی ؒ) فی ظلالِ القرآن (سید قطبؒ شہید)، بیان القرآن (ڈاکٹر اسرار احمدؒ)، روح القرآن (مولانا ڈاکٹر اسلم صدیقیؒ)، محاسن القرآن (مفتی غلام الرحمٰنؒ) تفسیر القرآن کریم (عبد السلام بن محمد بھٹویؒ)
جدید تفاسیر(عصری دینی مسائل):معارف القرآن(مفتی محمد شفیعؒ) ، تفسیر ماجدی (عبدالماجد دریا بادیؒ)، تیسیر القرآن(عبد الرحمٰن کیلانی ؒ) ضیاء القرآن (پیرکرم شاہ الازہریؒ)، آسان ترجمہ و تفسیر قرآن (مفتی تقی عثمانیؒ)
دیگر تفاسیر: بیان القرآن (اشرف علی تھانویؒ)، ترجمان القرآن (ابوالکلام آزادؒ)، تفسیر ابن کثیر (ابو الفدا ابن کثیرؒ)، تفسیر جلالین(جلال الدین السیوطیؒ)، تفسیر عثمانی ( شبیر احمد عثمانی ؒ)، تفسیرمظہری (قاضی ثناءاللہ پانی پتیؒ)،تفسیرقرطبی (ابوبکر قرطبیؒ)،
الفاظ معانی: تدریس لغات القرآن(ابومسعود حسن علوی ؒ)، صفوت التفاسیر(محمد علی صابونیؒ)، مدارک التنزیل (عبداللہ بن احمد محمدبن محمود النسفیؒ)، مفردات القرآن (مولانا محمد عبدہٗ فیروز پوریؒ)، اور مصباح القرآن جس میں مترادف الفاظ رنگین ترجمے کے ساتھ دیے گئے ہیں (آخر الذکر تینوں تفاسیرموبائل ایپ [EasyQuranWaHadith] ) پربھی موجود ہیں۔
’ضبط ِ ولادت‘ کے موضوع پر ، پروفیسر خورشیداحمد صاحب کی یہ تحریر محترم مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ضبطِ ولادت: عقلی و شرعی حیثیت سے (دارالاشاعت، کراچی، جنوری ۱۹۶۱ء) کے آغاز میں بطورِ ’مقدمہ‘ شائع ہوئی تھی۔ تاہم، مولانا عثمانی صاحب نے مذکورہ کتاب کے تازہ ایڈیشن میں اسے شامل نہیں کیا۔ حالانکہ اصل کتاب کے مقدمے میں خورشیدصاحب سے ممنونیت کا واضح الفاظ میں ذکر موجود تھا، جیساکہ خود خورشیدصاحب کے مقدمے کے آخری جملوں میں بھی کلماتِ تحسین درج ہیں۔ ۶۵برس گزرنے کے بعد آج بھی پاکستان میں مغرب کے کاسہ لیس، ضبط ِ ولادت کی نسبت سے انھی گھسے پٹے ’دلائل‘ کی جگالی کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔(ادارہ)
قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَہُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ۱۶ۙ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّہُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْہِمْ وَمِنْ خَلْفِہِمْ وَعَنْ اَيْمَانِہِمْ وَعَنْ شَمَاۗىِٕلِہِمْ۰ۭ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَہُمْ شٰكِرِيْنَ۱۷ (الاعراف ۷:۱۶-۱۷) بولا’’اچھا تو جس طرح تُو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تُو ان میں سے اکثر کو شکرگزار نہ پائے گا‘‘۔
تاریخ شاہد ہے کہ شیطان ہر دور اور ہر زمانے میں آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہرسمت سے حملہ آورہوا ہے، اور اس نے طرح طرح کےجال انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بچھائے ہیں۔ دورِجدید میں جو حسین اور دل کش فریب شیطان نے انسان کو دیئے ہیں، ان میں سے ایک غربت و افلاس کے ڈر سے قطع نسل اور تحدیدِ نسل بھی ہے۔ بظاہر تو یہ منصوبہ بڑا سادہ اور معصوم سا معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت یہ اسلامی تہذیب و تمدن پر ایک بڑا ہی گہرا وار ہے، اور اس کی زد عقیدے اور ایمان، اخلاقی اقدار اور معاشرتی روایات، سماج اور تمدن سب پر پڑتی ہے، بلاشبہہ: ع
ترے نشتر کی زد شریانِ قیس ناتواں تک ہے
یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلم ممالک بھی آہستہ آہستہ شیطان کے اس نئے حملے کے آگے سپر ڈالنے لگے ہیں، اور اس معاشی مغالطے کا شکار ہورہے ہیں، جس کا تانا بانا ابلیسی فکر نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ بنا ہے۔
تحدید ِ نسل کا مسئلہ اصلاً ایک معاشی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جن حضرات کی نگاہ حالاتِ جدیدہ پر ہے، وہ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ دورِ جدید میں یہ دراصل ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کی پشت پر بڑی خطرناک ذہنیت کام کر رہی ہے۔
تاریخ کا ہر طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ کثرتِ آبادی کی بڑی سیاسی اہمیت ہے۔ ہرتہذیب نے اپنے تعمیری اور تشکیلی دور میں آبادی کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ مشہور مؤرخ وِل ڈورانٹ (Will Durrant) نے اسے تہذیبی ترقی کا ایک بڑا اہم سبب قرار دیا ہے۔ ٹائن بی (Toynbee) بھی کثرتِ آبادی کو ان چیلنجوں میں سے ایک قرار دیتا ہے جو تہذیب کے ارتقاء کا باعث ہوتے ہیں۔ تاریخ کی ان تمام اقوام نے، جنھوں نے کوئی عظیم کارنامہ انجام دیا ہے ہمیشہ تکثیر آبادی ہی کی پالیسی اختیار کی ہے۔ اس کے برعکس زوال پذیر تہذیبوں میں آبادی کی قلّت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور آبادی کی قلّت بالآخر اجتماعی قوت کے اضمحلال پر منتج ہوتی ہے۔ اور وہ قوم جو اس حالت میں مبتلا ہوجائے، آہستہ آہستہ گمنامی کے غار میں گر جاتی ہے۔ تہذیب کے جتنے بھی قدیم مراکز ہیں، ان تمام کی تاریخ کے مطالعے سے یہی حقیقت سامنے آتی ہے۔ خود اسلامی تاریخ میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ بھی وہی تھا جب ان کی قوم میں نیا خون تیزی کے ساتھ شامل ہورہا تھا اور ان کی تعداد برابر بڑھ رہی تھی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ سب سے سچے انسان (فداہٗ ابی و امّی) نے فرمایا تھا کہ ’’ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی اور بچّے جننے والی ہو‘‘۔
اور خود ہمارے زمانے میں بھی جرمنی اور اٹلی اسی پالیسی پر عامل رہے ہیں، اور روس اور چین آج بھی اس پر شدت سے عمل کر رہے ہیں۔ وہ آبادی کو اپنا قومی اثاثہ سمجھتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی سیاسی سطوت تعمیر کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ تاریخ کا بے لاگ فتویٰ ہے کہ آبادی اور سیاسی قوت و اقتدار ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ ایک تہذیب کے تعمیروترقی کے دور میں آبادی بڑھتی ہے اور اس کے انحطاط کے زمانے میں آبادی میں کمی آتی ہے۔فطرت کا یہی قانون جدید مغرب میں بھی اپنا عمل دکھا رہا ہے۔
دُنیا میں آبادی کی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ ایشیا اور عالمِ اسلام آبادی کے سب سے بڑے مراکز ہیں۔ ان ممالک کے مقابلے میں مغربی ممالک کی آبادی نمایاں طور پر کم ہے۔ گذشتہ پانچ سو برسوں میں مغرب کی سیاسی قیادت و بالادستی کی بنیاد وہ سائنسی اور میکانیکی فوقیت تھی جو اسے مشرقی ممالک پر حاصل تھی، اور جس کی وجہ سے اس نے آبادی کی کمی کے باوجود سیاسی حکمرانی قائم کرلی، اور اس غلط فہمی کا شکار ہوگیا کہ اب آبادی کی اہمیت زیادہ نہیں ہے __ لیکن نئے حالات اور حقائق نے غلط فہمی کے اس طلسم کو چاک کردیا ہے۔
مغربی اقوام کی آبادی کے مسلسل کم ہونے سے ان کی سیاسی طاقت میں بھی انحطاط آنا شروع ہوا اور پہلی جنگ عظیم کے موقعے پر یہ احساس عام ہوگیا کہ تحدید آبادی کا مسلک سیاسی اور اجتماعی حیثیت سے بڑا مہنگا پڑ رہا ہے۔ فرانس نے اپنی عالمی پوزیشن آہستہ آہستہ کھودی اور مارشل پٹین نے اس امر کا اعتراف کیا کہ فرانس کے زوال کا ایک بڑا بنیادی سبب آبادی کی کمی ہے۔ برطانیہ کے متعلق سابق وزیراعظم ونسٹن چرچل کے صاحبزادے مسٹر رینڈ الف چرچل نے جو خود پارلیمنٹ کے ممبر اور ایک مشہور سیاسی مبصر اور صاحب ِ قلم ہیں۔ اس بات کا اظہار کیا کہ: ’’میں نہیں سمجھتا کہ ہماری قوم بالعموم اس خطرے سے آگاہ ہوچکی ہے کہ اگر ہماری شرح پیدائش اسی طرح گرتی رہی تو ایک صدی میں برطانیہ کی آبادی صرف ۴۰ لاکھ رہ جائے گی اور اتنی کم آبادی کے بل بوتے پر برطانیہ دُنیا میں ایک بڑی طاقت نہ رہ سکے گا‘‘۔
اس وجہ سے یورپ کی تقریباً تمام ہی اقوام نے اپنی پالیسی کو بدلا اور گذشتہ ۳۰ برس سے وہ آبادی کو بڑھانے کے مسلک پر عمل پیرا ہیں اور حکومت افزائش نسل کی ہرممکن حوصلہ افزائی کررہی ہے۔ فرانس نے اسقاطِ حمل اور تحدید نسل کی تمام کارروائیوں کو قانوناً ممنوع کیا۔ ہٹلر اور مسولینی کے تحت جرمنی اور اٹلی نے انھیں نہ صرف سخت ترین جرم قرار دیا بلکہ مثبت قانونی، معاشرتی اور معاشی تدابیر سے بچوں کی تعداد بڑھانے کی حوصلہ افزائی کی۔
سویڈن نے ایک سرکاری کمیشن مقرر کیا کہ وہ حالات کا جائزہ لے اور اس کمیشن کی سفارشات پر ’بڑے خاندان‘ کی پالیسی اختیار کی گئی۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے ٹیکس کی شرح کم کی گئی اور بے شمار دوسری مراعات بچوں کے لیے فراہم کی گئیں۔انگلستان کے وزیرداخلہ ہربرٹ موریسن نے ۱۹۴۳ء میں یہ ہدف قوم کے سامنے رکھا کہ ہر خاندان میں کم از کم ۲۵ فی صد کا اضافہ ہونا چاہیے۔ یہی پالیسی امریکا نے اختیار کی اور اس وقت مغربی دُنیا کے تمام ممالک یہی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں شرحِ پیدائش برابر بڑھ رہی ہے اور اس کا اندازہ مندرجہ ذیل اعداد و شمار سے ہوسکتا ہے:
اس وقت مغرب کی تمام ہی اقوام اپنی آبادی کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن یہ اضافہ مشرقی اقوام کی آبادی کے اضافہ کے مقابلے میں کم ہے۔ محض اس کے سہارے مغربی اقوام کو اپنا سیاسی اقتدار قائم رکھنا مشکل نظر آتا ہے۔ پھر وہ فنی، سائنسی اور تکنیکی معلومات جو آج تک مشرق پر مغرب کی بالادستی قائم رکھے ہوئے تھیں اور جن سے مشرقی ممالک کو بڑی کوشش کے بعد محروم رکھا گیا تھا، آج ان ممالک میں بھی عام ہورہی ہیں۔ چونکہ ان ممالک کی آبادی بھی مغربی ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے نئے مشینی آلات سے آراستہ ہونے کے بعد اقوام کے محکوم رہنے کا کوئی امکان نہیں، بلکہ فطری قوانین کی وجہ سے اس انقلاب کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مغرب کی سیاسی قیادت کے دن گنتی کے رہ جائیں گے اور نئی عالمی قیادت ان مقامات سے اُبھرے گی جہاں آبادی بھی زیادہ ہے اور جو فنی اور تکنیکی مہارت رکھتے ہیں۔ ان حالات میں مغرب اپنی سیادت کو قائم رکھنے کے لیے ایک ایسا کھیل کھیل رہا ہے، جو فطرت کے قانون کے خلاف ہے اور جو خود اس کے لیے بھی طویل عرصے میں نقصان دہ ثابت ہوگا، یعنی مشرقی ممالک میں تحدید نسل اور ضبط ِ ولادت کے ذریعے آبادی کو کم کرنے کی کوشش اور فنی معلومات کی ترویج میں رخنہ اندازی___ ہم یہ بات کسی تعصب کی بنا پر نہیں کہہ رہے بلکہ ہم خود مغربی ذرائع ہی سے اسے ثابت کرسکتے ہیں۔ مغرب میں آبادی کے مسئلے پر بیسیوں کتابیں ایسی آئی ہیں، جو آبادی کی کمی کے سیاسی اثرات کو واضح کررہی ہیں اور جن کے اثر کے طور پر خود حکومتی پالیسی میں تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ سارا لٹریچر ہمارے دعوے کے لیے ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح پروفیسر فرینک نوٹینسن ٹین مشہور امریکی رسالے Foreign Affairs میں لکھتے ہیں:
اب اس کا کوئی امکان نہیں کہ شمالی مغربی یا وسطی یورپ کی کوئی قوم دُنیا کو چیلنج کرسکے۔ جرمنی دوسری یورپی اقوام کی طرح اس دور سے گزر چکا ہے جب وہ دُنیا کی غالب طاقت بن سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب فنی اور تکنیکی تہذیب ان ممالک میں بھی پہنچ گئی ہے، جن کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ (اپریل ۱۹۴۴ء)
دراصل یورپ کی سیاسی قیادت کو بیسویں صدی کے دوسرے نصف میں ایشیا اور عالمِ اسلام کی بڑھتی ہوئی آبادی سے شدید خطرہ ہے۔ امریکی رسالہ ٹائم اپنی ۱۱جنوری ۱۹۶۰ء کی اشاعت میں لکھتا ہے:
کثرتِ آبادی (Over-Population) کے متعلق امریکا اور یورپی اقوام کی بوکھلاہٹ اور ان کے تمام وعظ و نصیحت بڑی حد تک بے نتیجہ ہیں۔ اُن سیاسی نتائج و اثرات کے احساس کا جو نئے حالات اور ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکا کی آبادی کے بڑھنے اور غالب اکثریت حاصل کرلینے کی بناپر متوقع ہیں۔
یعنی مستقبل میں غالب قوت ان ممالک کو حاصل ہوگی، جن کی آبادی زیادہ ہے اور جو نئی تکنیک سے بھی آراستہ ہیں۔ اب اس کا تو کوئی امکان نہیں کہ نئی تکنیک سے ان ممالک کو مزید محروم رکھا جائے۔ اس لیے مغربی سیادت و قیادت کو قائم رکھنے والی صرف ایک چیز ہوسکتی ہے اور وہ ہے ان ممالک میں تحدید نسل اور ضبط ِ ولادت! یہی وجہ ہے کہ تمام مغربی ممالک، مشرقی ممالک میں پروپیگنڈا کی بہترین قوتوں سے مسلح ہوکر یہاں ضبط ولادت کی تحریک کو ترقی دے رہے ہیں اور سادہ لوح مسلمان اس چال میں خود پیش قدمی کرکے پھنس رہے ہیں: ؎
مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار
انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات!
لیکن اب بلی تھیلے سے باہر آچکی ہے۔ اگر اب ہم نے دھوکا کھایا تو پھر کل ہمارا کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوگا، اور ہمارے جو ’ہمدرد‘ آج پوری شفقت کے ساتھ ہمیں خاندانی منصوبہ بندی کا درس دے رہے ہیں، کل یہی ہماری کمزوری سے فائدہ اُٹھا کر ہم پر اپنا تسلط قائم کریں گے اور ہم اُف بھی نہ کرسکیں گے۔ اسی خطرے کو حکیم الامت علّامہ اقبال نے بہت پہلے محسوس کرلیا تھا اور قوم کو تنبیہہ کی تھی کہ اس سے ہوشیار رہے ۔ ان کے یہ الفاظ آج بھی ہمیں دعوتِ فکر وعمل دے رہے ہیں:
عام طور پر اب ہندستان میں جو کچھ ہورہا ہے یا ہونے والا ہے، وہ سب یورپ کے پروپیگنڈے کے اثرات ہیں۔ اس قسم کے لٹریچر کا ایک سیلاب ہے جو ہمارے ملک میں بہہ نکلا ہے۔ بعض دوسرے وسائل بھی ان کی تشویق و ترویج کے لیے اختیار کیے جارہے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے ممالک میں آبادی کو گھٹانے کے بجائے بڑھانے کے وسائل اور تدابیر اختیار کی جارہی ہیں۔ اس تحریک کی ایک بڑی غرض میرے نزدیک یہ ہے کہ یورپ کی اپنی آبادی، اس کے اپنے پیدا کردہ حالات کی بناپر جو اس کے اختیار و اقتدار سے باہر ہیں، بہت کم ہورہی ہے اور اس کے مقابلے میں مشرق کی آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے اور اس چیز کو یورپ اپنی سیاسی ہستی کے لیے خطرئہ عظیم سمجھتا ہے۔(رسالہ الحکیم، لاہور، ماہ نومبر ۱۹۳۶ء، بحوالہ ہمدرد صحت ، دہلی، جولائی ۱۹۳۹ء، ص ۱۸۲)
یہ ہے اس مسئلے کی اصل حقیقت! پھر ہمارے ملک کے لیے تو کچھ خاص حالات کی بنا پر آبادی کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیٹھ دفاعی نقطۂ نظر سے ہماری حیثیت بتیس دانتوں کے درمیان ایک زبان کی سی ہے۔ ایک طرف ہندستان ہے جس کی آبادی ہم سے چارگنا زیادہ ہے۔ دوسری طرف روس ہے جس کی آبادی ہم سے تین گنا زیادہ ہے، اور تیسری طرف چین ہے جس کی آبادی ہم سے آٹھ گنا زیادہ ہے اور تینوں کی نگاہیں ہمارے اُوپر لگی ہوئی ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے دفاع کا حقیقی تقاضا کیا ہے؟ آیا یہ کہ ہم آبادی کو کم کرکے اپنی قوت کو اور بھی مضمحل کرلیں یا ہرممکن ذریعے سے اپنے کو اتنا قوی اور مؤثر بنالیں کہ کوئی دوسرا ہماری طرف بُری نگاہ ڈالنے کی ہمت بھی نہ کرسکے۔
اگر یہ کہا جائے کہ آج کی جنگ میں انسان کے مقابلے میں آلات زیادہ اہم ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ایٹمی ترقیات کے بعد پھر انسان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ آخر اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ کوریا کی جنگ میں چین نے محض اپنی عدد ی کثرت کی وجہ سے امریکا کے بہترین ہتھیاروں کو بھی بے اثر کردکھایا تھا۔ اس لیے آج آبادی کی دفاعی اہمیت کا ایک نیا احساس پیدا ہوگیا ہے اور عالمِ اسلام کو محض آنکھیں بند کرکے مغرب کی نقالی میں کوئی ایسی روش اختیار نہ کرنی چاہیے، جو اس کے لیے ملی خودکشی کے مترادف ہو۔
آبادی کی یہ دفاعی اہمیت صرف پاکستان ہی کے لیے نہیں ہے، عرب دُنیا کے لیے بھی اس کی اہمیت کچھ کم نہیں۔ وہاں اسرائیل اپنی آبادی کو بڑھانے کی پالیسی پر عامل ہے اور اس کے مقابلے کے لیے پورے عالم اسلام کو تیار ہونا ہے۔ اسی طرح مغربی دُنیا اور اشتراکی دُنیا میں جو کش مکش جاری ہے، اس میں بھی عالمِ اسلام کا ایک مرکزی رول ہے۔ اگر یہاں کی آبادی برابر کم ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کمیونسٹ ممالک کے علاوہ کسی کو نہ پہنچے گا۔ یہاں کی آبادی کی تحدید کرکے مغربی اقوام ایک موہوم منفعت عاجلہ کے لیے ایک حقیقی خطرہ مول لے رہی ہیں، جو خود ان کی دفاعی لائن کو بڑا کمزور کردے گا۔
ہماری اس بحث سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ آج آبادی کا مسئلہ اصلاً ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور اسے پوری سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ حل کرنا چاہیے، اور وہ مسلک اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم اور پورا عالم اسلام نہ صرف اپنی آزادی کو قائم رکھ سکیں بلکہ بین الاقوامی اُمور میں اپنا صحیح کردار اداکرنے لگیں۔ ہمیں پرائے شگون پر اپنی ناک کٹانے کی حماقت ہرگز نہ کرنی چاہیے۔
آبادی کے مسئلے کی سیاسی نوعیت کو ہم نے اُوپر واضح کر دیا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس بڑی بنیادی غلط فہمی کو بھی دُور کیا جائے، جس کا راگ ضبط ِ ولادت کے مؤیدین صبح و شام الاپتے ہیں، یعنی ’یہ اصل مسئلہ معاشی ہے اور پیداوار کی قلت کا واحد حل تحدید نسل ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو زمین پر تل دھرنے کی جگہ نہ رہے گی اور سخت تباہی مچے گی‘۔ یہ استدلال بھی اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور اس کی حیثیت محض پروپیگنڈے سے زیادہ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات گویبلز کے اس اصول پر کام کر رہے ہیں کہ ’’ایک جھوٹ کو اس کثرت سے نشر کرو کہ دُنیا اس کو سچ جان لے‘‘۔
یورپ میں تحدید نسل کی تحریک کا آغاز انیسویں صدی میں ہوا۔ مالتھس نے آبادی کا معاشی پہلو واضح کیا تھا لیکن تحدید نسل کا کوئی پروگرام اس کے لیے پیش نہ کیا۔ انگلستان میں سب سے پہلے فرانسس پیلس نے ۱۸۲۲ء میں ایک کتاب آبادی کے مسئلہ کی تفصیلات اور اس کے ثبوت لکھی۔ اور فرانسس پیلس، جان اسٹورٹ مل اور ٹی جے وولر نے اس تحریک میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ اس زمانے (۱۸۲۵ء) میں ایک کتاب محبت کیا ہے؟ لکھی گئی، جس کا مصنف رچرڈ کارلائل تھا۔ (اسے مشہور مؤرخ تھامس کارلائل نہ سمجھا جائے)اور اس نے بڑی بے باکی اور بے غیرتی کے ساتھ ضبط تولید کے ذریعے آسان اور بے ضرر محبت کا نظریہ پیش کیا۔
انگلستان میں یہ تحریک آٹھ دس سال تک بڑے زوروشور سے چلی، لیکن ابھی اخلاقی قدریں اتنی بے وزن نہیں ہوئی تھیں کہ یہ تحریک پائوں جماسکتی،اس لیے حباب کے مانند اُبھری اور دب گئی۔ یہ تحریک انیسویں صدی کے ربع آخر میں دوبارہ اُبھری۔ اب اس نے باقاعدہ ایک تنظیم کی شکل بھی اختیار کرلی۔ انگلستان میں مالتھوسین لیگ (Malthusean League) قائم ہوئی اور یورپ کے دوسرے ممالک میں ایسی ہی تنظیمیں قائم ہونے لگیں۔ ۱۸۷۶ء میںچارلس بریڈلا (Charles Bredlaugh) اور مسٹر اینی بسنٹ (Annie Basant) نے یہ ’جہاد‘ شروع کیا اور جلدہی اس تحریک کو مقبولیت حاصل ہوئی، خصوصیت سے طبی حلقوں نے اس کی بڑی رہنمائی کی اور ڈاکٹرڈریسڈیل اور ان کی اہلیہ نے تو اس مہم میں اپنی جان ہی کھپادی۔
امریکا میں رابرٹ ڈیل اووین نے ۱۸۳۰ء میں ایک کتاب Moral Physialogy (اخلاقی افعال الاعضاء) لکھی۔ ۱۸۳۲ء میں ڈاکٹر چارلس ناولٹن نے Fruits of Philosphy (ثمراتِ فلسفہ) کے نام سے ضبط ِ تولید کے نظریات کو پیش کیا اور آزاد خیالی کا سہارا لے کر اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر ناولٹن کا تعلق طبّی پیشے سے تھا، لیکن اس کی کتاب مبلغانہ انداز میں لکھی گئی۔ ان تحریرات نے فضا کو اس تحریک کے لیے سازگار بنایا، لیکن باقاعدہ تنظیم بند ی کا آغاز بیسویں صدی میں ہوا، جب کہ اس تحریک کی سب سے سرگرم کارکن مسز مارگریٹ سنیگر نے [مارچ ۱۹۱۴ء میں] The Woman Rebel (باغی عورت )کے نام سے ایک رسالہ نکالا [جس کا نعرہ تھا: No Gods, No Masters]۔ ۱۹۲۱ء میں ایک ملکی کانفرنس کی اور بالآخر ’برتھ کنٹرول لیگ‘ قائم کی۔ ۱۹۲۳ء سے کلینک بھی قائم ہونا شروع ہوئے اور ۱۹۳۹ء میں پورے ملک کی ضبط ِ تولید کی تنظیموں کی فیڈریشن قائم ہوئی۔ ۱۹۴۳ء میں اس فیڈریشن کا نام بدل کر Planned Parenthood Federation of America کردیا گیا اور جب ہی سے ضبط ِ تولید کی جگہ ’خاندانی منصوبہ بندی‘ کا زیادہ ’معصوم‘ نام مستعمل ہونے لگا۔
اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مغربی ممالک میں یہ تحریک وسط انیسویں صدی سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ تمام یورپ اور امریکا میں پھیل گئی، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ان ممالک میں پیداوار کی قلّت تھی؟ کیا رفتار پیداوار سُست تھی؟ کیا فی کس آمدنی برابر گر رہی تھی؟___ اس لیے کہ اگر یہ تحریک معاشی وجوہ کی بناپر اختیار کی گئی تھی تو ان سوالات کا جواب اثبات میں ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس زمانے میں ان تمام ممالک میں دولت کی ریل پیل تھی۔ پیداوار بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ صنعتی انقلاب اور اس کے تضمنات کی وجہ سے قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہورہا تھا ، اور ہرحیثیت سے خوش حالی کا دور دورہ تھا۔ مثال کے طور پر انگلستان میں ۱۸۳۸ء-۱۸۶۰ء کے درمیان فی کس آمدنی میں ۲۳۱فی صد کا اضافہ ہوا تھا اور عام خوش حالی کا معیار بلند ترین تھا۔ ۱۸۴۰ء اور ۱۸۸۶ء میں فی کس صرفہ (Per Capita Consumption) میں بھی نمایاں فرق ہوا، جس کا اندازہ مندرجہ ذیل جدول سے ہوسکتا ہے:
یہ جدول عام خوش حالی کوظاہر کرتا ہے ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دولت بڑھ رہی تھی، پیداوار میں اضافہ ہورہا تھا ، اُجرت بھی روز افزوں تھی اور عام خوش حالی کا معیار بھی بلندتر ہورہا تھا تو پھر تحدید نسل کی معاشی ضرورت کہاں پائی جاتی تھی؟
یہی حال امریکا کا ہے۔ امریکا میں ۱۸۰۹ء- ۱۹۲۹ء کے درمیان کل ملکی دولت ۷؍ارب ڈالر سے بڑھ کر ۷۹۵؍ ارب ڈالر پر پہنچ گئی تھی۔ اگر آبادی کے اضافے کو بھی شامل کرلیا جائے تو فی کس آمدنی (Per Capita Income) اس زمانے میں ۱۳۱ ڈالر سے بڑھ کر ۶۵۴ ڈالر ہوگئی تھی، یعنی یہاں بھی تقریباً ۵۰۰ فی صد کا اضافہ ہوا۔ ایسی حالت میں ضبط ِ تولید کی آخر کون سی معاشی وجوہ موجود تھیں؟
اگر یورپ اور امریکا کی معاشی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ غلط فہمی بالکل دُور ہوجاتی ہے کہ اس تحریک کی معاشی بنیادیں بھی تھیں۔ دراصل معاشی دلائل کی حیثیت محض ہاتھی کے ظاہری دانتوں کی سی تھی جن کی کوئی حقیقی اور عملی اہمیت نہ تھی اور جنھیں صرف فضا کو سازگار کرنے اور کم علم لوگوں کو بہکانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور یہی صورت آج بھی ہے۔ مشہور انگریز معاشی مفکر پروفیسر کولن کلارک (Colin Clark)نے اس سلسلے میں بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ’’آبادی کو ہّوا بناکر پیش کرنے والے محض پروپیگنڈا باز(Propagandist) ہیں اور ان کے ذہنوں کی تہ میں ’مخالف مذہب‘ مفروضات موجود ہیں‘‘۔
یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نقطۂ نظر ساینٹی فک ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ شاید صفحۂ ہستی پر سائنس دانوں کا ایسا کوئی اور گروہ موجود نہیں جس کی معلومات ان حقائق کے متعلق جن سے ان کا سابقہ ہے، اس درجہ غلط ہو۔بہت سے مالتھوسنیوں کو تو آبادی کے متعلق بنیادی حقائق کی عام معلومات تک نہیں ہیں اور جو آبادی کی شماریات میں کچھ شُدبُد رکھتے ہیں وہ بھی سب کے سب بلاشبہ معاشی فکر سے بالکل نابلد ہیں۔ (Colin Clark, Population growth and hiving .....)
آج بھی دُنیا کے معاشی وسائل بے انتہا ہیں اور نہ صرف موجودہ آبادی بلکہ اس سے ۱۰گنا آبادی تو صرف معلوم وسائل کے ذریعے مغربی ممالک کے اعلیٰ معیار پر زندگی گزار سکتی ہے۔ یہی حالت خود ہمارے اپنے ملک کی ہے، جہاں دولت کے خزانے خوابیدہ پڑے ہیں۔ ان ہاتھوں کا انتظار کر رہے ہیں جو انھیں بیدار کرسکیں۔
]اس موضوع پر اسلام اور ضبط ِ ولادت از مولانا مودودی شائع ہوچکی ہے۔ اصل کتاب کے تازہ ایڈیشن میں اضافوں کے لیے مَیں نے مولانا محترم کی معاونت کی تھی اور پھر خود انھوں نے اس کتاب میں میرا ایک مضمون جس میں تفصیل سے اس پہلو کا جائزہ لیا گیا ہے، کتاب کے ضمیمے کے طورپر شاملِ اشاعت کیا ہے۔جو حضرات اس مسئلے پر مغربی مصنّفین کو پڑھنا چاہیں وہ J.D Barned کی کتابWorld Without War (۱۹۵۸ء) اور ڈڈلی سٹامپ کی کتاب Our Developing World (۱۹۶۰ء)کامطالعہ کریں۔[اسی طرح ایلن وائزمین کی کتاب The World Without Us (۲۰۰۷ء) بھی اسی موضوع پر ہے۔]
ضبط ِ تولید کے سلسلے میں ایک بات مزید سامنے رکھنی چاہیے کہ خاص حالات میں انفرادی طور پر اسے اختیار کرنے اور اسے ملک و قوم کی عام پالیسی بنالینے میں بڑا فرق ہے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ صحت یا دوسرے معقول وجوہ کی بناء پر ایک شخص کبھی اس قسم کا کوئی ذریعہ اختیار کرے، لیکن اس رویّے کو ملک کی عام پالیسی بنا دینا ، دینی، اخلاقی اور معاشی ہرحیثیت سے مہلک ہوگا۔
اس موضوع پر مسلمان اہل علم اور اہل قلم نے قوم کی ہرمرحلے پر رہنمائی کی ہے اور ہمارے اپنے زمانے میں مولانا سیّدابوالاعلیٰ مودودی کا مقالہ اسلام اور ضبطِ ولادت بڑے معرکے کی چیز ہے۔اس بات کی ضرورت تھی کہ نئے حالات اور نئے مسائل کے مطابق اس مسئلے پر اَزسرنو بحث کی جائے اور مجھے خوشی ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع کے ہونہار اور نوعمر فرزند عزیزی میاں محمد تقی سلمہٗ نے اس موضوع پر قلم اُٹھایا ہے اور شرعی اور عقلی ہر پہلو سے اس پر سیرحاصل بحث کی ہے۔ ان کا یہ مقالہ ہرحیثیت سے جامع ہے اور ان کی نوعمری کے پیش نظر تو ایک شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انھیں اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقالہ میں جو نقطۂ نظر پیش کیا گیا ہے اسے قبولیت ِ عامہ بخشے۔ وما توفیقی اِلَّا باللہ۔
۱- نیو کوئنس روڈ خورشیداحمد
کراچی ۴؍جنوری ۱۹۶۱ء
پاکستان کی معیشت کو بدستور سنگین خطرات اور چیلنجوں کا سامنا ہے۔حکومت بہرحال معاشی استحکام لانے اور معیشت کو بہتری کی طرف گامزن کرنے کے دعوے تواتر سے کرتی رہی ہے۔یہ بات صحیح ہے کہ آئی ایم ایف کے قرضے کی قسط حاصل کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، ان کے نتیجے میں معیشت میں عارضی استحکام یقیناًنظر آرہا ہے۔ تاہم، ہر محب وطن پاکستانی کے لیے یہ امر باعث تشویش ہونا چاہیے کہ یہ عارضی معاشی استحکام دراصل ملک کی معیشت، کروڑوں عوام اور قومی سلامتی کی قیمت پرحاصل کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی نظر آرہی ہے کہ آئی ایم ایف کے قرضے کے موجودہ پروگرام کے دوران معیشت لڑکھڑاتی رہے گی اور پاکستان کے گردگھیرا مزید تنگ کرنے کے لیے خدانخواستہ ۲۰۲۷ءکے بعد بھی پاکستان ایک مرتبہ پھر۲۵ویں پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے دستِ سوال دراز کرے گا۔ حکومت کے ان دعوؤں کی کوئی حیثیت نہیں کہ آئی ایم ایف کا قرضے کا موجودہ پروگرام پاکستان کا آخری پروگرام ہوگا۔
ملکی و بیرونی اشرافیہ کے گٹھ جوڑ،وڈیرہ شاہی کلچر پر مبنی پالیسیاں یا اقدامات، بڑھتی ہوئی مالیاتی وانٹی لیکچویل (ذہنی) بدعنوانی سے معیشت وقومی سلامتی کو جو سنگین خطرات اور چیلنج درپیش ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:
پاکستان میں ٹیکسوں کا نظام غیر منصفانہ اور استحصالی ہے۔ یہ نظام طاقتور طبقوں کو ٹیکسوں میں چھوٹ اور مراعات دیتا ہے، ٹیکس چوری ہونے دیتا ہے، معیشت کو دستاویزی بنانے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، کالے دھن کی پیداوار کو روکنے کے بجائے کالے دھن کو سفید بنانے کے راستے کھلے رکھتا ہے، اور ایک مقررہ رقم سے زائد ہر قسم کی آمدنی پر مؤثر طور سے ٹیکس عائد کرنے کے بجائے اُونچی شرح سے ’جنرل سیلز ٹیکس‘ نافذ کرتا ہے، جس کا بوجھ براہِ راست عوام پر ہی پڑتا ہے۔ یہی نہیں، عوام کے ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی رقوم کا صحیح استعمال بھی نہیں ہوتا اور ان رقوم کا بڑا حصہ حکومت اور حکومتی اداروں کی شاہ خرچیوں، قرضوں پر سود کی ادائیگیوں اور کرپشن کی نذر ہوجاتا ہے۔ چنانچہ کئی ہزار ارب روپے سالانہ ٹیکس دینے والے عوام کو ان کی ادا کردہ رقوم سے عملاً کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا۔
اس ضمن میں کچھ حقائق پیش ہیں:
۱- ہماری تحقیق کے مطابق موجودہ مالی سال میں وفاق اور صوبائی حکومتیں مجموعی طور پر ٹیکسوں کی مد میں حقیقی استعداد کے مقابلے میں تقریباً ۲۳ہزار ارب روپے کم وصول کریں گی، یعنی تقریباً ۱۹۰۰؍ ارب روپے ماہانہ کی کم وصولی۔ اس کم وصولی کے بڑے حصے کو ٹیکسوں کے منصفانہ نظام کے تحت وصول کیے بغیر معیشت کی بحالی اور تعلیم، صحت اور انسانی وسائل کی ترقی کے لیے خاطر خواہ رقوم مختص کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اب وقت آگیا ہے کہ وفاق اور صوبے۱۰ لاکھ روپے سالانہ سے زائد ہر قسم کی آمدنی پر بلا کسی چھوٹ، مؤثر طور سے ٹیکس نافذ اور وصول کریں اور ساتھ ہی جنرل سیلزٹیکس کی شرح بھی مرحلہ وار ۷ء۵ فی صد پر لے آئیں،ماسوائے ان اشیاء کے جو لگژری کے زمرے میں آتی ہیں۔
بدقسمتی سے وفاق، صوبے اور اشرافیہ ان اصلاحات کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور نہ اس ضمن میں کسی سیاسی، دینی یا مذہبی جماعت کا کوئی مطالبہ سامنے آیا ہے کیونکہ کوئی بھی طاقتور اشرافیہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، خصوصاً وہ جماعتیں جو ان سے ووٹ اور نوٹ لینے کی خواہش رکھتی ہیں، انتخابات جیتنےکے لیےان کی مدد ضروری سمجھتی ہیں یا ان سے چندہ وغیرہ وصول کرتی ہیں۔
۲- معیشت کو دستاویزی بنانے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں نقد کاروبار عروج پر ہے ۔ تخمینہ ہے کہ کالے دھن کا حجم تقریباً ۷۰ ہزار ارب روپے ہے۔
۳- پاکستان میں پراپرٹی سیکٹر میں کئی ہزار ارب روپے کا کالا دھن لگا ہوا ہے۔ ان رقوم میں ٹیکس کی چوری اور کرپشن وغیرہ سے حاصل کی ہوئی رقوم بھی شامل ہیں۔پراپرٹی کی مالیت مارکیٹ کے نرخوں کے برابر لانے کے لیے نہ وفاقی حکومت تیار ہے اور نہ صوبائی حکومتیں۔ چنانچہ اس سیکٹر سے ٹیکسوں کی وصولی بہت کم ہورہی ہے۔
ہماری تجویز یہی ہے کہ ۱۵ملین روپے سے زائد ہر جائیداد کی فروخت کے اخبار میں شائع شدہ اعلان کے بعد ہر پاکستانی شخص کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ ۱۵ فی صد زیادہ قیمت کی پیش کش کرکے جائیداد کو خرید سکے۔ اس طرح یہ سودے بڑی حد تک مارکیٹ کے نرخوںپر ہوسکیں گے۔
پاکستان میں حکومتیں اور سیاسی پارٹیاں وقتاً فوقتاًملک سے لوٹ کر بیرونی ملکوں میں منتقل کی گئی خطیر رقم پاکستان واپس لا کر عوام کی فلاح وبہبود پر خرچ کرنے کے بارے میںسیاسی بیانات دیتی رہی ہیںچونکہ وہ سب اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ مختلف وجوہ کی بنا پر اب اس ضمن میں کامیابی کا امکان بہت ہی کم ہے۔یہ حقیقت بھی اپنی جگہ برقرار ہے کہ ٹیکس حکام سے خفیہ رکھےہوئے کئی ہزار ارب روپےکے ایسے اثاثے ملک کے اندر موجود ہیں، جن کی تفصیلات بہرحال ریکارڈ میں محفوظ ہیں۔
ہم برس ہا برس سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے حکومتوں کی توجہ اس طرف دلاتے رہے ہیںلیکن یہ ملکی اشرافیہ کے گٹھ جوڑ ہی کا کمال ہے کہ سیاسی، مذہبی، رفاہی، صحافتی اور اصلاحی قوتوں میں سے کوئی بھی ان کی ناراضی مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
پاکستان میں زکوٰۃ ، خیرات اور چندہ کی رقوم میں بڑے پیمانے پر غلط کاریاں ہوتی رہی ہیں۔ مختلف ادارے یہ مہم زور شور سے چلاتے رہے ہیں کہ زکوٰۃو خیرات وغیرہ کی رقوم ان کو دی جائیں تاکہ وہ مستحقین تک پہنچاسکیں۔ اسلام میں اجتماعیت کا تصور ہے۔ ارشادِربانی ہے: ’’ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کرکے ان کو پاک و صاف کردو‘‘(التوبہ ۹:۱۰۳)۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپؐ ان سے زکوٰۃ وصول کریں یعنی مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ زکوٰۃ کی رقوم کو الگ الگ خرچ کریں۔ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاحب ِنصاب مسلمانوں بشمول اداروں سے زکوٰۃ وصول کرے اوران رقوم کو مستحقین تک پہنچانے کا ایک باقاعدہ نظام بھی وضع کرے۔ ان قرآنی احکامات کے باوجود کوئی بھی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت، معاشرے کی اصلاح کرکے بیت المال کے نظام کا شفاف ڈھانچا قائم کرنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دے۔ پاکستان میں جو سماجی ادارے ’رجسٹرڈ این پی اوز‘ (منافع نہ کمانے والے سماجی ادارے)ہیں،ان کی تعداد ۴۵۰۹ ہے مگر صرف ۲۷۷۶؍ ادارے انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کراتے ہیں۔ اس سے زکوٰۃ،خیرات اور چندہ وغیرہ کی وصولی اور ان رقوم کی تقسیم وغیرہ کے ضمن میں متعدد شبہات جنم لیتے رہے ہیں۔ ان امور کی طرف سنجیدگی سے توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔
یہ ملک و قوم کی بدقسمتی ہے کہ برآمدات بڑھانے کے بجائے حکومتوں نے یہ پالیسی اختیار کیے رکھی ہے کہ انکم ٹیکس آرڈنینس کی شق ۱۱۱(۴) کے تحت کارکنوں کی ’ترسیلات‘ (Remittances) کے نام پر بڑی بڑی رقوم کی ’ترسیلات‘ پاکستان آنے دی جائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ :
۱- لوگ قومی خزانے میں ایک پیسہ جمع کرائے بغیراپنا کالادھن سفید کراسکیں۔
۲- غیر ضروری درآمدات کی وجہ سے پیدا ہونے والے تجارتی خسارے کے جھٹکے کو سنبھالنے کے لیے زرمبادلہ کی رقوم حاصل ہوسکیں۔
مالی سال۲۰۱۹ءسے مالی سال ۲۰۲۴ءکے ۶ برسوں کے یہ اعداد و شمار چشم کشا ہیں:
۱- ملک کی مجموعی درآمدات کا حجم ۳۴۶؍ ارب ڈالر
۲- ملک کی مجموعی برآمدات کا حجم ۱۶۱؍ ارب ڈالر
۳- ملک کے تجارتی خسارے کامجموعی حجم ۱۸۵؍ارب ڈالر
۴- ملک میںآنے والی ترسیلات کا مجموعی حجم ۱۶۳؍ارب ڈالر
۵- ملک کے جاری حسابات کے خسارے کا مجموعی حجم ۴۲؍ارب ڈالر
پاکستان میں مختلف حکومتیں بڑی چابک دستی سے جاری حسابات کے خسارے کے کم ہونے یا جاری حسابات کے عارضی طور پر فاضل ہونے پر کامیابیوں کی دعوے کرتی ہیں، جوعملاً پاکستان کے مخصوص حالات میں سفاکانہ خود فریبی کے مترادف ہے۔ حالانکہ پاکستان کو درپیش معاشی چیلنج یہ ہے کہ اپنے تجارتی خسارے کو کم کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ(ن )کے منشور میں کہا گیا تھا ’’سمندر پار پاکستانیوں کی آنے والی ترسیلات کا کم از کم ۵۰ فی صد سرمایہ کاری میں تبدیل کریں گے‘‘۔ اگر گذشتہ چھ برسوں میں ۱۶۳؍ارب ڈالر کی ترسیلات کا ۵۰فی صد ملکی سرمایہ کاری میں منتقل کردیا جاتا تو یقینا پاکستان کی قسمت بدل جاتی، مگر بدقسمتی سے ترسیلات کی رقوم، تجارتی خسارے کو سنبھالنے کے لیے استعمال کی جارہی ہیں جو کہ تباہی کا نسخہ ہے۔
ہماری تجویز ہے کہ کسی شخص کو اگر ایک مالی سال میں ۱۰ہزار ڈالر سالانہ سے زیادہ کی رقوم کی ترسیلات وصول ہوں، تو ان ترسیلات پر ملکی قوانین کے تحت انکم ٹیکس نافذ اور وصول کیا جائے۔ ہم یہ بھی تجویز کریں گے کہ انکم ٹیکس آرڈنینس کی شق ۱۱۱(۴)کو منسوخ کردیا جائے۔ جس کے نتیجے میں حکومت برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوگی اور ٹیکسوں کی وصولی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ ان اضافی رقوم کو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔ موجودہ سال میں پاکستان کی ترسیلات ۳۵؍ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہیں، جب کہ برآمدات تقریباً ۳۲؍ارب ڈالر تک رہیں گی۔ یہ تخمینے حکومت کی غلط ترجیحات کی واضح مثال ہیں۔
کرپشن کا ناسور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلاکررہا ہے۔ یہ ایک محتاط تخمینہ ہے کہ کرپشن، بدانتظامی، نااہلی، بدعنوان ونااہل افراد کی حکومتی اداروں میں تقرریوںو ترقیوں ، قواعدو ضوابط کو نظرانداز کرنے، شاہانہ اخراجات کرتے چلے جانے اور وفاق اور صوبوںکی جانب سے ٹیکسوں کی استعداد سے کم از کم۲۳ہزار ارب روپے سالانہ کی کم وصولی سمیت، قومی خزانے کومجموعی طور پر تقریباً ۳۴ہزار ارب روپے سالانہ کا نقصان ہورہا ہے، یعنی تقریباً۲۸۸؍ارب روپے ماہانہ۔ اس نقصان کے صرف ۲۵ فی صدپر قابو پانے سے پاکستان کی معیشت میں اتنی بہتری آسکتی ہے جس کا فوری طور پر تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، مگر اشرافیہ کے ناجائزمفادات کے تحفظ کے لیے کوئی بھی حکومت اس ضمن میں سیاسی عزم نہیں رکھتی۔اس صورتِ حال میں اسلامی نظام معیشت و بنکاری شریعت کی روح کے مطابق نافذ ہوہی نہیں سکتا۔
گذشتہ تقریباً ۳۲برسوں سے ملک میں رہائش پذیر پاکستانی اپنی ناجائز اور جائز رقوم سے کھلی منڈی سے بڑے پیمانے پر ڈالر خرید کرپاکستان میں کام کرنے والے بنکوں میں یہ رقوم اپنے بیرونی کرنسی کے کھاتوں میںجمع کراتے رہے ہیں۔ تخمینہ ہے کہ ملکی قوانین کے تحت ان کھاتوں میں جمع کرائی گئی رقوم میں سے تقریباً ۲۰۰؍ارب ڈالر بنکوں کے ذریعے پاکستان سے باہر بھجوائے گئے ہیں۔اس طرح ان کاکچھ کالادھن بھی سفید ہوگیا،جو بہرحال منی لانڈرنگ کی زمرے میں آتا ہے۔ پاکستان غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جہاںقومی خزانے میں ایک روپیہ جمع کرائے بغیر لوٹی ہوئی دولت کو قانونی تحفظ حاصل کرنا اب بھی ممکن ہے۔ گذشتہ برسوں میں حکومت نے ان کھاتوں کے ذریعے بیرونی کرنسی میں رقوم باہر منتقل کرنے پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں،مگر سرمائے کا فرار بدستور جاری ہے ۔بیرونی کرنسیوں کے کھاتوںکے ذریعے رقوم کی باہر منتقلی کے مندرجہ ذیل تخمینے چشم کشا ہیں:
۱- گذشتہ ۳۲برسوں میں کھلی منڈی سے ڈالر خرید کر بیرونی کرنسی کے کھاتوں کے ذریعے بیرونی ممالک میں رقوم کی منتقلی کا مجموعی حجم ۲۰۰؍ارب ڈالر
۲- آزادی کے تقریباً ۷۷برسوں کے بعد ۳۱دسمبر۲۰۲۴ءتک پاکستان پر بیرونی قرضوں اور ذمہ داریوں کامجموعی حجم ۱۳۱؍ ارب ڈالر
اس بات کا ادراک ضروری ہے کہ اگر تعلیم اور علاج معالجے وغیرہ کے علاوہ بیرونی کرنسیوں کے کھاتوں کے ذریعے مارکیٹ سے خریدے ہوئے ڈالرز کو باہر منتقل نہ ہونے دیا جائے، تو عملاً پاکستان پر بیرونی قرضہ ہوتا ہی نہیں اور پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آکر دانش مندانہ معاشی پالیسیاں بنانے کی پوزیشن میں آسکتا تھا۔ مگر حکومت اور اسٹیٹ بنک ان کھاتوں کے ذریعے تعلیم اور صحت کے علاوہ ملک سے باہررقوم کی منتقلی پر پابندی لگانے کے لیے تیارہی نہیں ہیں۔
گذشتہ تقریباً چھ برسوں میں پاکستان میں کام کرنے والے بنکوں نے اپنے سالانہ منافع میں جس تیز رفتاری سے اضافہ کیا ہے، اس کی پہلے کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ بنکوں کے منافع میں زبردست اضافے کی وجوہ میں مندرجہ ذیل عوامل بھی شامل ہیں:
۱- بنک نفع و نقصان میں شرکت کےکھاتے داروں کو اپنے منافع میں شریک نہیں کرتے رہے ہیں۔ اس طرح کروڑوں کھاتے داروں کو قانون توڑ کرکئی ہزار ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔
۲- بنکوں نے صنعت ، تجارت، زراعت اور برآمدات وغیرہ کے لیے قرضے کی فراہمی کو ثانوی حیثیت دے کر حکومتی تمسکات میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جہاں فی الحال نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔اس طرح پاکستان میں کرپشن کی پیداوار بجٹ خسارے کی مال کاری کو بنکوں نے اپنا فرض اولین بنا لیا ہے۔
۳- بنکوں نے بیرونی کرنسی میں سٹے بازی کی اور عملاً ڈالرائزیشن اور سرمائے کے فرار میں کردار ادا کیا۔
یہ بات حیرت انگیز ہے کہ۲۰۰۸ء کابنکوں کا ٹیکس سے قبل مجموعی منافع ۶۳؍ارب روپے تھا جو۲۰۱۸ء میں۲۴۲؍ارب روپے،۲۰۲۱ء میں۴۵۱؍ارب روپے، ۲۰۲۲ء میں۷۰۳؍ارب روپے اور ۲۰۲۳ء میں۱۲۸۷؍ارب روپے ہوگیا۔ پاکستان کی تاریخ میںبنکوں کے منافع میں اس حیرت انگیز تیز رفتاری سے اضافہ ہونے کی پہلے سے کوئی مثال نہیں ہے۔یہی نہیں، ۲۰۰۸ءمیں بنکوں کے قرضوں کا مجموعی حجم بنکوں کی مجموعی سرمایہ کاری سے کہیں زیادہ تھا،لیکن ۲۰۲۳ءمیں بنکوںکی مجموعی سرمایہ کاری بنکوںکے قرضوں کے حجم سے دوگنی سے بھی زیادہ ہوگئی۔ یہ خسارے اور تباہی کا سودا ہے اور اس سے قومی سلامتی کے لیے خطرات بڑھےہیں۔
بنکوں کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کی شرح نمو سست ہوئی، غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ،بچتوں کی حوصلہ شکنی ہوئی، ڈالرائزیشن و سرمائے کے فرار میں اضافہ ہوا، اور قومی سلامتی کو لاحق خطرات بھی دوچند ہوگئے۔ یہ نجکاری کے عمل کی زبردست ناکامی کا ایک اور ثبوت ہے۔
پاکستان میں کام کرنے والے تمام بنکوںکے دسمبر ۲۰۲۴ء میں مجموعی قرضوں کا حجم تقریباً ۱۶۳۰۹؍۱ رب روپے تھا، لیکن مجموعی سرمایہ کاری کا حجم تقریباً ۲۹۱۲۹؍ارب روپے تھا ۔تجارتی بنکوں کا اپنے قرضے کے مقابلے میں اتنی بڑی رقوم کی سرمایہ کاری کرنے کی پاکستان میں کوئی مثال موجود نہیں ہے اور شاید ہی دنیا بھر میں کوئی اور مثال ہو۔ ہم اس بارے میں برس ہا برس سے تواتر کے ساتھ اپنی پریشانی کا اظہار کرتے رہے ہیں مگر وزارتِ خزانہ،اسٹیٹ بنک اور بنکوں کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے یہ تباہ کن پالیسی برقرار رہی ہے۔ اب چونکہ پانی سر سے گزرچکا ہے، اس لیے ملک میں اِکا دکا کچھ آوازیں نیم دلی سے اٹھنا شروع ہوئی ہیں۔
پاکستان میں کام کرنے والے بنکوں کے ڈپازٹس کا تقریباً ۸۰فی صد ان بنکوں کے پاس ہے، جن کے مالکان غیر ملکی ہیں۔ ستمبر ۲۰۲۴ء میں پاکستان میں کام کرنے والے تمام بنکوں کے مجموعی اثاثوں کا حجم تقریباً۵۲۱۱۲ ارب روپے تھا،جب کہ پاکستان کی مجموعی جی ڈی پی کا حجم تقریباً ۱۰۵۰۰۰؍ارب روپے تھا یعنی بنکوں کے مجموعی اثاثے پاکستان کی جی ڈی پی کا تقریباً ۵۰فی صدہیں۔
پاکستان میں کام کرنے والے بنکوں نے برس ہا برس سے اسٹیٹ بنک اور وزارتِ خزانہ کے تعاون سے نجی شعبے کو قرضے فراہم کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ ہم یہ مسئلہ برس ہا برس سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اٹھاتے رہے ہیں ۔ آخر کار بعد از خرابیٔ بسیار گورنر اسٹیٹ بنک نے ۲۰۲۵ء میں یہ تسلیم کر ہی لیا کہ مالی سال ۲۰۰۴ءمیں بنکوں نے نجی شعبے کو جو قرضے دیے تھے،ان کا تناسب جی ڈی پی کا ۱۵فی صد تھا، جو مالی سال ۲۰۲۴ء میں کم ہوکر۸ء۴ فی صد رہ گیا۔ یہ حکومت، اسٹیٹ بنک اور بنکوں کے گٹھ جوڑ سے بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے بنکوں کی جانب سے حکومتی تمسکات میںسرمایہ کاری کی پالیسی کا منطقی نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی بنکوں کے شاہانہ اخراجات میںبھی حیرت انگیز تیز رفتاری سے اضافہ ہوا ہے۔
ہم یہ بات کہنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور پاتےہیں کہ بنکوں کی نجکاری کے بعد ان کی کارکردگی کی جو صورتِ حال سامنے آئی ہے، وہ ہمیں ’ایسٹ انڈیا کمپنی‘ (EIC)کے دور کی یاد دلاتی ہے،جو نیوگریٹ گیم کے تناظر میں نو آبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل میں واپسی کے مترادف ہے۔ اس پس منظر میں موجودہ حکومت کا نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کا فیصلہ بہت پریشان کن ہے۔
یہ امر بھی انتہائی تشویشناک ہے کہ گذشتہ تقریباًدوبرسوں سے پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتاچلاجارہا ہے۔ یہ سنگین وارداتیںپہلے سے طے شدہ منصوبےاورایک مربوط حکمت عملی کے تحت کروائی جارہی ہیں۔ اب یہ چیزیں کھل کر سامنے آرہی ہیں کہ امریکا نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جولائی ۲۰۲۱ء میںطالبان سےمفاہمت کے بعد اپنی افواج افغانستان سے اچانک واپس بلا لی تھیں۔ امریکا کا افغانستان سے انخلا کو پاکستان میں فتح مبین، امریکا کی شرمناک شکست اور طالبان کی زبردست کامیابی قرار دیاگیا تھا ۔ہم نےبہرحال اسی وقت کہاتھا:
۱- امریکا نے خطے میں اپنے استعماری مقاصد تبدیل کیے بغیر افغانستان سے انخلا کرکے صرف اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے۔اسے شکست سے منسوب کرنا خوش فہمی ہے۔
۲- امریکا، پاکستان اور افغانستان کو غیر مستحکم کرنے کی پالیسی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔
۳- امریکی انخلا کے بعدنئی افغان حکومت کے پاکستان سے تعلقات کشیدہ رہیں گے۔
۴- امریکا دہشت گردی کے نام پر جنگ جیتنےمیں کبھی بھی دلچسپی نہیں رکھتاتھا اور نہ وہ طالبان کی طاقت کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا ہے۔
گذشتہ تقریباً چار برسوں میں یہ تمام باتیں درست ثابت ہوئی ہیں۔نائن الیون کے فوراً بعد ہم نے لکھا تھا: ’’دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر لڑی جانے والی امریکی جنگ میں معاونت و شرکت پاکستان کے لیے خسارے اور تباہی کا سودا ہوگا اور اس معاونت و شرکت کے بدلے پاکستان کو جو امداد و مراعات ملیں گی، ان سے کہیں زیادہ نقصانات پاکستان کو اس دہشت گردی کی جنگ میںمعاونت کے نتیجے میں اٹھانا پڑیں گے‘‘(۲؍اکتوبر ۲۰۲۱ء)۔ اور اُسی وقت یہ بھی کہا تھا: ’’امریکی پالیسیوں کی نتیجے میں دہشت گردی کی اس جنگ میں معاونت اور شرکت سے جو چیلنج سامنے آئیں گے، ان سے نمٹنا پاکستان کی طاقت اور صلاحیت سے باہر ہوگا‘‘۔
افغانستان سے امریکی انخلا کے چند ماہ بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میںایک مرتبہ پھر تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ عالمی دہشت گردی انڈیکس ۲۰۲۵ءکے مندرجہ ذیل نکات انتہائی تشویشناک ہیں:
۱- عالمی دہشت گردی انڈیکس میںپاکستان کو دہشت گردی سے متاثر ہونے والا دنیا کا دوسراسب سے بڑا ملک قرار دیا گیا ہے۔
۲- کا لعدم تحریک طالبان پاکستان کو دنیا کی چار بڑی دہشت گرد تنظیموں میں شامل کیا گیاہے۔ اس تنظیم نے پاکستانی قوم اور مملکت پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی خوفناک اور خونی مہم شروع کی ہوئی ہے۔
۳- ۲۰۲۳ءکے مقابلے میں ۲۰۲۴ء میں پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیںدوگنی اور ۲۰۲۵ء کے پہلے تین ماہ ہی میں شدت پکڑگئی ہیں۔
۴- دہشت گردی کی ۹۶ فی صد وارداتیں صوبہ خیبر پختونخوا اورصوبہ بلوچستان میں ہورہی ہیں۔ بلوچستان کی دہشت گرد تنظیم، وہاں پر ہونے والی خوفناک دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہے۔
یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ افغانستان میں ۲۰۲۱ء میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد سے افغانستان ہی پاکستان میں دہشت گردی کرنے والی تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن گیا ہے۔ ان برسوںمیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید کشیدہ ہوگئے ہیں۔
پاکستان میں مختلف حکومتوں کے دور میںدہشت گردی کی وارداتوں سے نمٹنے کے لیے صرف طاقت کا استعمال کیا جاتارہا ہے۔ حالانکہ دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے لیے خطےکے عوام کے دل و دماغ بھی جیتنا ہوں گے اورپاکستان میں حکومتوں کو خود اپنی معاشی و مالیاتی پالیسیوں کے ذریعے عوام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی کرنے سے اجتناب کرنا ہوگا۔
نائن الیون کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر لڑی جانے والی امریکی جنگ میں معاونت اور بعد میں اس جنگ کوامریکی ایجنڈے کے مطابق پاکستان کی خود اپنی جنگ بنانے کے صلے میں امریکا نے پاکستان کے کچھ قرضے معاف کیے تھے۔ پاکستان کو نقد امداددی تھی اور دہشت گردی کی جنگ کے نقصانات کے ایک حصے کی تلافی بھی کی تھی، مگر یہ خسارے اور تباہی کا سودا ہی رہا۔ پاکستان میںدہشت گردی کی وارداتوںسے اب تک تقریباً ۸۵ ہزار افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا بھی سامنا ہے۔
اب سے کچھ عرصہ قبل پاکستان میں صبح شام ڈیفالٹ کرنے کے نعرے خود حکومتی حلقوں کی جانب سےبھی لگائے جاتے رہے تھے، مگر ہم نے درجنوں بار کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا،کیونکہ امریکا کوپاکستان میں جہادی تنظیموں کے خلاف کارروائی، افغانستان کے معاملات، روس یوکرین جنگ، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور’گریٹر اسرائیل‘ کے ناپاک منصوبے میں پیش رفت کرنے اور اپنے استعماری مقاصد کے حصو ل کے لیےبہترین محل وقوع کا حامل پاکستان، اس کی طاقت ور فوج اور عالم اسلام کا اہم ملک ہونے کی وجہ سے ابھی بھی امریکا کو پاکستان کی مددکی ضرورت ہے۔
۲۸ فروری ۲۰۲۵ءکو مدرسہ حقانیہ میں خود کش حملہ اور ماضی میں دینی مدارس کے خلاف اسلام دشمن قوتوں کے پروپیگنڈا سے اس بات کا خدشہ نظر آرہا ہے کہ استعماری طاقتیں آگے چل کر پاکستان میں دینی مدارس کے معاملات اور نصاب میں کسی نہ کسی شکل میں مداخلت کریں گی۔
افغانستان سے امریکی افواج نے انخلا کے وقت اربوں ڈالر کا اسلحہ اور فوجی سازوسامان دانستہ افغانستان میں چھوڑا تھا تاکہ یہ ہتھیار پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی کی وارداتوں کے لیے بھی استعمال کیے جاسکیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نےایک حکمت عملی کے تحت امریکی اسلحہ اور (چین پر نظر رکھنے کے لیے) افغانستان کا بگرام ائربیس واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ عزائم متعدد سنگین خدشات کو جنم دے رہے ہیں۔ دراصل نیو گریٹ گیم کےمقاصد کے حصول کے لیےاٹھائے جانے والے امریکی اقدامات اور پالیسیاںاس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر لڑی جانے والی امریکی جنگ کا پہلے سے کہیں زیادہ اہم اور فیصلہ کن مرحلہ چار برس قبل ہی شروع ہوچکا ہے، اور اس کا محور افغانستان اور پاکستان تک محدود نہیں ہے اور نہ رہے گا۔
امریکا میں حکومت ڈیموکریٹک پارٹی کی ہو یا ری پبلکن پارٹی کی، سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوششیں وہ بہرحال جاری رکھے گا۔ امریکا چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت آنے والے برسوں میںبحال تو نہ ہو مگر لڑکھڑاتی ہوئی چلتی رہے۔ بدقسمتی سےوفاقی وصوبائی حکومتوں ، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں، اسٹیٹ بنک اور ایف بی آروغیرہ کی پالیسیاں اس مقصد کے حصول میںعملاً معاونت کررہی ہیں۔ امریکا کا موجودہ نسبتاً ’ہمدردانہ رویہ‘ لمبے عرصےتک برقرار نہیں رہے گا اور ایک مرتبہ پھر معاندانہ ہوجائے گا ۔ اس مدت کو ایک مہلت سمجھ کر پاکستان کو معیشت، مالیات اور توانائی کے شعبے میں اسٹرکچرل اصلاحات کرنا ہوںگی اور معیشت کو خود انحصاری کے زریں اصولوں پر استوار کرنے کے لیے اسلامی نظام معیشت کےاصولوں کے مطابق انقلابی نوعیت کے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔
تنبیہہ:مندرجہ بالا گزارشات کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جوہری طاقت کے حامل پاکستان نے ایک فلاحی اسلامی مملکت کے شایان شان، اسلام کےعادلانہ معاشی نظام کے مطابق اپنی پالیسیاں اور قوانین وضع نہیں کیے اور سرمایہ دارانہ نظام کی بگڑی ہوئی شکل پر مبنی مختلف پالیسیاں برقرار رکھیں، تو خدشہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کی سلامتی کو خطرات دو چند ہوجائیں گے بلکہ معیشت سے سود کے خاتمے اور اسلامی نظام معیشت وبنکاری شریعت کی رو ح کے مطابق نافذ کرنے کے دعوے خواب و خیال بن کر رہ جائیں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔
پاکستان پانی کی فراوانی و دستیابی والے ملک کے مقام سے گر کر اب پانی کی قلت والا ملک بننے کے قریب ہے اور بعض تخمینوں کے مطابق بن چکا ہے۔ دیگر ماہرین کے مطابق اگر اس سلسلے کو روکنے کے لیے فوری اقدامات نہ اٹھائے گئے تو ۲۰۳۵ء تک یقینی طور پر پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہوگا۔ اس صورت حال تک پہنچنے میں جہاں موسمیاتی تبدیلیوں اور آبادی میں اضافے کا حصہ ہے، وہاں اس میں ایک بہت بڑا حصہ پانی کے غیرمحتاط استعمال، اس کی ترسیل کے ناقص انتظام اور اسے ذخیرہ کرنے میں کوتاہی کا بھی ہے۔ یہی وہ پہلو ہیں جن پر اس تحریر میں ہماری توجہ مرکوز ہے۔ اس مقصد کے لیے ماضی میں تیار کی گئی متعدد رپورٹوں سے مدد لی گئی ہے، جن میں سے اکثر کی تیاری کے لیے حکومتِ پاکستان کا کوئی نہ کوئی محکمہ شامل رہا ہے۔
ہمارے تجزیے کے مطابق قابلِ عمل منصوبہ بندی اور ترجیحات کے درست تعیّن کے ذریعے صورت حال کو اب بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ملک کے تمام صوبوں کی مشاورت اور شمولیت سے اور ان کے تحفظات کو دُور کرتے ہوئے ایسا کرنا بالکل ممکن ہے۔ ہمارے پاس ایسی دستاویزات، معاہدے، ایکٹ اور پالیسیاں موجود ہیں، جن کی بنیاد پر تعمیری پیش قدمی ممکن ہے۔ اسی طرح ہمیں ایسے فورم بھی میسر ہیں جہاں گفتگو اور تبادلۂ خیال کے ذریعے مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جا سکتا ہے۔
تاریخی طور پر وہ تہذیبیں اور شہر جو پانی کی عدم دستیابی سے اُجڑ گئے، ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ پانی کی قلت سے جو خشک سالی پیدا ہوئی تو اس نے ان علاقوں میں زراعت کو شدید نقصان پہنچایا۔ زراعت ہی ان علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی زندگی اور غذائی ضروریات کے حصول کا اہم ترین ذریعہ تھی۔ اس میں خلل پڑا تو یہ بستیاں اُجڑ گئیں۔
پاکستان بننے کے بعد بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں شدید خشک سالی اور قحط جیسی صورت حال پیدا ہوتی رہی ہے، جس کی کثرت موجودہ صدی میں بڑھ گئی ہے۔ مثلاً، پاکستان کی تاریخ کی شدید ترین خشک سالی صوبہ بلوچستان میں ۲۰۰۰ء اور ۲۰۰۲ء کے دوران ہوئی اور یہی صورت حال ۲۰۱۳ء-۲۰۱۴ء میں صوبہ سندھ کے علاقے تھرپارکر میں رہی، جب کہ ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء اور ۲۰۲۰ء میں سندھ اور بلوچستان کے کئی اضلاع خشک سالی کا شکار ہوئے۔ اس دوران، پاکستان کے موسمیاتی ادارے کے مطابق ان علاقوں میں ۲۰ سے ۳۰ فی صد بارش کی کمی رہی، جو ان علاقوں کے لیے پانی کی فراہمی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔
دوسری جانب ہم حالیہ برسوں میں سیلابوں سے ہونے والی تباہی دیکھ چکے ہیں۔ جن میں ۲۰۲۲ء کے سیلاب میں سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے صوبوں میں دو ہزار کے قریب اموات ہوئیں۔ مویشیوں، فصلوں اور رہائشی علاقوں کے علاوہ انفرا اسٹرکچر کی تباہی کا تخمینہ ۴۰ بلین ڈالر کے لگ بھگ لگایا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ۱۹۵۰ء، ۱۹۷۳ء،۱۹۹۲ء اور موجودہ صدی میں ۲۰۰۳ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء میں بھی سیلاب نے ملک میں تباہی مچائی۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ حالیہ برسوں میں سیلابوں کی کثرت میں اضافہ ہوا ہے، جس کا زیادہ تعلق موسمیاتی تبدیلیوں سے ہے، جو ایک قابلِ تشویش اور توجہ طلب صورت حال ہے۔
پانی کی تقسیم کے اعتبار سے بین الااقوامی اور بین الصوبائی معاہدوں کی تاریخ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ بہت اہم سندھ طاس معاہدہ مغربی اور مشرقی دریاؤں کی تقسیم کے سلسلے میں ۱۹۶۰ء میں ہوا، جو اب تک برقرار ہے۔ تاہم، انڈیا نے اس معاہدے پر نظرثانی کے لیے حال ہی میں دو نوٹس پاکستان کو بھیجے ہیں، جب کہ جموں و کشمیر میں پاکستان کے لیے مختص پانی پر روک لگانے کے انڈین منصوبوں کے خلاف پاکستان نےعالمی عدالت میں مقدمات دائر کر رکھے ہیں، جنھیں عدالت نے شنوائی کے لیے منظور بھی کر لیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انڈیا اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر تبدیل یا ختم نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انڈیا اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے بھاری رقوم خرچ کر کے بین الاقوامی رائے کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے لابنگ کررہا ہے۔
اگرچہ انڈیا ایک کمزور پوزیشن میں ہے، کیونکہ وہ خود بھی دریائے برہماپتر کے پانی کی نسبت سے ایسی صورت حال سے دوچار ہے جیسا کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کی صورت حال ہے۔ حال ہی میں چین نے دریائے برہماپتر پر ایک بڑا ڈیم بنانے کے منصوبے کا انکشاف کیا ہے۔ پاکستان کے بین الصوبائی معاہدوں میں اہم اور نافذ العمل معاہدہ ۱۹۹۱ء کا پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے، جس میں چاروں صوبوں کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ صوبوں کے درمیان اس معاہدے کے نفاذ سے متعلق بعض اوقات اختلافات سامنے آتے رہتے ہیں، تاہم ان اختلافات کو ٹکنالوجی، جدید مانیٹرنگ سسٹم اور واٹر آڈٹ کے ذریعے حل کیا جاسکتا ہے۔
پاکستان نے جب ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اپنا سفر شروع کیا تو مغربی پاکستان کی آبادی ۳ کروڑ ۳۰ لاکھ تھی، جو بڑھ کر ۲۰۲۵ء میں ۲۵کروڑ ۴۰ لاکھ ہوجائے گی۔ یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ فی کس پانی کی دستیابی میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی کمی آئی ہے۔ ۹۵ فی صد تک پانی زراعت پر صرف ہوتا ہے۔ زرعی شعبہ ۱۹۵۰ء کے عشرے میں جی ڈی پی میں اپنے حصے کے حساب سے ۵۳ فی صد کی بلند ترین سطح پر پہنچا، اور اس کے بعد تنزلی کا سفر طے کر کے اب ۲۴-۲۳ فی صد کے درمیان پہنچ گیا ہے (اکنامک سروے آف پاکستان ۲۰۲۴ء) ۔ اسی طرح زرعی اجناس کی برآمد ابتداء میں کل برآمد کا تقریباً ۹۹ فی صد تھی، جو ۹۰ فی صد زرِ مبادلہ کمانے کا ذریعہ تھی۔ تاہم، اب بھی پاکستان کی ۷۰ فی صد برآمدات بالواسطہ یا براہِ راست زراعت سے منسلک ہیں۔ اس طرح یہ شعبہ یقیناً ملک کے لیے بہت اہم ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ فرسودہ طریقوں سے جاری کاشت کاری کے باعث ایک جانب تو ہماری فی ایکڑ پیداوار کم ہے، ساتھ ہی پانی کے غیرمؤثر اور بلا ضرورت استعمال اور فراہمی آب کے ناقص نظام کے سبب پانی کی ایک بڑی مقدار ضائع ہوتی رہی ہے۔ فصلوں کے لیے پانی کے استعمال میں جدید سائنسی معلومات اور طریقوں کو اختیار کر کے جو کمی لائی جا سکتی تھی وہ ہم نہیں لاسکے۔ اگرچہ ہم اپنے نہری نظام کی وسعت پر تو فخر کرتے ہیں، جو صدیوں پرانا ہے اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وسیع تر ہوتا گیا ہے، لیکن ان نہروں کو پختہ کرنے پر خاطرخواہ توجہ نہیں دی گئی۔ کچی نہروں کے کناروں اور تہوں سے رس کر پانی کی ایک بہت بڑی مقدار ضائع ہوجاتی ہے۔ بلاشبہ اس طرح پانی کا ایک حصہ زیرزمین آبی ذخیروں کو قائم رکھنے میں بھی صرف ہوتا ہے۔ اسی طرح نہروں اور آبی ذخیروں سے سورج کی شعاعوں سے بخارات بن کر بھی پانی کا ایک حصہ اُڑ جاتا ہے۔ کئی علاقوں میں اس طرح پانی ضائع ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے جن میں بلوچستان سرِ فہرست ہے، جہاں تاریخی طور پر کاریزوں کے زیرِ زمین نظام کے ذریعے اس پر قابو پایا جاتا تھا۔ آج کے دور میں یہ ہدف آبی ذخیروں پر فلوٹنگ شمسی پینل لگا کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے سے پیدا ہونے والی بجلی کو مین گرڈ سے دُور علاقوں میں استعمال کے لیے مہیّا بھی کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی پانی کے ضیاع میں کمی لائی جاسکتی ہے۔ ایک نسبتاً کم خرچ حل ان ذخائر پر فلوٹنگ پلاسٹک گیندوں کو پھیلاکر بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔
یہاں اس چیلنج کو حل کرنے کی تجاویز پیش کی جاتی ہیں:
پاکستان میں چھوٹے بڑے ڈیموں کی کل تعداد ۱۵۰ ہے۔ ایک تقابلی جائزے کے لیے، انڈیا میں ایسے ڈیموں کے تعداد ۵۳۰۰ ہے، جب کہ سیکڑوں ڈیم زیر تعمیر ہیں۔ چین میں ڈیموں کی تعداد ۲۸ہزار ۹سو ہے۔ پاکستان میں ضرورت کا پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ۳۰ دن، جب کہ انڈیا میں ۱۲۰ دن کی ہے۔ پاکستان کی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش زیر تعمیر ڈیم منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد تقریباً ۱۳ ملین ایکڑ فٹ سے بڑھ کر تقریباً ۲۴ ملین ایکڑ فٹ ہوجائے گی۔ ان منصوبوں میں دیامر- بھاشا ڈیم سب سے بڑا ہے، جس میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ۸ء۲ملین مکعب فٹ ہوگی اور ۴۵۰۰ میگاواٹ بجلی بھی یہاں سے پیدا کی جا سکے گی۔ پاکستان میں اکثر ڈیم کثیرالمقاصد ہیں، جن کی افادیت میں پانی ذخیرہ کرنے کے علاوہ، بجلی پیدا کرنا، سیلاب سے بچاؤ وغیرہ شامل ہیں۔ اس سلسلے میں مستقبل میں بننے والے ڈیموں میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو شامل کرنا موجودہ حالات اور مستقبلِ قریب کے تناظر میں بحث طلب ہے۔
پچھلے چند عشروں میں ہماری حکومت کی ناقص منصوبہ سازیوں کے سبب ہم کبھی ’آئی پی پیز‘ (IPPs)کے جال میں پھنس گئے اور کبھی ایل این جی (LNG) جیسے قیمتی سرمائے (ایندھن) کو بجلی پیدا کرنے کے لیے درآمد (Import) کرنے کے لیے ناقابلِ تصور شرائط سے بُنے معاہدوں میں جکڑے گئے۔ پھر یہ بھی کہ ہم اس مہنگی بجلی کے استعمال کے وسیلے سے صنعتی ترقی بھی نہ کرسکے۔ اب ان معاہدوں سے نکلنے کی کوششوں میں مختلف وجوہ کے سبب خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں ہوپارہی۔ چنانچہ ہم اس صورتِ حال سے دوچار ہیں کہ ہم آج بھی اپنی ضرورت سے تقریباً دوگنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور زیرِ تعمیر منصوبے، جن میں دیامیر- بھاشا ڈیم اہم ہے، اس صلاحیت کو دُگنا کر دیں گے۔ بجلی کی پیداوار کو مؤخر کر کے اگر ان ڈیموں کی تعمیر کے کل اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہو تو ایسا کرنا مناسب ہو گا۔ کم از کم مستقبل قریب کے لیے تجویز کردہ منصوبوں کے لیے اس امر کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہمیں فی الحال بجلی پیدا کرنے کے مزید منصوبوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود کہ پن بجلی ایک سستی اور ماحولیاتی اعتبار سے محفوظ ذریعۂ توانائی ہے۔
پانی ذخیرہ کرنے کی موجودہ صلاحیت میں اضافے، پانی کی قلت کی رواں صورت حال اور اس کے مستقبل کے اندازوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کو مزید آبی ذخیروں کی ضرورت ہے۔ تاہم، یہ سوال اہم ہے کہ کیا ہم بڑے آبی ذخائر کی تعمیر کے متحمل بھی ہیں؟ دیامر- بھاشا ڈیم جو کہ پانی کا ایک بڑا ذخیرہ تخلیق کرے گا، پاکستان اس منصوبے کے لیے منظوری دے چکا اور اس کا پابند ہے۔ مزید آبی ذخائر کے لیے چھوٹے ڈیموں پر توجہ دینا ایک بہتر راستہ ہوگا، جن کے لیے صوبہ جات میں متعدد مقامات کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ چھوٹے ڈیم اور آبی ذخائر نسبتاً کم قیمت پر اور قلیل مدّت میں تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری تجویز ہے کہ تمام صوبے ۱۹۹۱ء کے بین الصوبائی معاہدے کے تحت اپنے متعین شدہ فی صد حجم کی مناسبت سے پانی ذخیرہ کرنے کے انتظامات کریں، تاکہ موسمیاتی تغیرات وغیرہ سے پیدا ہونے والی کمی اور آبادی میں اضافے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اضافی ضروریات کو ان ذخائر سے حسب ضرورت پورا کیا جا سکے۔ وفاقی حکومت اس مقصد کے لیے کل اضافی مقدار کا تعین کرے، صوبے اپنے اپنے حصے کا پانی ذخیرہ کرنے کی استطاعت میں اضافے کے لیے کم از کم اپنے مجوزہ حصے کے ہدف کو حاصل کرنے کے پابند ہوں۔
ڈیموں کے جہاں کچھ نقصانات ہیں اور ان سے بچاؤ کی تدابیر ضروری ہیں، وہاں ان کی افادیت کی فہرست طویل ہے، جس میں مچھلیوں کی افزائش، سیاحت کا فروغ اور ان کے آبی ذخائر کی تہہ میں معدنیات کے ذخائر (placer deposits) سے لے کر اس مٹی کی زرخیزی سے بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس بناء پر بڑی تعداد میں چھوٹے ڈیموں کی تعمیر کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ یہاں تک کہ دریائوں اور ندی نالوں کے ساتھ ساتھ موجود آبادی کے اشتراک سے حکومتی سرپرستی میں چھوٹے چھوٹے آبی ذخائر بنانے کے رجحان کو بھی فروغ دیا جائے۔ ہماری نظر میں، ہر وہ منصوبہ جس میں عوام کی ایک بڑی تعداد شامل ہو، وہ انفرادی اور قومی سطح کے فوائد حاصل کرنے کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ ایسے منصوبوں کی طرف خصوصی توجہ دینا ہمارے لیے بڑے بڑے منصوبوں پر عمل درآمد سے زیادہ بہتر نتائج کا ذریعہ ثابت ہو گا۔
مزید یہ کہ زیرزمین پانی کے ذخائر کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر ’الیکٹرک ری سسٹیویٹی سروے‘ (Electric Resistivity Survey) اور اس قسم کے دیگر طریقوں کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ خاص طور پر بارانی اور ریگستانی علاقوں میں اس قسم کے سروے اور ’ہائیڈرلوجک ماڈلنگ‘ سے مدد لے کر زیرزمین پانی کے ذخائر کے مناسب استعمال کی منصوبہ سازی کی جائے۔ ایسا کرنے سے دریائی پانی کی قلّت کے پیش نظر اس پر انحصار کو کم کیا جاسکے گا۔ چولستان جیسے علاقوں میں دریا کی پرانی گزرگاہیں زیرزمین پانی کی تلاش کے لیے موزوں علاقے ہوسکتے ہیں۔
اس مسئلے سے جڑے ایک اہم سوال پر غور و خوض ضروری ہے، اور وہ یہ کہ شعبۂ زراعت کے لیے مستقبل میں پانی کی کتنی ضرورت ہوگی؟ یہ بھی کہ اس ضمن میں ایسی کون سی نئی راہیں ہیں جنھیں اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ پانی کی متوقع ضرورت کو پورا کیا جا سکے؟ مختلف تخمینے بتاتے ہیں کہ زراعت کے لیے کل پانی کا ۹۰ سے ۹۵ فی صد کاشت کاری کے لیے نہری نظام کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے، مگر اس میں سے ۵۰ سے ۶۰ فی صد ضائع ہو جاتا ہے، جس کی بعض وجوہ اُوپر بیان کی گئی ہیں۔ مقدار کے حساب سے یہ ضائع ہونے والا پانی ۶۰ سے ۷۰ ملین ایکڑ فٹ بنتا ہے۔ اس ضیاع کو جس قدر مؤثر انداز میں کم کیا جا سکے اتنا ہی قومی خزانے پر نئے ڈیموں کی تعمیر کے حوالے سے کم بوجھ پڑے گا۔ کیونکہ یہ اقدامات نسبتاٌ کم خرچ اور بآسانی قومی اتفاقِ رائے پیدا کرکے کیے جا سکتے ہیں۔ انھیں ہنگامی بنیادوں پر، بڑے پیمانے پراور بلا کسی تاخیر کے شروع کرنا ناگزیر ہے۔ ان اقدامات کی ایک فہرست درج ذیل ہے:
اس مضمون میں ایسی بہت سی تفصیلات شامل نہیں کی گئیں، جنھیں انٹرنیٹ پر موجود رپورٹ میں دیکھا جا سکتا ہے، جس میں مختلف مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ یہاں پر صرف پاکستان کے مخصوص اقتصادی حالات سر فہرست ہیں، اور منصوبوں کے قابلِ عمل ہونے کے اعتبار سے ترجیحات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں اور ان کے حساب سے نئی ترجیحات مرتب کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے کہ آئی پی پیز وغیرہ کے مسائل سے چھٹکارا پانے کی صورت میں اور ملک کی اقتصادی صورتِ حال بہتر ہوجانے پر دوبارہ پن بجلی کے منصوبوں کی طرف توجہ کرنا، وغیرہ۔ اس بنا پر تمام مسائل اور ان سے نبردآزما ہونے کے ممکنہ طریقوں کونظر میں رکھنا ضروری ہے۔ ہماری ٹیم کی تیار کردہ جس رپورٹ کا حوالہ دیا گیا، اس مجموعی صورت حال کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔
یہ بات امید افزا ہے کہ پاکستان میں پانی کی قلت سے متعلق خطرات کو حکومتی سطح پر، ماہرین سائنس و ٹکنالوجی نے اور سماجی مسائل پر نظر رکھنے والے اہلِ علم و دانش نے شدّت سے محسوس کیا ہے اور پچھلے چند برسوں میں اس ضمن میں تحقیق کے نتیجے میں متعدد معیاری مقالے شائع ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین اور اداروں کا بھی اس کام میں بڑا حصہ ہے۔ مگر جو بات تشویشناک ہے وہ یہ کہ ایسی آگہی عوامی سطح پر موجود نہیں۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے ہدف کو ہم نے مقدّم رکھا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہماری غذائی اور دیگر ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں اور ساتھ ہی ہماری بین الاقوامی زرعی تجارت کا میزانیہ درآمد کی جانب کئی بلین ڈالر بڑھ گیا ہے ( External Trade, Pakistan Bureau of Statistics 2023)۔
۲۰۲۳ء میں یہ خسارہ۵۵ء۲۷ بلین ڈالر تھا (Agricultural Performance Finance Division 2022-2023 )۔ یہ صورت حال اس کے باوجود رہی کہ اس سال پاکستان نے گندم اور چینی کی ریکارڈ مقدار برآمد کی۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ زرعی پیداوارمیں اضافہ اپنی موجودہ صورت میں زرعی تجارت کے خسارے کو کم کرنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے، کہ پاکستان کی کل برآمدات میں ۷۰ فی صد حصہ براہِ راست زرعی پیداوار اور اس سے وابستہ اشیاء کا ہے۔ یہ صورت حال درج ذیل اقدامات کا تقاضاکرتی ہے:
اُوپر بیان کیے گئے نکات کی روشنی میں قابلِ کاشت زمین میں اضافے سے پہلے ہمارے لیے موجودہ قابل کاشت زمین کی زرعی پیداوار میں اضافے اور فصلوں کے انتخاب میں بہتری لانے کے مواقع پر توجہ کرنا اہم ہو گا، جن سے زرعی تجارت کے خسارے میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ مزید یہ کہ زراعت سے وابستہ مصنوعات جن میں کپاس سب سے اہم ہے۔ ان کی پیداوار، ان کی قدر بڑھانے اور زیادہ قیمتی اور قابلِ قدراشیاء کی تیاری وغیرہ پر توجہ دینا بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس سلسلے میں ٹیکسٹائل کی صنعتوں کو جدید نہج پر اٹھانے کی سعی کرنا ہوگی، تاکہ ہم محض کپاس کی بیلز اور دھاگے سے آگے بڑھ کر زیادہ قدرو قیمت والی اشیا برآمد کرسکیں۔ اس سلسلے میں حکومتی سرپرستی میں توانائی کی سستے داموں فراہمی کو یقینی بنانا ہماری مصنوعات کے لیے بین الاقوامی مسابقت میں اہم کردار ادا کرے گا۔
زرعی اجناس کی برآمدات کو متنوع بنانے پر توجہ دینا ہو گی تاکہ زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ اُٹھایا جاسکے۔ اس سلسلے میں بتدریج زراعت پر انحصار والی معیشت سے ایک کثیرالجہت معیشت کی طرف پیش قدمی کرنا ہوگی۔ ایسا کرنا مستقبل میں پانی کی قلت کے دباؤ کو کم کرنے میں بھی معاون ہو گا۔
دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ’’کیا پانی کی قلت پر قابو پانا آج ہمارے لیے اہم ترین مسئلہ ہے؟‘‘ اگرچہ اس تحریر کے ابتدائی حصے میں اس مسئلے کی اہمیت اور شدت پر گفتگو ہو چکی ہے اور اس سے نبردآزما ہونے کے لیے چند تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔ تاہم، یہاں ہم اپنے پہلے سوال سے وابستہ گزارشات کی روشنی میں چند مزید معروضات پیش کرتے ہیں۔
اس بات میں کوئی کلام نہیں کہ مستقبل قریب میں پانی کی قلت پاکستان کے لیے اہم ترین مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ بن کراُبھر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں، ایک جانب تو عوام الناس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، قومی ترقی متاثر ہو گی، اوردوسری جانب اس سے بین الاقوامی اور اندرونی تنازعات بھی سر اٹھا سکتے ہیں۔ انڈیا سے سندھ طاس معاہدے سے جڑے مسائل کا ذکر اوپر ہو چکا، جن سے نمٹنے کی تدابیر ضروری ہیں۔ پانی کی اندرونِ ملک تقسیم کے سلسلے میں ۸۰ کے عشرے میں ہم ’کالا باغ ڈیم‘ کے معاملے میں صوبوں کے درمیان کشیدگی کے شاہد ہیں۔ بعدازاں بھی اس قسم کے چھوٹے بڑے تنازعات سر اٹھاتے رہے ہیں۔ اگرچہ ان تنازعات کو ۱۹۹۱ء کے پانی کی تقسیم کے معاہدے کے مطابق اور سی سی آئی جیسے فورمز پر حل کیا جانا چاہیے۔ تاہم، ہم دیکھتے ہیں کہ ان راستوں کے موجودگی کے باوجود پانی سے تعلق رکھنے والے منصوبے عوام اور میڈیا میں موضوعِ بحث بن جاتے ہیں۔ ان بحثوں کے شرکاء میں مکمل معلومات کے فقدان کے سبب بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو عوامی سطح پر پھیل جاتی ہیں۔
اس سلسلے میں حالیہ دنوں کی مثال چولستان کا نہری منصوبہ ہے:
ہم اس منصوبے کے بارے میں چند حقائق پیش کرتے ہیں، جسے ’چولستان کنال پروجیکٹ‘ کہا جا رہا ہے، جو ’گرین پاکستان انیشیٹیو‘ کا ایک جزو ہے۔ اس کے ذریعے پہلے مرحلے میں چولستان کی ۴۵۲ ہزارایکڑصحرائی زمین کو قابلِ کاشت بنایا جائے گا اور اس منصوبے کی اہم شریان یعنی نہرچولستان ۱۷۶ کلو میٹر طویل ہو گی، جب کہ اس سے مشرق کی طرف نکلنے والی مروٹ نہر ۱۲۰ کلومیٹر طویل ہوگی، جس سے آگے چھوٹی نہروں کا ایک جال بچھایا جائے گا جو مجموعی طور پر ۴۵۲ کلومیٹرطویل ہوگا ۔ منصوبے کے اس پہلے حصے پر ۲۱۱ بلین روپے خرچ ہوں گے۔ IRSA (انڈس ریور سسٹم اتھارٹی) نے فروری ۲۰۲۵ء میں اس منصوبے کے لیے پنجاب حکومت کو پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، جس کی صوبہ سندھ نے مخالفت کی ہے۔ اس کے باوجود کہ موجودہ صدرِ مملکت مبینہ طور پر اس سے پہلے جولائی ۲۰۲۴ء میں اس منصوبے کی توثیق کرچکے ہیں۔ چولستان کی سیرابی کے دوسرے مرحلے میں نہری نظام کو مزید توسیع دے کر اس سے ۷۴۴ ہزار ایکٹر اضافی رقبے کو سیراب کرنے کا منصوبہ ہے۔
۲۰۲۳ءمیں ۱۰ اور ۱۴؍اگست کے درمیان سیلابی صورت حال کے باعث انڈیا نے ۸۰سے ۱۰۰ ہزار کیوسک کا ریلا ستلج اور بیاس کے مشرقی دریاؤں کے ذریعے پاکستان کی طرف چھوڑا، جس سے پاکستان کے کئی شہروں میں سیلاب سے تباہی آئی۔ تاہم، ریکارڈ بتاتا ہے کہ ایسی سیلابی صورت ۳۵ برسوں میں ایک بار ہی پیدا ہوئی، جب کہ اس سے برعکس یعنی خشک سالی کی کیفیت متعدد بار سامنے آئی ہے۔ مزید یہ کہ ایشین ڈویلپمنٹ بینک کی ۲۰۱۰ء کی رپورٹ جو گلیشیروں کے پگھلنے کے بارے میں ہے، آنے والے برسوں میں پانی کی شدید قلت کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایسی صورت حال میں پانی کے استعمال کے بڑے منصوبوں سے اس وقت تک اجتناب بہتر ہوگا، جب تک ہم واٹر مینجمنٹ کے دیرینہ مسائل کو حل نہیں کر لیتے۔
اُوپر بیان کردہ تفصیلات کی روشنی میں مستقبل میں پانی کی دستیابی میں کمی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ایسے حالات میں قابلِ کاشت رقبے کو بڑھانے کے ایسے منصوبوں پر عمل درآمد، جن میں اضافی پانی درکار ہو گا، تشویش پیدا کرتے ہیں۔ چولستان کی سیرابی جیسے منصوبوں کو محض سیلابی پانی پر تکیہ کر کے نہیں بنایا جا سکتا۔ غرض یہ کہ چولستان میں بنائے جانے والے نہری نظام کے لیے پانی کی ضروریات کو موجودہ زرخیز زمینوں کے پانی میں کٹوتی کر کے ہی پورا کیا جا سکے گا، جہاں پہلے ہی پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ اس اضافی کٹوتی سے جنوبی پنجاب ہی نہیں بلکہ صوبہ پنجاب کی تمام نہری زمینیں متاثر ہوسکتی ہیں، کیونکہ پنجاب حکومت کو اپنے طے شدہ حصے ہی میں سے یہ پانی چولستان کی سیرابی کے لیے مہیّا کرنا ہوگا۔ مزید یہ کہ اگر کسی انداز میں بھی دریائے سندھ کے زیریں بہاؤ کے لیے مقرّرہ پانی کے حصے کو کم کیا جاتا ہے تو جنوبی پنجاب سے لے کر دریا کی انتہا پر موجود ڈیلٹا سے متصل اراضی تک بلکہ ڈیلٹا کی آبی حیات اور ماحولیات بھی متاثر ہوں گے۔
اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ، زرعی پیداوار اپنی موجودہ صورت میں زرِ مبادلہ حاصل کرنے کا کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اس کے لیے قابلِ کاشت رقبے کو بڑھانے کے نتیجے میں ہم پانی کے استعمال میں اضافہ کریں گے اور اس اعتبار سے مزید دباؤ کی کیفیت میں آ جائیں گے۔ اس بنا پر چولستان کی سیرابی جیسے منصوبوں کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے یہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے پانی کے ترسیلی نظام کی مرمت اور اس کے استعمال کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے درست کرکے پانی کی بچت کا سامان کرنے پر توجہ دیں، اور پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں۔ ان اقدامات کے نتیجے میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہمیں جو اضافی پانی دستیاب ہوگا، وہ وقت قابلِ کاشت زمین میں اضافے کے لیے موزوں ہوگا۔ کیونکہ چولستان کی سیرابی جیسے منصوبے کی تکمیل میں کئی سال لگ جائیں گے، لہٰذا اس طرف سوچا جا سکتا ہے کہ اس منصوبے کو دو بڑے حصوں کے بجائے، چھوٹے چھوٹے کئی مراحل میں مکمل کیا جائے، اور جیسے جیسے دیگر اقدامات کے نتیجے میں پانی کی اضافی مقدار دستیاب ہوتی جائے، اسی رفتار سے یہ منصوبہ اپنی تکمیل کی طرف گامزن رہے۔ کیونکہ اس منصوبے کے بعض پہلو ہماری دفاعی ضروریات سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس پہلو کے پیشِ نظر منصوبے کی ترجیحات کو ترتیب دینا مناسب ہوگا۔
اس ضمن میں یہ بات بھی اہم ہوگی کہ پانی کا وہ حصہ جو ریگستان کی طرف ارسال کیا جانا ہے اور بالخصوص سیلابی پانی کو مجوزہ نہروں میں ایک عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے تدابیر کی جائیں، تاکہ بعدازاں وقت ِضرورت استعمال کیا جا سکے۔ اس میں پانی کو بخارات بن کر ضائع ہونے سے روکنے کی تدابیراہم ہیں۔
پاکستان کی نا قابلِ کاشت زمین کے مفید استعمال کے موضوعات پر سوچنا اور ایسے قابلِ عمل منصوبوں پر آگے بڑھنا قابلِ تحسین عمل ہوگا کہ جس سے چولستان، تھرپارکر یا تھل وغیرہ کی زمینوں کو ملک کے لیے اور ان علاقوں میں بسنے والوں کے لیے منفعت بخش بنایا جاسکے۔ ایسی کسی بھی پیش رفت کے لیے ملک کی تمام اکائیوں اور بالخصوص منصوبوں کے لیے زیرِ غور علاقوں اور منصوبوں سے متاثر ہونے والے علاقوں میں بسنے والوں کو منصوبہ بندی کے لیے مشورے میں شامل رکھا جائے اور تمام اقدامات ایک مشترکہ اور قابلِ قبول لائحہ عمل کے تحت ہی کیے جائیں۔
اپریل کا مہینہ اب ’یاد اقبال‘ کے لیے وقف سا ہو گیا ہے۔ ہم خاص مواقع پر خصوصی پروگراموں کے مخالف نہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارا سال تو ہم اقبال کو بھولے رہتے ہیں۔ اِدھر ۲۱؍اپریل آئی، اُدھر مختلف گوشوں سے طرح طرح کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ سب اقبال کا پیغام یاد دلاتے ہیں اور اس پر عمل کا مشورہ دیتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت نہ کوئی اس کے پیغام کو بیان کرتا ہے، اور نہ خود اس پر عمل کی کوئی روشن مثال قائم کرتا ہے۔ پورا ہنگامہ ہوا ہو ایک ڈراما سامعلوم ہوتا ہے، جس کے بیش تر اداکار مصنوعی ہوں اور جن کے پیش نظر بس ایک ڈراما اسٹیج کرنا ہو۔
پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ ہر حلقے اور ہرگوشے سے اقبال کی ایک نئی تعبیر ابھر رہی ہے۔ کم ہی لوگوں کو اس امر میں دلچسپی ہے کہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ہر کوئی اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی بات کی تائید میں اقبال کو پیش کرے اور خود اقبال کا حال آج یہ ہے کہ:
شد پریشاں خوابِ من از کثرت تعبیر
برگِ کل چوں بوئے خویش
جو حضرات اقبال کے ساتھ خلوص کا تعلق رکھتے ہیں، وہ فطری طور پر اس صورت حال پر کبیدہ خاطر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دانشوروں کے غوروفکر کے لیے چند معروضات پیش کریں:
پہلی بات تو یہ سامنے رہنی چاہیے کہ کسی ملک کے دانش وروں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ان کے کندھوں پر قوم کی ذہنی اور فکری قیادت کا بوجھ ہوتا ہے۔ اگر وہ سچائی کے پرستار اور حق کے خادم کا رول ادا نہیں کریں گے، تو اپنے فرض میں کوتاہی کریں گے، اور بہت سی گمراہیوں کے فروغ کا باعث ہوں گے۔ حقیقی دانش ور وہ ہیں جو خلوص اور احساسِ ذمہ داری کے ساتھ اپنا قومی فرض ادا کرتے ہیں، اور خوف اور لالچ سے اپنا دامن بچا کر قومی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔
وہ حضرات جو ’دان‘ کے چکر میں ’شور‘ مچاتے ہیں ان کو ’دانشور‘ نہیں کہا جاسکتا، خواہ ان کے نام کتنے ہی بڑے، القاب کتنے ہی لمبے، عہدے کتنے ہی اونچے اور اثرات کتنے ہی وسیع کیوں نہ ہوں۔ خواہ دنیا ان کے پیچھے ہو یا تماشا ان کے آگے! حقیقی دانش ور وہی ہیں، جن کی اصل دلچسپی حق اور سچائی کے ساتھ ہے، جو سچائی پر سنجیدگی سے غوروفکر کرتے ہیں۔ ایمان داری سے نتائج و آراء مرتب کرتے ہیں اور بے خوف ہو کر ان کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس قوم کا ضمیر ہیں اور اس کے حقیقی محسن۔ اس کی فکری زندگی انھی کے دم سے قائم ہے۔
ہم اس ملک کے پڑھے لکھے طبقے سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو محسوس کرے کہ قومی زندگی میں اہلِ دانش کا اصل کردار کیا ہونا چاہیے؟ اور پھر اس کردار کو ادا کرنے کے لیے اپنے کو تیار کرے۔ اس کے بغیر اس ملک میں کسی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا جاسکتا۔ اقبال کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص اسے اپنے مفید مطلب استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس کا روبار میں خلوص، فکری دیانت اور علمی وفاداری کو بڑی فراخ دلی سے قربان کیا جارہا ہے۔ یہ کھیل اسی وقت ختم ہو سکتا ہے، جب دانش ور اپنا فرض پہچانیں اور فکرِ اقبال کو کرگسوں کے اس حملے سے محفوظ کریں۔
ایک بلند آہنگ گروہ ایسا بھی ہے، جو اقبال کو تغیر اور تجدّد کے علم بردار کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے اور اس کا نام لے کر روایات کو توڑنے، ثقافتی اقدار کو پامال کرنے، منکرات و فواحش کو عام کرنے اور تمدنی ورثے کو دریا برد کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اسے اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ اس قسم کے تخریبی تجدد کے لیے اقبال نے بہ صراحت کیا کچھ کہا ہے اور اس وضاحت پر مبنی سب چیزیں اس کے کلام اور اس کی تحریرات میں محفوظ ہیں۔ اسی طبقے کو جو آج اقبال کا بہت بڑا کرم فرما ہے، وہ مخاطب کر کے کہتا ہے:
ترا وجود سرا پا تجلّیِ افرنگ
کہ تُو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر
مگر یہ پیکرِ خاکی خودی سے ہے خالی
فقط نیام ہے تُو، زرنگار و بے شمشیر
ایک گروہ وہ ہے، جس کا مسلک ہر چڑھتے سورج کی پوجا ہے۔ اسے آج کل اقبال کی شاعری میں جمہوریت کی مخالفت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔
ایک اور گروہ ’آشفتہ سر، آشفتہ خو‘ تھا۔ اس کی نگاہ میں اقبال اشتراکیت کاحامی اور سوشلسٹ انقلاب کا نصیب تھا۔ اس گروہ میں سے کچھ اتنے پردہ دار بھی تھے، جو اقبال کو ’ننگی اشتراکیت‘ کا نہیں ’اسلامی سوشلزم‘ کا علم بردار بتاتے رہے اور کچھ یہ پردہ بھی باقی نہیں رکھتے تھے۔ پھر حد یہ ہے کہ پیر، فقیر اور وزیر سب ہی سے یہ گروہ فائدہ اٹھا کر اقبال کے کندھوں پر سرخ پرچم لادنے میں مصروف رہا۔ اوربات قلم سے بڑھ کر فلم تک پہنچ گئی۔ نام اقبال کا ہے اور بات سرخ انقلاب کی۔
بلاشبہ اقبال کو مذہبی جمود اور تنگ نظری سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن وہ تجدد، آمریت، نسل پرستی، سرمایہ داریت، پیری، کٹھ مُلائیت، اشتراکیت سب کا مخالف تھا اور اس نے ان کے خلاف کھلی جنگ لڑی۔ اقبال کو ان میں سے کسی کی ہمنوائی میں پیش کرنا اقبال پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔
ہماری نگاہ میں اقبال کے ساتھ انصاف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اقبال پر بولنے اور لکھنے والے کم از کم ان تین باتوں کا خیال رکھیں:
۱- اقبال نہ تو محض ایک شاعر تھا اور نہ صرف ایک فلسفی اور انسانی زندگی سے الگ تھلگ مفکر۔ اس کی شخصیت بلاشبہ ان عناصر سے مل کر بنی ہے۔ اگر اس کو صرف ایک مفکر کی میزان پر پرکھا جائے گا تو بظاہر بہت سے تضادات نظر آئیں گے۔ اور اگر محض اسے ایک شاعر سمجھا جائے گا، تو اس کا اصل پیغام نگاہوں سے اوجھل رہے گا۔ شاعر کے سوچنے اور اپنے مدعا کا اظہار کرنے کا انداز خاص قسم کا ہوتا ہے۔ اس بات کو ملحوظ رکھے بغیر فکرِ اقبال کی گتھیاں نہیں سلجھائی جاسکتیں۔ اس لیے فہمِ اقبال کے لیے ضروری ہے کہ اس بنیادی حقیقت کوسامنے رکھا جائے۔
۲- اقبال کے کلام اور اس کی نثری تحریرات کا مطالعہ اقبال کے فکری، سیاسی اور تمدنی پس منظر اور اقبال کے ذہنی ارتقاء کے مراحل کی روشنی میں کیا جانا چاہیے۔ ان میں سے جس کو بھی جس قدر نظر انداز کیا جائے گا، اقبال کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ بلاشبہ اقبال، وطنی قومیت کا حامی بھی رہا ہے، لیکن یہ اس کی فکری ارتقاء کے اوّلیں مرحلے کی بات ہے۔ جس طرح اس نے کبھی اسکول میں بھی پڑھا تھا، اسی طرح اس کے کچھ افکار پر بھی طفولیت کا دور گزرا ہے۔ فکر کی پختگی کے ساتھ اس نے بہت سے تصورات کو بدلا ہے۔ ’نیا شوالا‘ بچہ کا لباس (BABY's FROCK) تھا، جسے ’’باقیات اقبال‘‘ کے میوزیم میں تو جگہ دی جاسکتی ہے، لیکن اقبال کی بالغ فکر میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ سوشلسٹ انقلاب روس کی چکا چوند میں شاعر مشرق کو بھی افق پر روشنی کی ایک کرن نظر آئی تھی، اور شاعر نے اپنے ان جذبات کو ’حجاب‘ میں نہیں رکھا بلکہ برملا اور واشگاف اظہار کرنے میں کوئی تاخیر نہ کی۔ لیکن جب چشمِ شاعر نے یہ دیکھا کہ سرخی بام و در مظلوموں کے خون کی پیدا کردہ ہے، تو اُفق پر رونما ہونے والی ننھی کرن تاریکیوں کو چھاٹنے سے پہلے ہی ان کے سینے میں دفن ہوگئی۔ اگر فکر ِاقبال کے مختلف ارتقائی مراحل کو سامنے نہ رکھا جائے تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور مخصوص مفادات کے پرستار اقبال کی فکر کو اس کے پس منظر سے کاٹ کر لوگوں کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سادہ لوح طالب علم بھی اس کی بنا پر غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اقبال کے ساتھ انصاف اسی وقت ہو سکتا ہے، جب اس کی فکر کو اس کے اصل پس منظر میں رکھ کر سمجھا جائے۔
۳- آخری اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اقبال کے مرکزی تصورات اور اس کے نظامِ فکر کو سمجھے بغیر اس کے مختلف اشعار کو سمجھنا محال ہے۔ کسی بھی شخص کے ساتھ انصاف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے مختلف افکار کو اس کے نظامِ فکر کے سانچے میں رکھ کر سمجھا جائے، اور تشریح و تاویل کے لیے خود اس کے افکار و تصورات ہی سے مدد لی جائے۔ کسی بھی فکر کو سمجھنے کے لیے یہ حددرجہ ضروری بھی ہے اور مفکر کے ساتھ دیانت کا معاملہ کرنےکے لیے بھی اہم تر۔
اگر ان تین بنیادی باتوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر اقبال کے ساتھ انصاف کیا جاسکتا ہے۔ وہ بھانت بھانت کی بولیاں بند ہو سکتی ہیں، جن کی وجہ سے فکری انتشار اور ژولیدگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
ہم اپنے ملک کے دانشوروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے اصل مقام کو محسوس کریں اور اقبال کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو حق و انصاف پر مبنی ہے۔
عالم عرب میں علّامہ محمد اقبال کے پہلے پہل تعارف کے سلسلے میں مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ [م: ۱۹۹۹ء]کی کتاب روائع اقبال کو زیادہ تر کریڈٹ دیا جاتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اس کتاب کے چند ایک مضامین اسلامی ادب کا شاہکار ہیںاور اپنی اثر انگیزی میں جواب نہیں رکھتے۔ روائع اقبال کا پہلا ایڈیشن دارالفکر، دمشق سے ۱۹۶۰ء میں شائع ہوا تھا۔ اس مجموعے سے پہلے مولانا ابوالحسن کا اقبال پر ایک مختصر سا کتابچہ شاعر الاسلام الدکتور محمد اقبال کے عنوان سے ۱۹۵۱ء میں دارالکتاب العربی، مصر سے شائع ہوا تھا۔ لیکن ان دونوں کتابوں سے بھی پہلے مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب کے رفیق مولانا مسعود عالم ندوی [م:۱۹۵۴ء]نے ہفت روزہ الرسالہ مصر کے ۸نومبر ۱۹۴۸ء کے شمارے سے محمد اقبال شاعر الشرق والاسلام کے عنوان سے مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جو پانچ قسطوں پر مشتمل تھا۔
الرسالۃ اُن دنوں استاد احمد حسن الزیات [م:۱۹۶۸ء]کی ادارت میں جاری عالم عرب کا سب سے معیاری ادبی پرچہ شمار ہوتا تھا۔ اس مجلے نے شیخ علی طنطاوی [م:۱۹۹۹ء] جیسے کئی عظیم ادیبوں کو دنیائے ادب سے روشناس کرایا تھا۔ اس زمانے میں کسی ادیب کی شہرت اور اعتبار کے لیے اس مجلے میں شائع ہونا کافی سمجھا جاتا تھا، جس طرح ہمارے یہاں اردو مجلات میں مولانا صلاح الدین احمد [م: ۱۹۶۴ء] کے ادبی دنیا لاہور کو کسی زمانے میں یہ حیثیت حاصل تھی، لیکن الرسالہ اپنے معیار میں اس سے کافی بلند تھا۔ مولانا مسعود عالم ندوی نے ۴۳ سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کیا، وہ زندگی بھر دمے کا شکار رہے۔ انھیں اس کی کمی کا سامنا رہا کہ چند رفقا کے علاوہ، ان کے احباب اور پھر اگلی نسل کو عربی زبان وادب سے سروکار نہیں ہے۔ عربی زبان میں بانی ٔجماعت اسلامی سیّدمودودی کی کتابوں کے جن تراجم نے شہرت ومقبولیت پائی تھی، ان میں سے کئی کتابیں مترجم کی حیثیت سے آپ کے نام کے بغیر بھی شائع ہوئیں۔
لہٰذا مسعود عالم صاحب کو عرب دُنیا میں وہ مقام نہیں مل سکا جس کے وہ بجا طور پر مستحق تھے۔ ]دراصل وہ اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، اُن کے تھوڑے کام کو بھی بہت بہتر بنا کر اُنھی کے نام سے پیش کرتے تھے، اور اکثر صورتوں میں اپنے نام کو شائع نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان تراجم کو مؤثر بنانے کے لیے بڑی محنت اور جاں کاہی سے کام لیتے تھے۔ س م خ[
مولانا ابوالحسن علی ندوی نے نقوش اقبال کے دیباچہ میں اپنے اس رفیق کے بارے میں لکھا ہے کہ ’’مولانا مسعود عالم صاحب کی اقبال کے بارے میں حمایت، حمیت تک پہنچی ہوئی تھی، وہ ان کے بڑے پُرجوش مبلغ تھے۔ انھیں یہ بات کھلتی تھی کہ ٹیگور [۱۸۶۱ء-۱۹۴۱ء] اقبال کے مقابلے میں بلاد عربیہ میں زیادہ روشناس ہیں‘‘۔ مولانا مسعود عالم ندوی نے اپنے اسی احساس کے جذبے سے اقبال پر اپنے سلسلۂ مضامین کا آغاز کیا ہے‘‘۔
اقبال خوش نصیب تھے کہ آپ کی زندگی ہی میں ڈاکٹر عبد الوہاب عزام [م:۱۹۵۹ء]کی شکل میں آپ کو عربی زبان کا ایک مترجم نصیب ہوا، جس نے آپ کے فارسی کلام کوعربی نظم میں ڈھال کر عام کیا۔ عزام کے ترجموں کے بارے میں یہ عمومی احساس پایا جاتا ہے کہ اگر وہ عربی نثر میں اقبال کا ترجمہ پیش کرتے تو یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا، اور اس سے اقبال کی بہتر ترجمانی ہوتی ،جس کا ایک نمونہ آپ کی نثر میں لکھی ہوئی کتاب محمد اقبال سيرته وفلسفته وشعره میں ملتا ہے۔ ویسے علامہ اقبال کی وفات سے تین سال قبل مصری مجلہ الرسالۃ میں سید ابوالنصر احمد الحسینی کے پانچ سلسلہ وار مضامین الدكتور محمد إقبال: فلسفۃ، معالم الاتفاق والاختلاف بينه وبين فلاسفة الغرب کے عنوان سے مارچ ۱۹۳۵ء میں شائع ہوئے تھے۔ سید ابوالنصر غالباً حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتے تھے۔
ہمارے خیال میں علامہ اقبال کی شاعری کو عالم عرب میں مقبول بنانے کا اصل سہرا، ڈاکٹر محمد حسن الاعظمی کو جاتا ہے۔کراچی میں ۱۹۴۹ء میں مؤتمر اسلامی کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اعظمی صاحب اس زمانے میں مؤتمر سے وابستہ تھے ۔ اس کا نفرنس کے انعقاد اور کامیابی کے لیے انھوں نے بھر پور کوششیں کی تھیں ۔آپ نے کانفرنس کے دوران عرب مندوبین کے لیے ترجمانی کا فریضہ انجام دیا۔ اس زمانے میں نواب زادہ لیاقت علی خان [م:۱۹۵۱ء] پاکستان کے وزیراعظم تھے۔ اس کانفرنس میں سیدامین الحسینی [م: ۱۹۷۴ء] مفتی اعظم فلسطین بھی شریک ہوئے۔ اس وقت پاکستان نیا نیا بنا تھا۔ وزرا اور سیاسی قائدین قومی خدمت اور ملک کو ترقی دینے کے جذبے سے سرشار تھے۔ اسلامی نظریۂ حیات کے بارے میں بھی بیش تر سیاست دان مخلص تھے۔ اعظمی صاحب قائدین کے نزدیک آ گئے اور انھوں نے ان حضرات کو عربی سیکھنے کی افادیت سے آگاہ کیا۔ سردار عبدالرب نشتر[م:۱۹۵۸ء] ،ڈاکٹرفضل الرحمٰن [م:۱۹۶۰ء] اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی [م:۱۹۸۱ء]جو مرکزی کابینہ میں وزیر تھے، اور خود وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان، اعظمی صاحب سے عربی سیکھنے لگے اور یہ سلسلہ چند ماہ تک جاری رہا۔
ڈاکٹر محمد حسن الاعظمی ۲۵ دسمبر ۱۹۲۲ء کو مبارک پور، اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے، اورآپ کی وفات ۸ستمبر ۱۹۹۵ء کو کراچی میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی عربی زبان وادب کی تعلیم مبارک پور، الجامعۃ السیفیۃ، سورت میں یمنی علما کے ہاتھوں ہوئی تھی، جس کے بعد آپ نے جامعہ ازہر میں داخلہ لیا، اوریہاں سے ۱۹۳۸ء میں درجہ اول امتیاز کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ سند کی حصول یابی کے اس مقابلے میں عالم اسلام کے ایک سو گیارہ اسکالرز شریک ہوئے تھے، اور ان میں سے صرف تیرہ اسکالرز کے حصے میں کامیابی آئی تھی، جن میں سے صرف آپ اکیلے غیر عرب تھے۔ یہ اعزاز پانے والے آپ پہلے ہندستانی تھے۔ ابھی علامہ اقبال زندہ تھے تو ۱۹۳۷ء ہی میں آپ نے آپ کے کلام کا عربی میں ترجمہ کرکے اسے عربی مجلات میں عام کرنا شروع کیا تھا۔
آپ کی زندگی کے دو ہی مقصد تھے: عربی زبان کی ترویج اور مسلمانوں میں باہمی بھائی چارہ، جس کے فروغ کے لیے آپ نے ۱۹۳۸ء میں جماعۃ الاخوۃ الاسلامیہ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تھی ، جس کے صدر ڈاکٹر عبدالوہاب عزام ، اور ممبران میں مشہور مفسر قرآن طنطاوی جوہری اور شیخ الازہر مصطفیٰ المراغی [م:۱۹۴۵ء]شامل تھے۔ طنطاوی جوہری نے وہ تمام کتابیں جو تفسیر الجواہر کی تصنیف میں استعمال ہوئی تھیں، اس ادارے کے کتب خانے کو وقف کردی تھیں۔
آپ پیدائشی طور پر بوہرہ اسماعیلی فرقے سے نسبت رکھتے تھے، لیکن سلطان بوہرہ برہان الدین کی شدید مخالفت کی وجہ سے آپ کو اپنے فرقہ سے نکال دیا گیا تھا۔ آپ نے سو سے زیادہ عربی و اردو تصانیف یادگار چھوڑیں۔ علاوہ ازیں ۱۹۳۹ء میں حکومت مصر کی ایما پر جامع ازہر کی ہزار سالہ تقریبات کی مناسبت سے آپ نے فاطمی حاکم امیر تمیم کا دیوان مرتب کیا۔شاہ فاروق کے دور میں آپ کی تحریک پر ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی دلچسپی سے جامعہ ازہر میں اردو زبان کا شعبہ پہلی مرتبہ کھولا گیا۔پانچ جلدوں میں آپ کی عربی اردو لغت المعجم الاعظم بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
آپ نے پہلے پہل بانگ درا کے مشہور ترانوں اور نظموں کا عربی نثر میں ترجمہ کیا تھا، جسے آپ کے دوست الصاوی علی شعلان[۱۹۰۲ء-۱۹۸۲ء] نے شعر میں ڈھالا۔ ان نظموں کو جو شہرت ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آسکی۔ان میں سے چند اہم نظمیں یہ ہیں: ’شکوہ‘، ’جوابِ شکوہ‘، ’فاطمۃ الزہراء صوت اقبال إلى الأمة العربية ، النشيد الإسلامي : الدِّينُ لَنَا وَالْعُرْبُ لَنَا وَالْهِنْدُ لَنَا وَالْكُلُّ لَنَا (چین وعرب ہمارا)۔ ان کے علاوہ بھی کئی نظمیں ہیں، جو ایک زمانے میں عرب بچوں کے نوکِ زبان تھیں اور ابتدائی اور ثانوی درجات میں کورس میں ترانے کی حیثیت سے گائی جاتی تھیں۔
ان نظموں کا مجموعہ ایک طویل عرصہ بعد ان دونوں کے اشتراک سے فلسفۃ اقبال والثقافۃ الاسلامیہ فی الھند والباکستان کے عنوان سے ۱۹۵۰ء میں عیسٰی البابی الحلبی سے شائع ہوکر مقبولِ عام ہوا۔ اس مجموعے میں اقبال کے کلام کے علاوہ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبیؐ کے شاہکار دیباچہ کا ترجمہ ، اور علامہ سید سلیمان ندوی کی سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعارف، اور دوسرے بہت سے دلچسپ مضامین شامل ہیں۔ پروفیسر محمد حسن الاعظمی نے بانگ درا کی ان نظموں کو پہلے نثر میں ترجمہ کیا تھا، پھر اسے الصاوی علی شعلان نے نظم میں ڈھالا۔ ان نظموں میں یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اقبال کی اردو نظم اور اس کے عربی ترجمے میں سے کون سی زیادہ پُرجوش اور مؤثر ہے۔ان نظموں میں ’شکوہ‘ اور ’جوابِ شکوہ‘ جسے عربی زبان میں حدیث الروح نام دیا گیا تھا، مقبول ترین نظم ہے۔
اس کے سلسلے میں ڈاکٹر عقیل عباس جعفری لکھتے ہیں: ۱۹۶۷ءمیں عرب اسرائیل جنگ کے بعد عوام کے جذبات اور احساسات کے پیش نظر اُمِ کلثوم [م:۱۹۷۵ء]نے ایک نیا نغمہ تیار کیا۔ ان کی آواز سامعین کو سرخوشی میں مبتلا کرتی تھی مگر اس روز وہ جو نغمہ گا رہی تھیں وہ غیر روایتی نغمہ تھا۔ حدیث الروح کے نام سے گایا جانے والا یہ نغمہ علامہ اقبال کی نظم ’شکوہ‘ کا الصاوی الشعلان کے ہاتھوں منظوم عربی ترجمہ تھا۔ جس کا آہنگ ریاض الضباطی نے ترتیب دیا تھا۔ اللہ کے حضور مسلمانوں کی زبوں حالی کا یہ شکوہ کروڑوں عرب عوام کے دل کی دھڑکن بن گیا۔ الصاوی علی الشعلان، بینائی سے محروم تھے اور فارسی میں ایم اے کی سند کے علاوہ اردو پر بھی کمال دسترس رکھتے تھے۔ ان سے قبل پاکستان میں مصر کے سابق سفیر عبدالوہاب عزام نے بھی اقبال کے فارسی اور اردو کلام کو عربی میں منتقل کیا تھا، مگر اہل عرب میں عوامی سطح پر اقبال کا تعارف بہرحال اُمِ کلثوم کی بدولت ہوا۔ اُم کلثوم کے اس نغمے کی شہرت جب پاکستان تک پہنچی تو حکومت وقت نے ۱۸ نومبر۱۹۶۷ء کو انھیں ستارۂ امتیاز عطا کرنے کا اعلان کیا، جو ۲؍ اپریل ۱۹۶۸ء کو انھیں ایک خصوصی تقریب میں مصر میں پاکستان کے سفیر سجاد حیدر نے عطا کیا۔
اُمِ کلثوم کی خواہش تھی کہ اقبال کی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نظم کو بھی اسی طرح اسٹیج پر پیش کرے لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ ایک زمانہ تھا کہ عالم عرب کے ریڈیو اسٹیشنوں سے ہرجمعہ کو اُمِ کلثوم کی آواز میں قصائد، ولد الھدٰی، نہج البردہ، اشرق البدر باری باری نشر ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک اقبال کی حدیث الروح بھی تھی۔ تین ہفتوں کے وقفے سے پابندی سے بروزِجمعہ ایک بجے آتے جاتے ہوئے چائے خانوں میں ریڈیو دوبئی سے اسے بجتے ہوئے سالہاسال تک ہم نے سنا ہے۔ ان دونوں کے اشتراک سے ایک اور مجموعہ الاعلام الخمسہ للشعر الاسلامی کے عنوان سے بھی شائع ہوا تھا۔ اس میں عطار، سعدی، رومی ، حافظ اور اقبال کے منتخب اشعار کا عربی ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔
برصغیر میں استاد محمد حسن الاعظمی کے ہاتھوں عربی زبان کے فروغ اور عالم عرب میں ہندستانی مصنّفین کے تعارف کے لیے کی گئی خدمات کا کماحقہٗ تعارف نہیں ہوا۔ ڈاکٹر محمد حسن الاعظمی کو اب شاذو نادر ہی جانا جاتا ہے۔ ان کی پانچ جلدوں میں لکھی المعجم الاعظم بھی شاید ایک سے زیادہ مرتبہ نہ چھپ سکی، اور وہ طلبۂ مدارس عربیہ میں متعارف نہ ہوسکی۔
سرینگر، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مکھن دین نامی نوجوان ضلع کٹھوعہ، کشمیر کی ایک خالی مسجد میں کھڑا اپنے موبائل فون پر آخری ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہا ہے۔سر پر ٹوپی اور نیلے اور سفید رنگ کی اسپورٹس جیکٹ پہنے، یہ ۲۵سالہ باریش نوجوان کہتا ہے: ’’میں اپنی جان ’قربان‘ کرنے جا رہا ہوں تاکہ خطّے میں کسی اور کو پولیس کے ’تشدد‘ کا سامنا نہ کرنا پڑے‘‘۔ پولیس نے اس پر ’شدت پسندوں سے وابستگی‘ کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ —یہ وہ اصطلاح ہے جو بھارتی حکمرانی کے خلاف برسرِ پیکار نوجوانوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
۵ فروری کو ریکارڈ کیے گئے اس چار منٹ کے دھندلے ویڈیو کلپ کے درمیان، اس نوجوان کو ایک شیلف سے قرآن اٹھاتے اور اسے اپنے سر پر رکھ کر قسم کھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ ’’میں نے کبھی کسی باغی کو نہیں دیکھا‘‘۔ وہ بیان کرتا ہے کہ پچھلی رات پولیس حراست میں اس پر کیا بیتی۔ پھر وہ قرآن کو واپس رکھ دیتا ہے اور مسلسل دعا کرتا رہتا ہے۔
’’میں مر جاؤں گا تاکہ میرے بعد دوسرے لوگ بچ جائیں۔ یااللہ! میری قربانی قبول فرما۔ میری فیملی کو ہمیشہ خوش رکھ، یا اللہ! مجھے قبر کے عذاب سے بچا… تو سب کچھ دیکھ رہا ہے… فرشتے بھیج جو میری روح مسجد سے لے جائیں۔ یااللہ! مجھے معاف کر دے‘‘۔وہ اتنا کہہ کر کیمرہ بند کر دیتا ہے۔
۷ فروری کو جاری کردہ ایک بیان میں، کشمیر پولیس نے دعویٰ کیا کہ: مکھن دین کے پاکستان اور دیگر غیر ملکی ممالک میں متعدد مشکوک روابط تھے۔ اس پر تشدد نہیں کیا گیا۔ اس سے تفتیش کی گئی، وہ گھر گیا، اور خودکشی کرلی۔ جموں ضلعی انتظامیہ دین کی خودکشی اور مبینہ تشدد کی تحقیقات کر رہی ہے۔
دوسری جانب، دین کا ویڈیو پیغام خطے کے اندر اور باہر لاکھوں موبائل فونز اور ٹی وی اسکرینوں تک پہنچ چکا تھا، جس نے کشیدگی کو بڑھا دیا اور وادیٔ کشمیر میں ہونے والے تشدد اور دیگر مظالم کی تلخ یادیں تازہ کر دیں۔ یہ وہ خطّہ ہے جہاں عشروں سے مسلح بغاوت جاری ہے۔
۱۹۴۷ء میں برطانوی راج سے آزادی اور تقسیم کے بعد، پورے کشمیر پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس پر تنازعہ پیدا ہوا۔ دونوں جوہری طاقتوں نے اس متنازع علاقے پر تین بڑی جنگیں لڑی ہیں اور اس کی برف پوش سرحدوں پر دسیوں ہزار فوجی تعینات ہیں۔ انڈیا، پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ بھارتی کشمیر میں جاری بغاوت کو تربیت اور مدد فراہم کرتا ہے۔ تاہم، اسلام آباد اس الزام کو مسترد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صرف بین الاقوامی سطح پر سفارتی حمایت فراہم کرتا ہے۔ انڈیا نے وادیٔ کشمیر میں۵[۸] لاکھ سے زائد فوجی تعینات کر رکھے ہیں، جس سے یہ دنیا کے سب سے زیادہ عسکری علاقوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ انڈین افواج کو وہاں خصوصی اختیارات اور استثنا حاصل ہے تاکہ وہ بغاوت کو کچل سکیں۔
مقامی باشندے کہتے ہیں کہ ۲۰۱۹ء کے بعد سے نئی دہلی نے خطے پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی ہے، جس سال نریندر مودی کی حکومت نے بھارتی آئین کے آرٹیکل ۳۷۰ [اور ۳۵-اے] کو منسوخ کر دیا، جو بھارتی کشمیر کو کچھ حد تک خودمختاری دیتا تھا، اور خطے کو دو وفاقی علاقوں —جموں و کشمیر اور لداخ —میں تقسیم کر دیا۔ حکومت نے دعویٰ کیا کہ ’’اس اقدام سے خطے میں ’معمول کی صورتِ حال‘، امن اور ترقی آئے گی‘‘، لیکن کشمیریوں کو خدشہ ہے کہ نئی دہلی کی طرف سے بنائے گئے نئے قوانین اور پالیسیوں کا مقصد مسلم اکثریتی آبادی کے تناسب کو بدلنا ہے۔
۲۰۱۹ء کے اس اقدام کے بعد مہینوں تک سکیورٹی لاک ڈاؤن اور عوامی احتجاج پر پابندی بھی عائد کر دی گئی، جب کہ ہزاروں افراد، —طلبہ، وکلاء، کارکنان، حتیٰ کہ بھارت نواز سیاست دان بھی —جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ لیکن پانچ سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود، اس خطّے کی بے چین سڑکوں پر حقیقی امن تاحال نظر نہیں آتا۔
مگر مکھن دین کا مبینہ پولیس تشدد کے بعد خودکشی کا واقعہ شہریوں میں خوف کو مزید بڑھا رہا ہے۔ ایک ۲۲ سالہ نوجوان نے، جو انتقامی کارروائی کے خوف سے نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا، کہا: ’’یہ خوفناک تھا کہ ایک شخص نے خودکشی جیسا انتہائی قدم اٹھایا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک سنگین گناہ ہے۔ ہمارا مذہب [اسلام] ہمیں اس عمل سے سختی سے روکتا ہے‘‘۔
اس نوجوان نے مزید کہا کہ ’’دین کے اس دل دہلا دینے والے اقدام نے میرے اعتماد کو ہلاکر رکھ دیا ہے‘‘۔میں اس تکلیف کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو اس نے برداشت کی ہوگی۔ ایسے واقعات کے بارے میں یہاں کم ہی بات کی جاتی ہے۔ زیادہ تر خبریں اب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتیں۔ کشمیر میں وقت بدل چکا ہے‘‘۔’’یہ درحقیقت ایک اختتام کا آغاز ہے‘‘۔
مکھن دین کی خودکشی کے اگلے ہی دن، ۳۲ سالہ وسیم احمد میر، جو شمالی کشمیر کے ضلع سوپور سے تعلق رکھنے والا ایک ٹرک ڈرائیور تھا، بھارتی فوج کے ہاتھوں گولی کا نشانہ بنادیاگیا۔ فوج کے بیان کے مطابق: وسیم میر نے سری نگر -بارہ مولہ ہائی وے پر ایک سکیورٹی چوکی عبور کی اور رُکنے کے احکامات کو نظرانداز کیا۔ فوج نے دعویٰ کیا کہ ٹرک کا ۲۳ کلومیٹر تک پیچھا کرنے کے بعد اسے گولی مار دی گئی۔تاہم، میر کے اہلِ خانہ نے فوج کے اس موقف کو مسترد کر دیا۔
فوج کہتی ہے کہ انھوں نے ۲۳ کلومیٹر تک پیچھا کیا، جب کہ [سپرنٹنڈنٹ آف پولیس] نے ہمیں بتایا کہ تعاقب ۳۵ کلومیٹر تک کیا گیا۔ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جب اسے سری نگر جانا تھا تو گاڑی مخالف سمت بارہ مولہ کی طرف کیوں جا رہی تھی؟” میر کے ایک کزن نے انڈین ایکسپریس اخبار کو بتایا، اور فوج اور پولیس کے بیانات میں تضاد کی نشاندہی کی: اس کے کپڑے مٹی میں لت پت تھے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اسے مارا یا تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، قتل سے پہلے؟‘‘
بھارتی فورسز کے مبینہ مظالم کے نتیجے میں ان دو عام شہریوں کی ہلاکت ایسے وقت میں ہوئی جب ۵۰۰ سے زائد کشمیریوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ یہ گرفتاریاں ۳ فروری کو ’’جنوبی کشمیر کے کولگام میں ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کے قتل کے بعد عمل میں آئیں، جسے مشتبہ باغیوں نے گولی مار دی تھی، جب کہ اس کی بیوی اور بھانجی زخمی ہو گئی تھیں۔
قتل کے بعد حکام نے جنوبی کشمیر کے کئی اضلاع میں نوجوانوں کو پکڑنا شروع کر دیا، جن میں سے زیادہ تر پہلے ہی حکومت مخالف احتجاج یا مسلح بغاوت میں ملوث ہونے کے الزامات کا سامنا کر چکے تھے۔ مختلف سکیورٹی چوکیوں پر گاڑیوں اور لوگوں کی تلاشی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔
پلوامہ کے ایک ۲۱ سالہ نوجوان نے بتایا:’’حالیہ کریک ڈاؤن کے بعد میں خوف زدہ ہوں، کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی کشمیر میں سکون سے نہیں زندہ رہ سکتے۔ یا تو ہمیں مسلسل خوف میں رہنا ہوگا، یا پھر یہاں سے چلے جانا ہوگا۔ آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ کب اور کس وقت فوج آکر آپ کو اٹھا لے، اور پھر آپ کو بے گناہ ہونے کے باوجود تکلیف اٹھانی پڑے‘‘۔
اس نوجوان نے مزید کہا:’’یہاں بہت زیادہ خوف ہے۔ کئی نوجوانوں کو فوجی کیمپوں سے کالیں آ رہی ہیں، انھیں ’طلب‘ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب انتہائی دہشت زدہ کر دینے والا ماحول ہے۔
اُوپر سے، گھریلو دباؤ بھی ہے۔ ہمارے خاندان خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی گھر سے نکلتا ہے، تو یہ یقینی نہیں ہوتا کہ وہ پھر واپس آئے گا یا نہیں؟ اگر ہمیں یہاں رہنا ہے، تو ہمیں ہروقت تیار رہنا ہوگا کہ جب وہ بلائیں، ہم فوراً حاضر ہو جائیں‘‘۔
صحافتی حلقوں کی جانب سے کئی ایسے افراد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی جو حالیہ دنوں میں حراست میں لیے گئے تھے یا جن سے پوچھ گچھ ہوئی تھی، لیکن ایسے نوجوانوں نے ’نتائج‘ کے خوف سے میڈیا سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔
ایک سابقہ حراستی قیدی نے کہا:’’مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے رہا ہوا؟ میرا ذہن فی الحال آزاد ہے، لیکن اگر میں بات کروں گا، تو ایک اور خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ مجھے دوبارہ پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ میں نے آپ سے بات کی ہے‘‘۔
جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع سے تعلق رکھنے والے وکیل اقبال نے کہا کہ ’’پولیس کو کسی کو بھی ’شک‘ کی بنیاد پر حراست میں لینے کا اختیار حاصل ہے، لیکن یہ حراست ۲۴ گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس دوران، مشتبہ شخص کو عدالت میں پیش کرنا اور گرفتاری کی وجوہ اس کے اہل خانہ کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔۵۰۰ کے قریب لوگوں کو حراست میں لینا، جیسا کہ رپورٹ کیا گیا ہے، قانون کی صریح خلاف ورزی اور پولیس کے اختیارات کے ناجائز استعمال کی مثال ہے۔ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ زیرِ حراست افراد کے حقوق اور ان کے لیے دستیاب قانونی تحفظات کی خلاف ورزی کی جاتی ہے‘‘۔
ممبئی کے مصنف اور انسانی حقوق کے کارکن رام پونیانی نے کہا:’’پولیس محض شک کی بنیاد پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو حراست میں نہیں لے سکتی۔ ضرور کوئی قانونی اصول ہوگا جس کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مگر یہ تو واضح طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے‘‘۔
عام شہریوں کی اموات اور بڑے پیمانے پر گرفتاریوں نے کشمیری سیاستدانوں میں بھی شدید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے، جنھوں نے نئی دہلی کے اس دعوے پر سوال اٹھایا ہے کہ’’اگست ۲۰۱۹ء کے بعد کشمیر میں معمول کی صورتِ حال بحال ہو چکی ہے‘‘۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما التجا مفتی نے بیان دیا: ’’خدشہ یہ ہے کہ پولیس وہی قانون توڑ رہی ہے جس کی وہ حفاظت کرنے کی پابند ہے۔ نتیجتاً، لوگ پولیس ہی سے خوف زدہ ہیں، نہ کہ عسکریت پسندوں سے۔ یہ ایک انتہائی بگڑا ہوا نظام ہے‘‘۔
۲۰۱۹ء کے بعد کشمیر میں وزیر اعلیٰ کے اختیارات کو سختی سے محدود کر دیا گیا ہے، اور اب پولیس براہِ راست وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے چیئرمین آکار پٹیل نے کہا کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کے انسانی حقوق میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔
بھارتی پارلیمنٹ میں کشمیری رکنِ پارلیمان شیخ عبدالرشید نے وسیم میر اور مکھن دین کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا:’’ہمارا خون سستا نہیں‘‘، ’’ہمیں بھی جینے کا حق حاصل ہے‘‘۔
۱۹۴۷ ء سے مسئلہ کشمیر لاینحل چلا آرہا ہے اور امن سے محروم بھی۔ اس کی وجہ بھارت کی مسلسل بدنیتی اور بدعہدی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ بدامنی بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ الحمدللہ! آزاد کشمیر میں تو مکمل امن وامان ہے، لوگ محفوظ اور اطمینان سے معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وادیٔ کشمیر جنت نظیر، آبشاروں اور جھرنوں کی سرزمین ،مشک نافہ ،زعفران اور پھولوں کی سرزمین ظلم وستم کی آگ میں جل رہی ہے۔ لوگ تقریباً ۸۰ سال سے ظلم وستم اور جبر کا شکار ہیں اور آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ۱۹۴۸ء میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ’استصواب رائے‘ کے انعقاد کے فیصلے کے باوجود بھارت کشت وخون میں مصروف ہے۔ تقریباً آٹھ لاکھ فوج کے ذریعے ڈھٹائی سے تباہی مچارہا ہے، خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے ہیں لیکن مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو رہا ہے۔
ان اسبا ب کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے پاکستان کا موقف برحق ہونے کے باوجود اقوام عالم میں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مشرقی اور جنوبی سوڈان میں مختصر مدت کی جدوجہد کامیابی سے ہم کنار ہو گئی تھی، پھر کیا وجوہ ہیں کہ کشمیر میں ۷۰ سال سے جاری جدوجہد اور ۳۵ سال سے جاری کشت وخون کو اقوام عالم نے قرار واقعی مقام نہیں دیا؟
۱- ماضی میں کی جانے والی کمزور اور نااہل سفارت کاری کی وجہ سے دوسرے ممالک میں برسرِاقتدار اور حزب اختلاف کے مؤثر قائدین اور ذرائع ابلاغ کے اہم نمائندوں کو مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے برحق موقف پر قائل کرنے میں کوتاہی ہوتی رہی ہے۔ سفارش پر میرٹ کے بغیر تقرریاں اور تعیناتیاں اور وزارت خارجہ کے افسران کی مسئلے پر پوری تربیت نہ ہونا اس کی بنیادی وجہ ہے جس کا تدارک ضروری ہے۔
۲- سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کی باہمی رنجشیں ،جوڑتوڑ اور سازشیں عام رہی ہیں۔ قومی مفاد کے بجائے ذاتی مفاد کے لیے پارٹیاں بدلنا معمول رہا ہے، جس کے نتیجے میں قومی کریکٹر پروان نہیں چڑھ سکا اور دنیا میں بھی ہمارے ملک کا تاثر خراب ہوا۔ ملک کا اعتبار اور وقار مجروح ہوا اور ہمارے موقف کو اہمیت نہ ملی۔
۳- ملک میں مسلکی اختلاف رائے کے بجائے فرقہ واریت کا فروغ ہماری بدنامی کا باعث بنا۔ اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے بھارت نے سازش کے ذریعے منصوبہ بنایا جس کی نشان دہی معروف صحافی افتخار گیلانی نے ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن لاہور، ماہ جنوری ۲۰۲۲ء میں شائع شدہ مضمون میں کی ہے کہ دہلی کے قریب ایک زرعی فارم پر قائم دینی مدرسے میں جنونی ہندونوجوانوں کو مسلمان علمائے دین کے بھیس میں تیار کر کے پاکستان میں مختلف فرقوں کی مساجد میں پلانٹ کیا گیا یا نئی مساجد قائم کی گئیں یا پیرخانے قائم کیے گئے جہاں بیٹھ کر لوگوں کو دوسرے مسالک کے خلاف مشتعل کیا جاتا رہا ہے۔ فرقوں کی آپس کی لڑائیوں اور کشت وخون نے دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا۔ اس کا اثر بھی ہمارے موقف کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ اس کا حل یہ ہے کہ تمام مسالک کے رہنما اپنے اپنے موقف پر لچک دار اور برداشت کا رویہ اپنائیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا کریں، تا کہ ملک کی بدنامی ختم ہو سکے۔
۴- کمزور معیشت اور بیرونی قرضے بھی دنیا میں ہمارے وقار اور عزت واحترام کے خاتمے کا سبب بنے ہیں۔ کمزور ملک کو دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ملتی اور نہ اس کی بات سنی جاتی ہے اور اس کو حمایت کم ہی ملتی ہے۔
۵- ۱۹۷۹ء کے بعد دنیا میں اسلامو فوبیا کو اُبھارا گیا۔ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف شدت پسند عیسائیوں ،یہودیوں اور بدھوں کے ساتھ بھارتی نسل پرست ہندو بھی شامل ہوگئے، جو قیام پاکستان سے بھی پہلے سے مسلم دشمنی میں ملوث تھے۔ کشمیر پر پاکستان کی آواز صدا بہ صحرا ثابت ہونے کی ایک وجہ اسلامو فوبیا بھی ہے۔
۶- بھارت بہتر ڈپلومیسی ،سفارت کاری ،مستحکم معیشت، اسرائیل کی مدد سے امریکا سے معاشی فوائد کا حصول اور امریکی اداروں میں سرایت اور متعدد عہدوں پر تعیناتی سے دنیا میں اور بالخصوص امریکا میں اثرورسوخ کا سبب بنا اور کشمیر کے کمزور موقف پر حمایت حاصل کر لی۔
ان اسباب اور عوامل کے علاوہ کچھ اور اسباب وعوامل بھی ہیں۔کشمیریوں کی جدوجہد اور مذکورہ بالا اسباب سے عہدہ برآ ہونے کے نتیجے کے طور پر ان شاء اللہ کشمیریوں کی برحق جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستانی سیاسی اور دینی رہنمائوں کو ان اسباب کے پیش نظر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال کے عثمانیوں کی ابتلا کے سلسلے میں کہے گئے شعر میں معمولی تصرف کرتے ہوئے کہوں گا ؎
اگر ’کشمیریوں‘ پر کوہِ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے
کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا
۱۸مارچ کو سحری کے وقت تباہ حال غزہ پہ بغیر کسی وارننگ کے اسرائیلی فضائیہ نے سو سے زیادہ جنگی جہازوں سے بمباری کرکے۲۷۹ معصوم بچوں سمیت ۴۲۹ ؍ افراد کو شہید اور ۵۳۰ کو زخمی کردیا۔ اسرائیل نے اس بار حماس کی غیر فوجی قیادت کو نشانہ بنا تے ہوئے غز ہ میں حکومت کی نگران کمیٹی کے سربراہ عصام الدعلیس، حماس کے سیاسی بیورو کے رکن یاسر حرب، وزارت انصاف کے انڈرسیکرٹری، احمد الحطا، وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری میجر جنرل محمود ابو وفا اور انٹرنل سیکورٹی سروس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بہجت ابو سلطان کوشہید کردیا۔ ان کے علاوہ اسلامی جہاد کے ناجی ابو سیف عرف ابو حمزہ نےبھی اپنےخاندان کے متعدد افراد کے ساتھ جام شہادت نوش کیا ۔
اس پر حماس نےیہ بیان دیا: ’’ہم اپنےعوام، سرزمین اور اپنے مقدس مقامات کے دفاع کے لیے ثابت قدمی اور شہادت کی تمنا کے ساتھ دشمن کی جارحیت میں شہید ہونے والے رہنماؤں کی شہادت پر سوگ کا اعلان کرتے ہیں‘‘۔ فلسطینی عوامی قائدین کا یہ عظیم گروپ لوگوں کے ساتھ ثابت قدمی، استقامت اور یک جہتی کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما رہا ۔ اس نے اپنے لوگوں کی خدمت، ان کی سلامتی اور سماجی استحکام کو مضبوط بنانے میں اَ ن تھک محنت کی شاندار مثال قائم کی۔ حماس نے زور دیا کہ ’’یہ جرائم فلسطینی عوام کی خواہش یا ان کی قیادت اور مزاحمت کے ساتھ ان کی مضبوط یک جہتی کو نہیں توڑسکیں گے۔ یہ جارحیت ہماری قوم کے عزم اور ثابت قدمی کو مزید مضبوط کرے گی‘‘۔حماس کے مطابق: ’’امریکی انتظامیہ کا یہ اعتراف کہ اسے صہیونی جارحیت کے بارے میں پیشگی مطلع کر دیا گیا تھا، فلسطینیوں کی نسل کشی میں شراکت داری کا واضح ثبوت ہے۔ واشنگٹن کی لامحدود سیاسی اور فوجی مدد نے امریکا کوغزہ میں خواتین اور بچوں کے قتل عام کےجرم میں برابر کا شریک ثابت کیا ہے‘‘۔
اسرائیل کی داخلی سیاست سے جو لوگ واقف ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچانک نتین یاہو پر یہ درندگی کا جنون کیوں سوار ہوگیا؟ امریکا کے معروف ماہر معاشیات پروفیسر جیفری شاس نے نیتن یاہو کو گہرے کالے کتے سے تعبیر کیا تھا اور اس ویڈیو کو اپنے ٹوئٹر ہینڈل سے شیئر کرکے امریکی صدر نے بلا واسطہ اس کی تائید کردی تھی۔ اسی درندہ صفت نیتن یاہو سے یہ ظالمانہ حرکت کروائی ۔ یاہو کی پہلی مجبوری اپنی اقلیتی حکومت کا تحفظ ہے۔ اس کو سہارادینے والے امن کی دشمن جنگ پسند پارٹیاں ہیں۔
فلسطینی وزارتِ خارجہ نے ان حملوں کو غزہ کی تعمیرِ نو کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں خلل ڈالنے کی ظالمانہ حرکت قرار دیا اور کہا ہے کہ سیاسی حل ہی امن کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ الجزیرہ نے اسرائیلی حملوں کو غیرانسانی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔
ان حملوں نے خطّے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔
یاد رہے اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ یہ آپریشن غیرمعینہ مدت تک جاری رہے گا اور اس میں مزید شدت آئے گی۔ اب اسرائیل، حماس کے خلاف مزید فوجی طاقت کے ساتھ کارروائی کرے گا۔ اسرائیلی رائے عامہ میں ایک قابلِ ذکر تعداد اس حملے کی مخالف ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پُرامن طریقے سے مسائل حل ہوں، جب کہ نیتن یاہو کا فاشسٹ ٹولہ غزہ میں مکمل نسل کشی پر تُلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ ٹولا اسلحے کے ساتھ ساتھ، پانی، خوراک، ادویات اور چھت کو چھین کر، مظلوم فلسطینیوں کی زندگی تباہ کرنے کے خوفناک منصوبے پر عمل کر رہا ہے۔ اسرائیل کی اس تازہ درندگی کا جو بھی پس منظر ہو، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اسے مسلم دُنیا کی طرف سے کسی دبائو کا سامنا نہیں اور امریکا کی اندھی سرپرستی اس کی درندگی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ کے یک طرفہ غزہ قبضہ منصوبے کے جواب میں، ۵۷ رکنی اسلامی تعاون تنظیم (OIC) نے ایک کثیرجہتی تعمیر نو منصوبہ منظور کیا، جس کی قاہرہ میں عرب لیگ کے اجلاس نے بھی توثیق اور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح فرانس، جرمنی، اٹلی (یورپی یونین کے رکن ممالک) اور برطانیہ نے اس منصوبے کی حمایت کی ہے۔
ٹرمپ کے نام نہاد’غزہ رویرا‘ منصوبے کے برعکس، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، او آئی سی کا تجویز کردہ منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی بالادستی کو تسلیم کرتا ہے، جب کہ ٹرمپ کے منصوبے میں ۲۴ لاکھ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی شامل ہے۔ او آئی سی کا کثیرالملکی منصوبہ غزہ کو تعمیرِ نو کے ذریعے بحال کرنے کا خواہاں ہے، بغیر کسی مقامی باشندے کی نقل مکانی کے۔
اسی طرح جنگ کے بعد غزہ کی تعمیرِ نو کے حوالے سے امریکا، عرب ممالک اور یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں۔
قاہرہ سمٹ (۴ مارچ) میں عرب رہنماؤں نے غزہ کی تعمیرِ نو کے لیے ۵۳ بلین ڈالر کے مصری منصوبے پر اتفاق کیا، جس کا بنیادی نکتہ ۲۴ لاکھ فلسطینیوں کی نقل مکانی کو روکنا ہے۔ اس کے بعد، ۷مارچ کو جدہ، سعودی عرب میں منعقدہ ’اسلامی تعاون تنظیم‘ کے ہنگامی اجلاس میں اس عرب متبادل منصوبے کو باضابطہ طور پر منظور کیا گیا۔
یہ منصوبہ ایک آزاد تکنیکی کمیٹی کے ذریعے غزہ کا چھ ماہ تک انتظام سنبھالنے کے بعد اختیار منتقل کرنے کی تجویز پیش کرتا ہے۔
’اسلامی تعاون تنظیم‘ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے مطابق: تنظیم نے غزہ کی ’جلد بحالی اور تعمیرِ نو‘ کے منصوبے کو اپنایا اور بین الاقوامی برادری، مالیاتی اداروں اور خطے کے فنڈنگ ذرائع سے فوری امداد کی اپیل کی۔مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کے مطابق: ’’او آئی سی کے ہنگامی وزارتی اجلاس نے مصری منصوبے کو اپنا لیا ہے، جو اَب ’عرب-اسلامی منصوبہ‘ بن چکا ہے۔ اگلا قدم یہ ہوگا کہ اس منصوبے کو یورپی یونین اور دیگر عالمی قوتوں جیسے جاپان، روس اور چین کی منظوری حاصل ہو، تاکہ اسے بین الاقوامی منصوبہ بنایا جا سکے‘‘۔
علاوہ اَزیں، پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے زور دیا:’’او آئی سی کو اجتماعی طور پر فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی ہر کوشش کی مزاحمت کرنی چاہیے، چاہے وہ انسانی ہمدردی کے پردے میں ہو یا تعمیرِ نو کے بہانے۔ اور یہ کہ فلسطینیوں کی بے دخلی کو ’سرخ لکیر‘ تصور کیا جائے، کیونکہ یہ نسل کشی کے مترادف ہے اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے‘‘۔ انھوں نے اقوامِ متحدہ کے ادارے UNRWA کے فلسطینیوں کی بحالی میں کردار کو بحال کرنے پر بھی زور دیا اور نشاندہی کی کہ اسرائیل پر یہ قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل ۲(۵) کے تحت فلسطینیوں کو انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی کو یقینی بنائے‘‘۔
’اسلامی تعاون تنظیم‘ کے منظور کردہ منصوبے کا بنیادی مقصد تباہ حال غزہ کی تعمیرِ نو اور ’فلسطینی اتھارٹی‘ (PA) کے فعال کردار کے ذریعے وہاں امن و استحکام قائم کرنا ہے۔
اس منصوبے کے تحت، پانچ سال میں غزہ کی تعمیر نو کے تین مراحل مکمل کیے جائیں گے:
عرب منصوبے کے تحت ایک ’انتظامی کمیٹی‘ قائم کی جائے گی، جو آزاد فلسطینی ماہرین پر مشتمل ہوگی اور عبوری مدت کے دوران غزہ کا انتظام سنبھالے گی، تاکہ فلسطینی اتھارٹی کو مکمل اختیار کی منتقلی ممکن ہو سکے۔
’اسلامی تعاون تنظیم‘ کے طویل مدتی منصوبے کے مطابق، ۲۰۳۰ء تک غزہ میں لاکھوں نئے مکانات، ایئرپورٹ، صنعتی زون، ہوٹل اور پارک بنائے جائیں گے اور اسے ایک جدید، خودمختار فلسطینی علاقہ بنایا جائے گا، جہاں فلسطینی اتھارٹی کی حکمرانی ہوگی۔
’فلسطینی اتھارٹی‘ (PA) اور حماس نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ’’غزہ کو عبوری طور پر آزاد ماہرین کی کمیٹی کے ذریعے چلایا جائے اور وہاں بین الاقوامی امن دستے تعینات کیے جائیں‘‘۔
تاہم، امریکا اور اسرائیل نے ’اسلامی تعاون تنظیم‘ کے اس تعمیرِ نو منصوبے کو مسترد کر دیا ہے، جو امریکی-اسرائیلی غزہ قبضہ پالیسی کے خلاف ایک کثیرالملکی مزاحمتی حکمت عملی کا نمونہ ہے۔
امریکا اور اسرائیل کی ہچکچاہٹ کے باوجود، صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے خصوصی ایلچی، اسٹیو وٹکوف نے بعد میں کہا کہ ’’یہ مصریوں کی جانب سے نیک نیتی پر مبنی پہلا قدم ہے‘‘۔
اُمید ہے کہ عالمی برادری جلد ہی ’اسلامی تعاون تنظیم‘ کے اس منصوبے کو ایک قابلِ عمل روڈمیپ کے طور پر تسلیم کرے گی۔لہٰذا، قاہرہ کو اپنی سفارتی کوششوں کو مزید مضبوط بنانا ہوگا اور ایک وسیع ورکنگ گروپ تشکیل دینا ہوگا، جس میں مصر، اُردن، امریکا، فلسطینی اتھارٹی، خلیجی ریاستیں، یورپی یونین اور دیگر عطیہ دہندگان شامل ہوں۔
فلسطینی قیادت کے اندر مجوزہ منصوبے پر اتفاق رائے کی شدید ضرورت کے پیش نظر، ایک مشترکہ امریکی-عرب کوشش بھی ضروری ہے، تاکہ فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات کا آغاز ہو سکے اور حماس کے ساتھ جنگ بندی کے بعد ایک دیرپا معاہدہ طے پاسکے، اور امن سفارتکاری کو کامیاب ہونے کا موقع دیا جا سکے۔(ترجمہ: ادارہ)
عمر کیسی ہی دراز ہوجائے، چار دن کی چاندنی ہوتی ہے۔ دو دن آرزو اور دو انتظار میں کٹ جاتے ہیں، پھر انسان خود کو رخت ِسفر باندھ لینے پر مجبور پاتا ہے۔ صبح شام ہونے اور عمر تمام ہونے کی یہ کہانی انسانوں کے انبوہ عظیم کی داستانِ حیات ہے۔ جو چند مستثنیٰ ہوتے ہیں، وہ وقت اور صلاحیتوں کی قدر کرکے کسی مخصوص میدان میں انسانیت کے قافلے کو ذرا آگے لے جاتے ہیں۔ ان کا یہ اختصاص انسانیت کی عظیم خدمت شمار ہوتا ہے اور تاریخ انھیں محسنوں کی حیثیت سے یاد رکھتی ہے۔ البتہ خال خال کچھ ایسے دیدہ ور بھی پیدا ہوتے ہیں، جو کسی ایک صلاحیت کی فصل لگاکر عمر بھر اسی کھیتی کو جوتنے کے بجائے اپنی شخصیت میں صلاحیتوں کا ایک باغ لگاتے ہیں۔ وہ فطرت کے عطا کردہ بالقویٰ جواہر کی ہمہ جہت پرداخت پر کچھ ایسی توجہ صرف کرتے ہیں کہ ہر جوہر اپنی جگہ آفتاب بن جاتا ہے۔ ابن سینا کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ منٹ، سیکنڈ اور ماہ و سال کے اعتبار سے ان کی ۵۷ سالہ زندگی اور عام زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن زندگی کے ہر لمحے کی انھوں نے کچھ ایسی قدر کی کہ آج بھی ان کی فکری فتوحات کا پورا مال غنیمت اکٹھا نہیں کیا جاسکا ہے۔ ایک سنجیدہ، ذہین، اور محنتی طالب علم کے لیے وہ بجا طور پر ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔
ابن سینا افشنہ (مضافات بخارا)میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد حکومت کی جانب سے ملکی اُمور کی انجام دہی پر مامور تھے۔ ابتدائی تعلیم وطن ہی میں حاصل کی۔ ذہنی استعداد خداداد تھی، اس پر علمی تجسس، فکری ذوق ، اور تحقیقی مزاج سونے پر سہاگہ تھا۔ زبان و ادب اور علومِ دینیہ کی تحصیل کے ساتھ ساتھ دس برس کی عمر میں قرآن کے حفظ سے فارغ ہوئے۔پھر فقہ، فلسفہ و ریاضی کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے شوق اور لگن کا یہ عالم تھا کہ ۱۶ برس کی عمر تک رائج علوم و فنون پر عبور حاصل کرلیا۔ واضح رہے کہ ابن سینا کے لیے ان کے والد نے وقت کے بہترین اساتذہ کے ذریعے گھر پر ہی تعلیم کا انتظام کیا تھا۔لیکن بیٹے کی ذہانت و ذکاوت اور استعداد علمی کی وجہ سے کسی لائق استاد کی تلاش خود ان کے والد کے لیے ایک خوش گوار پریشانی بن گئی تھی۔حصولِ علم کے جنون میں ابن سینا نے ایک سبزی فروش سے ہندستانی ریاضی اور ایک عیسائی مسافر سے طب یونانی کے ابتدائی درس لیے۔
طبرستان کے ابو عبداللہ ناتلی جب بخارا آئے تو ابن سینا کے والد نے انھیں اپنے یہاں جگہ دی۔ ایک بڑے عالم کی قدردانی کے علاوہ ابن سینا کو استفادے کا موقع بہم پہنچانا بھی مقصود تھا۔ ان سے ابن سینا نے منطق کے بنیادی مسائل سیکھے، اور ذاتی مطالعے سے دقیق مسائل تک رسائی حاصل کی۔ پھر تو حالت یہ ہوگئی کہ بطلیموس اور اقلیدس کی کتابوں کے ان مسائل کو بھی خود حل کرنے لگے، جن کے استاذ محترم بھی متحمل نہ تھے۔ ابن سینا کے علمی شوق، سرعت مطالعہ، دورانِ درس سوالات و اعتراضات اور بحث و مباحثے سے استاذ کو شاگرد کے علمی مقام کا اندازہ ہوگیا۔ انھوں نے ابن سینا کے والد سے کہا کہ اس لڑکے کو علم کے علاوہ کسی اور کام میں مصروف نہ کریں۔
کثرتِ مطالعہ کا ایک فتنہ یہ ہے کہ انسان بے سمجھے بوجھے حروف پر نظر کی اسکیننگ سے مطمئن ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ابن سینا معلومات، دقیق نکات، اور فلسفیانہ دلائل کو اپنے فہم کا حصہ بنانے کے حریص تھے۔ چنانچہ ارسطو کی مابعد الطبیعۃ کے مطالب ان پر نہ کھلے تو انھوں نے اس کتاب کا چالیس چالیس مرتبہ مطالعہ کرڈالا۔ اور پھر جب فارابی کی شرح سے ارسطو کی گرہیں کھلیں تو سجدۂ شکر بجا لائے اور فرحت و انبساط کے عالم میں فقراء و مساکین کو دل کھول کر صدقہ دیا۔
ابن سینا جب طب کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک آدھ برس ہی میں یعنی عمر کی اٹھارھویں منزل پر پہنچتے پہنچتے یہ استعداد حاصل کرلی کہ باقاعدہ علاج معالجہ کرنے لگے۔سیکھنے کا ایسا جنون تھا کہ اپنے مطب میں مریضوں کا مفت علاج کرتے، مرض کی علامات کو باقاعدہ نوٹ کرتے اور وجوہ پر غور کرتے۔ اس طرح اپنے قاموسی دماغ میں کتابی معلومات کے ساتھ ساتھ ذاتی تجربے کی حکمتوں کا خزانہ بھی جمع کیا۔ جلد ہی ان کی طبی مہارت و تحقیقات کی دھوم مچ گئی۔ انھیں سلطانِ بخارا کے علاج کے لیے شاہی دربار بلایا گیا۔ جہاں بڑے بڑے اطباء نے ہاتھ کھڑے کردیے تھے، وہاں اس نوعمر حکیم نے سلطان کو پیروں پر کھڑا کردیا۔ کوئی اور ہوتا تو اس کامیابی پر بادشاہ سے دنیا جہان کی دولت مانگ لیتا، لیکن ابن سینا نے شاہی کتب خانے سے استفادے کی اجازت مانگی۔ شاید نادر و نایاب کتب کی معیت ہی ابن سینا کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔
طب میں ابن سینا کو یہ درجہ اس وجہ سے بھی حاصل ہوا کہ انھوں نے اس علم کو مروجہ رجحانات سے آگے لے جانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ مثلاً انھوں نے یونانی مسلمات سے ہٹ کر یہ تصور پیش کیا کہ مختلف بیماریوں کے لیے جراثیم ذمہ دار ہوتے ہیں۔ انھی بنیادوں پر لوئی پاسچر نے انیسویں صدی میں Immunologyکی پوری عمارت تعمیر کی۔ ابن سینا کی القانون اور دیگر طبی کتابوں کے مطالعے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ وہ طب میں دواؤں کے ذریعے علاج کے یک رُخے تصور کے بجائے صحت کے سلسلے میں ایک جامع نقطۂ نظر کے حامل ہیں، جس میں پرہیز، غذا ، پانی، نیند، آب و ہوا، نفسیات، طرز زندگی،جسمانی سرگرمی وغیرہ عوامل کےاپنے خصوصی مقام کو تسلیم کیا گیاہے۔ ان کے تجویز کردہ نسخوں میں بھی مریض کی عمر، وزن اور کھانے پینے کے معمولات کے اعتبار سے اختلاف نظر آتا ہے۔ انھوں نے علم طب میں سائنٹی فک تجربے کی بنیاد ڈالی، اور ان شرائط کا تفصیل سے ذکر کیا، جن کے پورے ہونے پر دوا کا اثر معلوم کیا جاسکے۔ جدید آلات اور ٹکنالوجی کی عدم موجودگی میں بھی انسانی اعضاء بالخصوص آنکھ جیسے نازک عضو کی معیاری تشریح بھی ان کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ ذیابیطس، موتیابند، ذات الصدر، اور گردن توڑ بخار وغیرہ پر ابن سینا کے تحقیقی مشاہدات سے بظاہر یکساں علامات کے حامل مختلف امراض کے درمیان خطِ امتیاز واضح ہوا۔ ابن سینا نے بتایا کہ ٹی بی متعدی بیماری ہے، نیز طاعون کی وبا میں چوہوں کے مسموم کردار کی پیش گوئی کی جو بعد میں صحیح ثابت ہوئی۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران ہر کوئی قرنطینہ (Quarantine)سے واقف ہوگیا ہے، لیکن اس حقیقت سے بہت سے لوگ لاعلم رہے کہ ٹھوس طبی بنیادوں پر سب سے پہلے ابن سینا ہی نے متعدی امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ۴۰دنوں کے قرنطینہ کا تصور دیا تھا۔
فلسفے کے میدان میں ابن سینا کے اثرات دیر پا ہیں۔وہ محض یونانی فلسفے کے شارح نہیں تھے، ان کا خیال تھا کہ قدما کی کتابوں کی شروحات سے آگے بڑھ کر اپنا فلسفہ مدون کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تناظر میں ابن سینا کو بجا طور پر یونانی فلسفہ اور مشرقی حکمت کا جامع کہا جاتا ہے۔ ایک نامور فلسفی ہونے کے باوجود ابن سینا نے انسان کی قوتِ خیال کو ناقص قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوتِ فکر و خیال آزاد نہیں ہے،منطق کی محتاج ہے۔ جس طرح کوئی قیافہ شناس کسی فرد کے ظاہر سے اس کے باطن پر گمان قائم کرتا ہے، اسی طرح منطق داں معلوم مقدمات سے نامعلوم نتائج کا استنباط کرتے ہیں۔ ابن سینا کے مطابق اس عمل میں غلطیوں اور تعصبات کی آمیزش کا احتمال قوی ہوتا ہے، لہٰذا منطق سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، وحی الٰہی سے ہوتا ہے۔ وحی الٰہی کے سایۂ عاطفت میں انسان منطق سے اس طور پر غنی (بے نیاز) ہوجاتا ہے جیسا کہ کوئی عرب بدو علمِ صرف و نحو سے۔
ابن سینا کا اختراعی ذہن اپنے زمانے سے بہت آگے تھا۔ ان کا مبلغ علم کتب بینی سے آگے بڑھ کر تجربات تک وسیع تھا۔ انھوں نے فکری وعملی ہر دو طرح کے تجربے کیے۔ مثلاً ’الرجل المعلق‘ (The Floating Man)کے فکری تجربے (Thought Experiment) کے ذریعے انھوں نے شعور اور روح کے غیر مادی وجود کو ثابت کیا ہے۔ تقریباً چھ سو برسوں کے بعد ڈیکارٹ کا یہ کہنا کہ I think therefore I am،ابن سینا کے اسی فکری تجربے کو خراج عقیدت محسوس ہوتا ہے۔
اسی طرح ایک مثال اس عملی تجربے کی ہے، جس میں ابن سینا نے دو بھیڑ کے بچوں کو لیا جن میں عمر، نسل، جسامت، اور وزن کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا۔ ان دونوں بھیڑوں کو الگ الگ پنجروں میں رکھا گیا۔ ایک تیسرے پنجرے میں ایک بھیڑیے کو بھی بند کیا گیا اور اسے ذرا دور کچھ اس زاویے سے رکھا گیا کہ ایک بھیڑ کے بچے کو بھیڑیا نظر آتا مگردوسرے کو دکھائی نہیں دیتا۔دونوں بھیڑ کے بچے اس ایک معمولی فرق کے علاوہ بالکل یکساں ماحول میں تھے، انھیں غذا بھی ایک سی دی جارہی تھی۔ابن سینا نے یہ نوٹ کیا کہ جس بھیڑ کے بچے کی نظر سے بھیڑیا دور تھا وہ صحت مند رہا، لیکن جس بھیڑ کے بچے کو بھیڑیا دکھائی دیتا تھا، اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوکھلاہٹ، سراسیمگی، اور دیوانگی کے آثار پائے جانے لگے۔ اس کی نشوونما متاثر ہونے لگی، وزن بھی گھٹنے لگا، حتیٰ کہ ایک دن وہ مرگیا۔ بھیڑیے کی دسترس سے بظاہر محفوظ رہنے کے باوجود بھیڑ کے بچے کا جو حال ہوااس سے ابن سینا نے خوف، دہشت، گھبراہٹ، اور منفی سوچ جیسے غیر مادی عوامل کے صحت پر اثرات کو ثابت کیا ہے۔
قصہ المختصر یہ کہ ابن سینا کے تجسس و جستجو اور پیہم سرگردانی میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ان کی طبی و فلسفیانہ کتابیں ہی نہیں بلکہ مذہبی مضامین، صوفیانہ رسائل، متفرق اشعار و مضامین بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی انشاپردازی بھی غضب کی تھی۔ منطق و فلسفہ اور طب کی کتابوں کی خوب صورت اور بلیغ نثر میں اہل ذوق کو شاعری کا مزہ ملتا ہے۔
مشہور ہے کہ تنوع، گہرائی اور وسعت کے اعتبار سے سمندر بے مثال ہوتے ہیں، لیکن ابن سینا کی علمی کاوشوں کے تنوع، فکر و فلسفے کی گہرائی، اور اختصاصی میدانوں کی وسعت بحر الکاہل اور بحراوقیانوس کو شرماتی ہے۔ ڈی بورو نے لکھا ہے: ’’ابن سینا میں بیک وقت اتنے اوصاف و کمالات یکجا ہوگئے تھے کہ اہل یورپ انھیں ’جادوگر‘ کہا کرتے تھے‘‘۔ ایک عام انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ ابن سینا، ربِّ ذوالجلال سے کتنی زندگیاں مانگ لائے تھے۔ لیکن ایک عقل مند جانتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کا اصل راز ماہ و سال کی کثرت تعداد پر نہیں بلکہ ہر گزرتے لمحے کی استعداد سے بھرپور استفادے پر ہے۔
خود ابن سینا کا قول ہے کہ میں مختصر مگر کشادہ زندگی کو لمبی مگر تنگ زندگی پر ترجیح دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لغویات و کسل مندی کے پھندوں اور تنگ و محدود زندگی کی لعنت سے حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی مہلت عمل کے احسن اور بہترین استعمال کی توفیق دے، آمین!
ایک امریکی خاتون مؤرخ پروفیسر آڈری ٹروشکی (Audrey Truschke) کی مغل فرمانروا اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ایک ایسی کتاب جس نے ہندوتوادیوں میں ہلچل مچا دی، تو وہ سب آڈری ٹروشکی کے خلاف یکجا ہوگئے۔ ساورکر کے پرستار اور ’ہندوتوا‘ کے علَم بردار مؤرخ وکرم سمپت اس میں پیش پیش تھے ۔ اب،جب کہ پھر اورنگزیب کے نام پر [انڈیا میں]سیاست کھیلی جا رہی ہے اور ان مباحث کو تازہ کیے رہتے ہیں۔ مغل فرمانروا اورنگزیب نہ ولی تھے اور نہ صوفی ۔اسی طرح اورنگزیب متعصب یا کٹّر مسلمان بھی نہیں تھے ۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ زیادہ تر مؤرخین نے اورنگزیب کی ذات، صفات اور خدمات کا مطالعہ انھی دو متضاد انتہاؤں سے کیا ہے۔ یا اگر کچھ ہٹ کر کرنا چاہا تو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان سے یہ جگہ نکالی کہ اورنگزیب کو نہ قطعی متعصب قرار دیا اور نہ ان کے صوفی ہونے سےکُلّی طور پر انکار کیا ۔ یہ ایک طرح سے اورنگزیب کا دفاع کرنے کی سعی ہے ۔ مگر کیا ان بنیادوں پر اورنگزیب کا درست اور صحیح مطالعہ ممکن ہے؟
آڈری ٹروشکی نے اپنی کتاب Aurangzeb: The Man the and The Myth (’’اورنگزیب : ایک شخص اور فرضی قصے‘‘، اُردو ترجمہ: اقبال حسین، فہد ہاشمی) میں اورنگزیب کا مطالعہ جدید پیمانے پر پیش کیا ہے ۔مصنّفہ کے مطابق: ’’ماضی کے تئیں ایمان دار رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ بحیثیت ایک شہزادہ اور بحیثیت ایک بادشاہ، ان کی مکمل تصویر پیش کریں‘‘۔ ایک جگہ وہ لکھتی ہیں کہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ اورنگزیب کی زندگی اور دورِ حکومت کا ایک تاریخی خاکہ تیار کیا جائے، اور اس طرح غلط بیانیوں کے انبار تلے دبے اورنگزیب کو بحیثیت ایک بادشاہ اور ایک انسان، بازیابی کو ممکن بنایا جا سکے جن کے بارے میں صدیوں سے ہم نے افواہوں کو من و عن قبول کرنے میں سادگی اور جہالت سے کام لیا ہے‘‘۔
وہ کون سی غلط بیانیاں ہیں جن کے انبار تلے اورنگزیب دبے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب مشکل نہیں ہے ۔ آڈری نے آٹھ ابواب میں ، جو محض ۱۲۸ صفحات پر مشتمل ہیں، اورنگزیب کی ایک انسان، شہزادے اور شہنشاہ کی حیثیت سے وہ تصویر پیش کی ہے، جو ان کی خوبیوں اور خامیوں کو پوری طرح عیاں کردیتی ہے۔ جن کے تعلق سے فرضی قصوں کا ایک ایسا جال بنا گیا ہے کہ لوگ اس میں پھنستے ہی چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بقول آڈری: ’’ اکیسویں صدی کے جنوبی ایشیا میں اورنگزیب کی شبیہ غلط بیانی اور تردید کے بھنور میں پھنس کر رہ گئی ہے، اور اورنگزیب کی ذات ایک پہیلی بن گئی ہے ‘‘۔
اورنگزیب نے ۴۹ سال تک ۱۵ کروڑ انسانوں پر حکومت کی۔ ان کے دور میں مغلیہ سلطنت کی آبادی پورے یورپ سے زیادہ تھی اور وہ خود اپنے وقت کے امیرترین انسان تھے۔ جب ۱۷۰۷ء میں انھوں نے دنیا سے کوچ کیا تب مغل ہندستان جغرافیائی اور معاشی بنیاد پر دنیا کی سب سے بڑی حکومت بن چکا تھا، مگر اورنگزیب دنیا سے جاتے ہوئے خوش نہیں تھے، انھیں یہ لگ رہا تھا کہ ان کی زندگی ناکام رہی ہے ۔ بستر مرگ سے تحریر کیے گئے اپنے ایک خط میں انھوں نے لکھا ہے: ’’میں ایک اجنبی کی حیثیت سے آیا ہوں، اور ایک اجنبی ہی کی طرح چلا جاؤں گا۔‘‘انھیں یہ احساس تھا کہ ایک بادشاہ کے طور پر وہ اپنی ذمہ داریوں کی پوری طرح ادائیگی نہیں کرسکے۔
ایک خط میں اورنگزیب نے یہ اعتراف کیا ہے:’’ حکمرانی کی ذمہ داریوں اور عوام کی اعلیٰ درجے میں خدمت اور ان کے تحفظ کے مَیں لائق نہیں تھا‘‘۔ دنیا اورنگزیب کو سخت مذہبی فرد سمجھتی ہے، بلکہ اسی چیز کو ان کا سب سے بڑا ’جرم‘ قرار دیتی ہے، لیکن انھوں نے ایک خط میں اپنی دینی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے: ’’میں جلد ہی خدا کی عدالت میں ایک گناہ گار کے طور پر سامنا کروں گا‘‘۔ اپنے آخری خط میں دنیا سے کوچ کا اظہار جذباتی انداز میں کرتے ہوئے تین بار ’’خداحافظ، خدا حافظ، خدا حافظ‘‘ لکھا ہے ۔ مذکورہ خطوط سے اورنگزیب کی تصویر، اُس تصویر سے بالکل الگ صورت میں اُبھرتی ہے کہ جو تصویر ہمیں دکھائی جاتی ہے۔
اورنگزیب کو یہ احساسِ محرومی زندگی بھر دامن گیر رہا کہ وہ عوام کی حفاظت نہیں کر سکے، اور حکمرانی کے فرائض ادا نہیں ہو سکے۔ یہ کہ وہ ساری زندگی خدا کو ایسے بھولے رہے کہ مذہبی تعلیمات پر عمل نہیں کرسکے۔ لیکن آج اُن کے سارے ’کرم فرما‘ انھیں کٹّر مذہبی، ظالم بادشاہ، متعصب اور جبراً ہندوؤں کا مذہب تبدیل کرنے والے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں ۔ آڈری ٹروشکی نے اپنی اس کتاب کے ذریعے ان کی درست تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔
یہ کتاب ہمیں بہت سی ایسی باتیں بھی بتاتی ہے، جو انڈیا کی ’ہندوتوا سیاست‘ اور بھگوا تاریخ اور صحافت ہم سے چھپاتی ہے ۔ مثلاً یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے ’ہولی‘ پر روک لگائی تھی، مگر یہ امرواقعہ چھپایا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے ’عیدالفطر‘ اور ’بقرعید‘ پر بھی اسی طرح روک لگائی تھی ۔ آڈری ٹروشکی لکھتی ہیں ’’اورنگزیب نے ’نوروز‘ پر بھاری بھرکم تقریبات کے انعقاد کو محدود کیا، اور مسلمانوں کے بڑے تہواروں عیدالفطر اور عیدالاضحی کے موقعوں پر بڑے پیمانے پر جشن منا نے کے رسم و رواج کو بھی منسوخ کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح انھوں نے ہندوؤں کے تہواروں ’ہولی‘ اور ’دیوالی‘ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے محرم کے یادگاری جلوس سے متعلق ہنگامہ خیزی پر بھی لگام کسنے کی کوشش کی تھی ۔‘‘یہ احکامات ایک تو اس لیے تھے کہ انھیں رنگ رلیاں کرنے والوں کے بے ہنگم جوش و خروش سے کسی قدر بیزاری تھی، اور دوسرا مقصد عوام کی حفاظت تھی کہ ایسے مواقع پر اکثر پُرتشدد ہنگامے ہو جاتے تھے ۔
آڈری یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہندوئوں اور مسلمانوں کے ان مذہبی تہواروں پر فضول خرچی اور لہوولعب پر گرفت کرنے کے لیے احکامات تو دیے گئے، مگر ان پر کبھی پوری طرح عمل نہیں ہوا، یہاں تک کہ درباری اور شاہی خاندان کے افراد بھی تہوار مناتے رہے ۔ پروپیگنڈا مواد یہ تو بتاتا ہے کہ اورنگزیب نے بہت سارے لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا تھا، مگر یہ نہیں بتاتا کہ کچھ لوگوں نے مغلیہ سلسلۂ مراتب میں ترقی کے لیے بھی اسلام قبول کیا تھا اور کچھ لوگوں نے دوسرے محرکات اور ترقی کے حصول کے لیے بھی اسلام قبول کیا تھا ۔
آڈری کے مطابق: تبدیلیٔ مذہب کرنے والے لوگ اورنگزیب کی تنقیدی نظر میں آجاتے تھے، اپنے ایک خط میں ایسے ہی دو لوگوں کی، جنھوں نے اپنے قبولِ اسلام کی فخریہ تشہیر کی تھی، اورنگزیب نے مذمت کی تھی اور انھیں قید کرنے کا حکم دیا تھا ۔ آڈری نے لکھا ہے: ’’ مجموعی طور پر اورنگزیب کے ہندستان میں نسبتاً ہندوؤں کی قلیل تعداد نے اسلام قبول کیا تھا‘‘۔ اسی طرح لکھا ہے کہ یہ بات بھی سامنے نہیں لائی جاتی کہ اورنگزیب اپنی مسلمان رعایا کے تئیں اقدامی کارروائی میں پہل کیا کرتے تھے ۔ انھوں نے شیخ احمد سرہندی نقشبندیؒ (مجدد الف ثانی)کی کچھ تحریروں پر بھی پابندی عائد کر دی تھی، مہدویہ فرقے کے چند درجن افراد قتل کردیئے تھے، اپنی شہزادگی میں شیعہ اور اسماعیلی بوہرہ فرقے پر نگرانی سخت کردی تھی۔ اسماعیلی بوہرہ فرقہ کے لیے یہ حکم دیا کہ وہ اپنی مساجد میں سنّی طریقے سے نماز پڑھیں ۔ لیکن پھر یہی اورنگزیب دوسری طرف ہندو مذہبی برادری کے لیے نرم رو تھے ۔
آڈری ٹروشکی بتاتی ہیں: ’’اورنگزیب کا یہ ماننا تھا کہ اسلامی تعلیمات اور مغلیہ روایات نے انھیں ہندو مندروں، زیارت گاہوں، اور مقدس شخصیتوں کی حفاظت کے لیے پابند کیا تھا‘‘۔ ان پر ہندو مندروں کی مسماری کا الزام لگتا ہے، لیکن مصنّفہ لکھتی ہیں: ’’ اورنگزیب کی سلطنت میں زمین کا پورا خطہ ہندو اور جین مندروں سے مزین تھا ۔ یہ مذہبی ادارے مغل حکومت کی محافظت میں تھے، اورنگزیب عموماً ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہتے تھے ۔ علیٰ ہذا القیاس، جب کبھی کوئی خاص مندر یا اس سے منسلک لوگ شاہی سلطنت کے مفاد کے خلاف کسی عمل میں شامل ہوتے، تب مغل نقطۂ نظر کے تحت ایسے خیر سگالی عمل کو منسوخ بھی کر دیا جاتا تھا ۔اسی اسکیم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اورنگزیب نے کچھ مخصوص مندروں کے انہدام کا حکم صادر کیا تھا‘‘ ۔
اس ضمن میں بنارس کے وشوناتھ مندر اور متھرا کے کیشو دیوا مندر کے انہدام کا الزام اورنگزیب پر لگتا ہے، مگر یہ بات سامنے نہیں لائی جاتی کہ یہ مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ سیاسی اقدامی فیصلے تھے، اور مقصد کچھ لوگوں کو ان کی سیاسی غلطیوں کی سزا دینا تھا ۔ ورنہ اورنگزیب کے دور میں کثیر پیمانے پر مندر بنے، مندروں کو بڑی بڑی جاگیریں دی گئیں اور ان کی حفاظت کی گئی ۔ بنارس کے پنڈتوں کی حفاظت کا فرمان تک جاری کیا گیا ۔ شہنشاہ کے امراء میں ۵۰ فی صد ہندو تھے، جن میں مراٹھے سب سے زیادہ تھے ۔ مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ شیواجی، جو مراٹھا تھے، آخر دم تک ان کے لیے دردِسر بنے رہے۔
اس کتاب میں اورنگزیب اور شیواجی کی ملاقات کا دلچسپ احوال شامل ہے، نیز شیواجی کے تعلق سے دیگر اہم باتیں بھی درج ہیں ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب ’جزیہ‘ لیتے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ برہمن پروہتوں، راجپوت اور مراٹھا درباریوں، اور ہندو منصب داروں سے ’جزیہ‘ نہیں لیا جاتا تھا۔ جین، سکھ، اور دیگر غیر مسلم عوام پر جزیہ کی ادائیگی لازم تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انھیں کچھ مخصوص حقوقِ فراہم کیے گئے تھے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا تھا۔
آڈری بتاتی ہیں کہ علما کی ایک بڑی تعداد کو بادشاہ کی مذہبی سنجیدگی پر شبہ تھا۔ انھی علما کو، اور جو مذہب تبدیل کرکے مسلمان بنے تھے، انھیں ’جزیہ‘ کی وصولی میں لگایا گیا تھا۔ اس طرح علما کے حلقے میں اورنگزیب کی ساکھ کچھ بحال ہوئی تھی، مگر بہت سے مسلم امراء اور شاہی خاندان کے افراد، جن میں اورنگزیب کی بہن جہاں آراء بھی شامل تھیں، وہ ’جزیہ‘ وصولی کے ناقص انتظامی فیصلے کا مذاق اڑاتے تھے کہ ’جزیہ‘ وصولی کے بعد بڑا حصہ وصول کرنے والے ہڑپ کرلیتےتھے ، بادشاہ اس کو روکنے میں بے بس تھا ۔
اورنگزیب نے ہندو مذہبی کتابوں کے تراجم پر کوئی روک نہیں لگائی،بلکہ ’رامائن‘ کے فارسی تراجم تحفتاً قبول کیے ۔ اورنگزیب کے دربار میں اخبار بھی تھا، جی ہاں انھیں اپنی حکومت کے ہرکونے کی خبر پڑھ کر سنائی جاتی تھی ۔ اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے واقعات پر آج تک سخت ردعمل ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن بقول آڈری: مغلوں میں سیاسی طاقت کے حصول پر خاندان کے تمام مردوں کا دعویٰ ہوتا تھا ۔ اکبر بادشاہ نے قانونی حق داروں کو کم کر کے اسے صرف بیٹوں تک محدود کر دیا تھا، لہٰذا حکومت کے حصول کے لیے اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، وہی کارروائیاں ان کے بھائی بھی موقع پاتے تو اورنگزیب کے ساتھ کرتے ۔
اورنگزیب کے ہاتھوں والد شہنشاہ شاہجہاں کی بے دخلی اور قید کرنا ایک سخت افسوس ناک عمل سمجھا جاتا تھا اور مغل سلطنت کے قاضی القضاۃ (چیف جسٹس)نے اس پر برہمی کا اظہار کیا تھا، جس پہ انھیں ہٹا دیا گیا تھا ۔ اسی طرح بیرون ملک بھی ان کا یہ عمل ناپسندیدہ قرار پایا تھا۔ ’شریف مکہ‘ نے تو اورنگزیب کو ہندستان کا جائز بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا تھا ۔ صفوی حکمران شاہ سلیمان نے تو اس کی مذمت کی تھی ۔ دراصل اپنے والد سے برتاؤ کے معاملے میں اورنگزیب کو کبھی چھٹکارا نہیں ملا۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے موسیقی پر پابندی لگا دی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انھوں نے کچھ مخصوص قسم کی موسیقی پر، وہ بھی صرف اپنے ایوان ہی میںپابندی لگائی تھی ۔ اورنگزیب کے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کی والدہ اودیپوری ایک مغنیہ تھیں، جو علالت کے دنوں میں اورنگ زیب کے ساتھ رہیں۔
ایک دلچسپ بات آڈری نے یہ لکھی ہے: اورنگزیب نے کئی بار ریاستی مفاد میں اسلامی اصولوں پر سمجھوتہ کیا۔ اسی لیے علمائے دین کی ایک قابلِ ذکر تعداد اور خاص طور پر قاضی القضاۃ سے پورے عہد حکومت میں نہیں نبھی۔ حالانکہ دوسری طرف حقیقت یہ بھی ہے کہ انھوں نے فتاویٰ عالمگیری کو ترتیب دینے کے لیے بہت سے قابل علمائے کرام کو خصوصی وظائف بھی دیئے۔
اورنگزیب کی یہ تصویر، جو آڈری ٹروشکی نے دکھائی ہے، یہ کسی متشدد شہنشاہ کی نہیں ہے، لیکن قوم پرست ہندو نظریے کی رُو سے ظہیرالدین بابر اور اورنگزیب عالم گیر ظالم بادشاہ ہیں۔ سیکولر ذہن کے حامل دانش وروں اور مؤرخوں کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی نسل پرست ہندوئوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اورنگزیب کو متشدد مسلمان ہی قرار دیتی ہے ۔
انڈیا کے پہلے وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں اورنگزیب کو ایک متعصب اور متشدد حد تک کٹّر مذہبی کہا اور مذمت کی ہے ۔ مؤرخ جادو ناتھ سرکار نے بھی متعصب قرار دیا ہے ۔پاکستانی ’ترقی پسند‘ ڈرامہ نگار شاہد ندیم نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ ’’اورنگزیب نے اپنے بھائی داراشکوہ پر فتح حاصل کرکے تقسیم کے بیج بودیے تھے‘‘۔ آڈری لکھتی ہیں کہ اورنگزیب بحیثیت ایک ’شر‘ اور ’متعصب‘ ہونے کے فرضی قصوں کو بہت ہی کم تاریخی شہادتوں کی موجودگی کے بغیر پھیلایا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بی جے پی اور دیگر قوم پرست جماعتوں سے سیاسی و نظریاتی طور پر متفق نہ ہونے والے افراد بھی اورنگزیب کو ’شر‘ قرار دیتے اور ’متعصب‘ کہتے ہیں۔ افسوس کہ اپنی وصیت کے مطابق خلد آباد میں کھلے آسمان تلے ایک معمولی سی قبر میں دفنائے گئے۔ اورنگزیب تاریخ کا ایک ایسا زندہ تار بن گئے ہیں، جس میں مسلسل برقی رو دوڑتی رہتی ہے۔ انڈیا کی حالیہ سیاست ان کے نام کو مکمل مٹانے کے درپے ہے۔ اسی لیے دہلی میں ان کے نام کی سڑک کو دوسرا نام دے دیا گیا ہے ۔ لیکن بقول آڈری اس طرح کی باتوں سے اورنگزیب کا نام مٹنے کے بجائے لوگوں کے ذہن پر مزید گہرا نقش ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو اورنگزیب کی اولاد کہا جانے لگا ہے۔
آڈری کے بقول: غالباً اورنگزیب اس بات سے مطمئن ہوتے کہ انھیں فراموش کر دیا گیا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ انھیں بھولنے کو تیار نہیں ہیں ۔ قصوروار بی جے پی اور سنگھ پریوار ہے، جو بار بار ان کا نام لیتی رہتی ہے ۔ کتاب شاندار ہے،اور موضوع کی دلچسپی کے سبب اس کا مطالعہ مفید ہے۔
ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ دیکھیں تو اخلاق کی پستی کے ساتھ ہم سرے سے کسی اسلامی زندگی کا تصوّر ہی نہیں کرسکتے۔ مسلمان تو مسلمان بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی ذات سے دُنیا میں بھلائی قائم ہو اور بُرائی مٹے۔ بھلائی کو مٹانا اور بُرائی پھیلانا ، اور پھر اس کے ساتھ مسلمان بھی ہونا، یہ درحقیقت ایک کھلا ہوا تناقض ہے۔ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اُس کے شر سے دوسرے بندگانِ خدا محفوظ نہ ہوں۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اُس پر کسی معاملے میں اعتماد نہ کیا جاسکے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی وہ نیکی سے بھاگے اور بدی کی طرف لپکے، حرام کھائے اور حرام طریقوں سے اپنی خواہشات پوری کرے، تو آخر اس کے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کسی مسلم معاشرے کی اس سے بڑھ کر کوئی ذلّت نہیں ہوسکتی کہ وہ انصاف سے خالی اور ظلم سے لبریز ہوتا چلا جائے۔ اس میں روز بروز بھلائیاں دبتی اور بُرائیاں فروغ پاتی چلی جائیں، اور اس کے اندر دیانت و امانت اور شرافت کے لیے پھلنے پھولنے کے مواقع کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں۔ یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی حالت ہے۔ اگر کسی مسلم معاشرے کی یہ حالت ہوجائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اسلام کی روح سے خالی ہوچکا ہے، صرف اسلام کا نام ہی اس میں باقی رہ گیا ہے، اور یہ نام بھی اب صرف اس لیے رہ گیا ہے کہ دُنیا کو اس دینِ حق سے دُور بھگاتا رہے۔
مسلمان اخلاقی زوال کی طرف جاتا ہی اس وقت ہے جب اسے خدا کی رضا اور آخرت کی فلاح مطلوب نہیں رہتی اور صرف دُنیا اس کی مطلوب بن کر ہ جاتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کی پستی کے ساتھ کوئی قوم دُنیا کی کامیابی بھی حاصل نہیں کرسکتی۔ اس پستی کے ساتھ تو آخرت بھی ہاتھ سے جاتی ہے اور دُنیا بھی ہاتھ نہیں آتی۔(’تعمیر اخلاق کیوں اور کیسے ؟‘، سیّدابوالاعلیٰ مودودی، ترجمان القرآن، اپریل ۱۹۶۵ء، ص ۲۸)