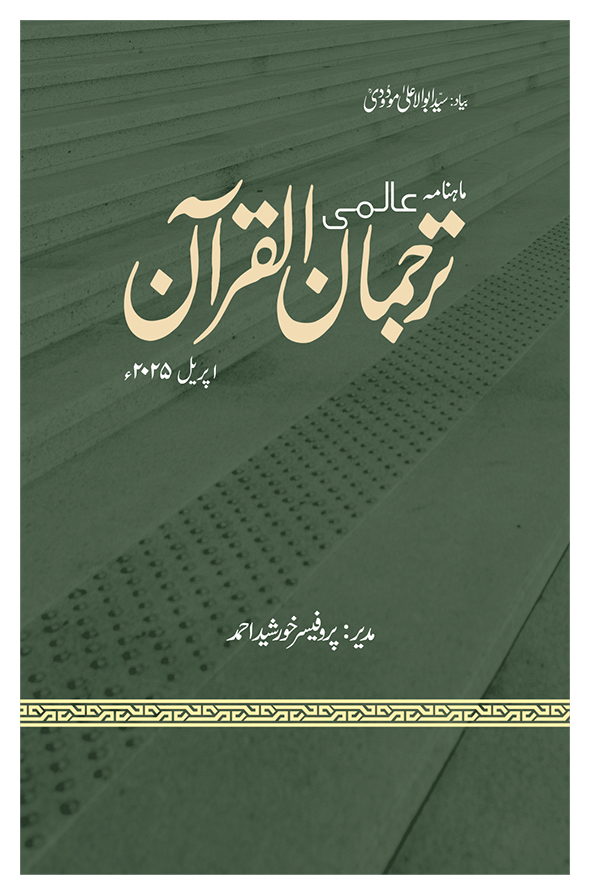
پاکستان پانی کی فراوانی و دستیابی والے ملک کے مقام سے گر کر اب پانی کی قلت والا ملک بننے کے قریب ہے اور بعض تخمینوں کے مطابق بن چکا ہے۔ دیگر ماہرین کے مطابق اگر اس سلسلے کو روکنے کے لیے فوری اقدامات نہ اٹھائے گئے تو ۲۰۳۵ء تک یقینی طور پر پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہوگا۔ اس صورت حال تک پہنچنے میں جہاں موسمیاتی تبدیلیوں اور آبادی میں اضافے کا حصہ ہے، وہاں اس میں ایک بہت بڑا حصہ پانی کے غیرمحتاط استعمال، اس کی ترسیل کے ناقص انتظام اور اسے ذخیرہ کرنے میں کوتاہی کا بھی ہے۔ یہی وہ پہلو ہیں جن پر اس تحریر میں ہماری توجہ مرکوز ہے۔ اس مقصد کے لیے ماضی میں تیار کی گئی متعدد رپورٹوں سے مدد لی گئی ہے، جن میں سے اکثر کی تیاری کے لیے حکومتِ پاکستان کا کوئی نہ کوئی محکمہ شامل رہا ہے۔
ہمارے تجزیے کے مطابق قابلِ عمل منصوبہ بندی اور ترجیحات کے درست تعیّن کے ذریعے صورت حال کو اب بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ملک کے تمام صوبوں کی مشاورت اور شمولیت سے اور ان کے تحفظات کو دُور کرتے ہوئے ایسا کرنا بالکل ممکن ہے۔ ہمارے پاس ایسی دستاویزات، معاہدے، ایکٹ اور پالیسیاں موجود ہیں، جن کی بنیاد پر تعمیری پیش قدمی ممکن ہے۔ اسی طرح ہمیں ایسے فورم بھی میسر ہیں جہاں گفتگو اور تبادلۂ خیال کے ذریعے مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جا سکتا ہے۔
تاریخی طور پر وہ تہذیبیں اور شہر جو پانی کی عدم دستیابی سے اُجڑ گئے، ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ پانی کی قلت سے جو خشک سالی پیدا ہوئی تو اس نے ان علاقوں میں زراعت کو شدید نقصان پہنچایا۔ زراعت ہی ان علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی زندگی اور غذائی ضروریات کے حصول کا اہم ترین ذریعہ تھی۔ اس میں خلل پڑا تو یہ بستیاں اُجڑ گئیں۔
پاکستان بننے کے بعد بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں شدید خشک سالی اور قحط جیسی صورت حال پیدا ہوتی رہی ہے، جس کی کثرت موجودہ صدی میں بڑھ گئی ہے۔ مثلاً، پاکستان کی تاریخ کی شدید ترین خشک سالی صوبہ بلوچستان میں ۲۰۰۰ء اور ۲۰۰۲ء کے دوران ہوئی اور یہی صورت حال ۲۰۱۳ء-۲۰۱۴ء میں صوبہ سندھ کے علاقے تھرپارکر میں رہی، جب کہ ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء اور ۲۰۲۰ء میں سندھ اور بلوچستان کے کئی اضلاع خشک سالی کا شکار ہوئے۔ اس دوران، پاکستان کے موسمیاتی ادارے کے مطابق ان علاقوں میں ۲۰ سے ۳۰ فی صد بارش کی کمی رہی، جو ان علاقوں کے لیے پانی کی فراہمی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔
دوسری جانب ہم حالیہ برسوں میں سیلابوں سے ہونے والی تباہی دیکھ چکے ہیں۔ جن میں ۲۰۲۲ء کے سیلاب میں سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے صوبوں میں دو ہزار کے قریب اموات ہوئیں۔ مویشیوں، فصلوں اور رہائشی علاقوں کے علاوہ انفرا اسٹرکچر کی تباہی کا تخمینہ ۴۰ بلین ڈالر کے لگ بھگ لگایا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ۱۹۵۰ء، ۱۹۷۳ء،۱۹۹۲ء اور موجودہ صدی میں ۲۰۰۳ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء میں بھی سیلاب نے ملک میں تباہی مچائی۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ حالیہ برسوں میں سیلابوں کی کثرت میں اضافہ ہوا ہے، جس کا زیادہ تعلق موسمیاتی تبدیلیوں سے ہے، جو ایک قابلِ تشویش اور توجہ طلب صورت حال ہے۔
پانی کی تقسیم کے اعتبار سے بین الااقوامی اور بین الصوبائی معاہدوں کی تاریخ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ بہت اہم سندھ طاس معاہدہ مغربی اور مشرقی دریاؤں کی تقسیم کے سلسلے میں ۱۹۶۰ء میں ہوا، جو اب تک برقرار ہے۔ تاہم، انڈیا نے اس معاہدے پر نظرثانی کے لیے حال ہی میں دو نوٹس پاکستان کو بھیجے ہیں، جب کہ جموں و کشمیر میں پاکستان کے لیے مختص پانی پر روک لگانے کے انڈین منصوبوں کے خلاف پاکستان نےعالمی عدالت میں مقدمات دائر کر رکھے ہیں، جنھیں عدالت نے شنوائی کے لیے منظور بھی کر لیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انڈیا اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر تبدیل یا ختم نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انڈیا اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے بھاری رقوم خرچ کر کے بین الاقوامی رائے کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے لابنگ کررہا ہے۔
اگرچہ انڈیا ایک کمزور پوزیشن میں ہے، کیونکہ وہ خود بھی دریائے برہماپتر کے پانی کی نسبت سے ایسی صورت حال سے دوچار ہے جیسا کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کی صورت حال ہے۔ حال ہی میں چین نے دریائے برہماپتر پر ایک بڑا ڈیم بنانے کے منصوبے کا انکشاف کیا ہے۔ پاکستان کے بین الصوبائی معاہدوں میں اہم اور نافذ العمل معاہدہ ۱۹۹۱ء کا پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے، جس میں چاروں صوبوں کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ صوبوں کے درمیان اس معاہدے کے نفاذ سے متعلق بعض اوقات اختلافات سامنے آتے رہتے ہیں، تاہم ان اختلافات کو ٹکنالوجی، جدید مانیٹرنگ سسٹم اور واٹر آڈٹ کے ذریعے حل کیا جاسکتا ہے۔
پاکستان نے جب ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اپنا سفر شروع کیا تو مغربی پاکستان کی آبادی ۳ کروڑ ۳۰ لاکھ تھی، جو بڑھ کر ۲۰۲۵ء میں ۲۵کروڑ ۴۰ لاکھ ہوجائے گی۔ یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ فی کس پانی کی دستیابی میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی کمی آئی ہے۔ ۹۵ فی صد تک پانی زراعت پر صرف ہوتا ہے۔ زرعی شعبہ ۱۹۵۰ء کے عشرے میں جی ڈی پی میں اپنے حصے کے حساب سے ۵۳ فی صد کی بلند ترین سطح پر پہنچا، اور اس کے بعد تنزلی کا سفر طے کر کے اب ۲۴-۲۳ فی صد کے درمیان پہنچ گیا ہے (اکنامک سروے آف پاکستان ۲۰۲۴ء) ۔ اسی طرح زرعی اجناس کی برآمد ابتداء میں کل برآمد کا تقریباً ۹۹ فی صد تھی، جو ۹۰ فی صد زرِ مبادلہ کمانے کا ذریعہ تھی۔ تاہم، اب بھی پاکستان کی ۷۰ فی صد برآمدات بالواسطہ یا براہِ راست زراعت سے منسلک ہیں۔ اس طرح یہ شعبہ یقیناً ملک کے لیے بہت اہم ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ فرسودہ طریقوں سے جاری کاشت کاری کے باعث ایک جانب تو ہماری فی ایکڑ پیداوار کم ہے، ساتھ ہی پانی کے غیرمؤثر اور بلا ضرورت استعمال اور فراہمی آب کے ناقص نظام کے سبب پانی کی ایک بڑی مقدار ضائع ہوتی رہی ہے۔ فصلوں کے لیے پانی کے استعمال میں جدید سائنسی معلومات اور طریقوں کو اختیار کر کے جو کمی لائی جا سکتی تھی وہ ہم نہیں لاسکے۔ اگرچہ ہم اپنے نہری نظام کی وسعت پر تو فخر کرتے ہیں، جو صدیوں پرانا ہے اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وسیع تر ہوتا گیا ہے، لیکن ان نہروں کو پختہ کرنے پر خاطرخواہ توجہ نہیں دی گئی۔ کچی نہروں کے کناروں اور تہوں سے رس کر پانی کی ایک بہت بڑی مقدار ضائع ہوجاتی ہے۔ بلاشبہ اس طرح پانی کا ایک حصہ زیرزمین آبی ذخیروں کو قائم رکھنے میں بھی صرف ہوتا ہے۔ اسی طرح نہروں اور آبی ذخیروں سے سورج کی شعاعوں سے بخارات بن کر بھی پانی کا ایک حصہ اُڑ جاتا ہے۔ کئی علاقوں میں اس طرح پانی ضائع ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے جن میں بلوچستان سرِ فہرست ہے، جہاں تاریخی طور پر کاریزوں کے زیرِ زمین نظام کے ذریعے اس پر قابو پایا جاتا تھا۔ آج کے دور میں یہ ہدف آبی ذخیروں پر فلوٹنگ شمسی پینل لگا کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے سے پیدا ہونے والی بجلی کو مین گرڈ سے دُور علاقوں میں استعمال کے لیے مہیّا بھی کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی پانی کے ضیاع میں کمی لائی جاسکتی ہے۔ ایک نسبتاً کم خرچ حل ان ذخائر پر فلوٹنگ پلاسٹک گیندوں کو پھیلاکر بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔
یہاں اس چیلنج کو حل کرنے کی تجاویز پیش کی جاتی ہیں:
پاکستان میں چھوٹے بڑے ڈیموں کی کل تعداد ۱۵۰ ہے۔ ایک تقابلی جائزے کے لیے، انڈیا میں ایسے ڈیموں کے تعداد ۵۳۰۰ ہے، جب کہ سیکڑوں ڈیم زیر تعمیر ہیں۔ چین میں ڈیموں کی تعداد ۲۸ہزار ۹سو ہے۔ پاکستان میں ضرورت کا پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ۳۰ دن، جب کہ انڈیا میں ۱۲۰ دن کی ہے۔ پاکستان کی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش زیر تعمیر ڈیم منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد تقریباً ۱۳ ملین ایکڑ فٹ سے بڑھ کر تقریباً ۲۴ ملین ایکڑ فٹ ہوجائے گی۔ ان منصوبوں میں دیامر- بھاشا ڈیم سب سے بڑا ہے، جس میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ۸ء۲ملین مکعب فٹ ہوگی اور ۴۵۰۰ میگاواٹ بجلی بھی یہاں سے پیدا کی جا سکے گی۔ پاکستان میں اکثر ڈیم کثیرالمقاصد ہیں، جن کی افادیت میں پانی ذخیرہ کرنے کے علاوہ، بجلی پیدا کرنا، سیلاب سے بچاؤ وغیرہ شامل ہیں۔ اس سلسلے میں مستقبل میں بننے والے ڈیموں میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو شامل کرنا موجودہ حالات اور مستقبلِ قریب کے تناظر میں بحث طلب ہے۔
پچھلے چند عشروں میں ہماری حکومت کی ناقص منصوبہ سازیوں کے سبب ہم کبھی ’آئی پی پیز‘ (IPPs)کے جال میں پھنس گئے اور کبھی ایل این جی (LNG) جیسے قیمتی سرمائے (ایندھن) کو بجلی پیدا کرنے کے لیے درآمد (Import) کرنے کے لیے ناقابلِ تصور شرائط سے بُنے معاہدوں میں جکڑے گئے۔ پھر یہ بھی کہ ہم اس مہنگی بجلی کے استعمال کے وسیلے سے صنعتی ترقی بھی نہ کرسکے۔ اب ان معاہدوں سے نکلنے کی کوششوں میں مختلف وجوہ کے سبب خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں ہوپارہی۔ چنانچہ ہم اس صورتِ حال سے دوچار ہیں کہ ہم آج بھی اپنی ضرورت سے تقریباً دوگنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور زیرِ تعمیر منصوبے، جن میں دیامیر- بھاشا ڈیم اہم ہے، اس صلاحیت کو دُگنا کر دیں گے۔ بجلی کی پیداوار کو مؤخر کر کے اگر ان ڈیموں کی تعمیر کے کل اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہو تو ایسا کرنا مناسب ہو گا۔ کم از کم مستقبل قریب کے لیے تجویز کردہ منصوبوں کے لیے اس امر کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہمیں فی الحال بجلی پیدا کرنے کے مزید منصوبوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود کہ پن بجلی ایک سستی اور ماحولیاتی اعتبار سے محفوظ ذریعۂ توانائی ہے۔
پانی ذخیرہ کرنے کی موجودہ صلاحیت میں اضافے، پانی کی قلت کی رواں صورت حال اور اس کے مستقبل کے اندازوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کو مزید آبی ذخیروں کی ضرورت ہے۔ تاہم، یہ سوال اہم ہے کہ کیا ہم بڑے آبی ذخائر کی تعمیر کے متحمل بھی ہیں؟ دیامر- بھاشا ڈیم جو کہ پانی کا ایک بڑا ذخیرہ تخلیق کرے گا، پاکستان اس منصوبے کے لیے منظوری دے چکا اور اس کا پابند ہے۔ مزید آبی ذخائر کے لیے چھوٹے ڈیموں پر توجہ دینا ایک بہتر راستہ ہوگا، جن کے لیے صوبہ جات میں متعدد مقامات کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ چھوٹے ڈیم اور آبی ذخائر نسبتاً کم قیمت پر اور قلیل مدّت میں تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری تجویز ہے کہ تمام صوبے ۱۹۹۱ء کے بین الصوبائی معاہدے کے تحت اپنے متعین شدہ فی صد حجم کی مناسبت سے پانی ذخیرہ کرنے کے انتظامات کریں، تاکہ موسمیاتی تغیرات وغیرہ سے پیدا ہونے والی کمی اور آبادی میں اضافے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اضافی ضروریات کو ان ذخائر سے حسب ضرورت پورا کیا جا سکے۔ وفاقی حکومت اس مقصد کے لیے کل اضافی مقدار کا تعین کرے، صوبے اپنے اپنے حصے کا پانی ذخیرہ کرنے کی استطاعت میں اضافے کے لیے کم از کم اپنے مجوزہ حصے کے ہدف کو حاصل کرنے کے پابند ہوں۔
ڈیموں کے جہاں کچھ نقصانات ہیں اور ان سے بچاؤ کی تدابیر ضروری ہیں، وہاں ان کی افادیت کی فہرست طویل ہے، جس میں مچھلیوں کی افزائش، سیاحت کا فروغ اور ان کے آبی ذخائر کی تہہ میں معدنیات کے ذخائر (placer deposits) سے لے کر اس مٹی کی زرخیزی سے بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس بناء پر بڑی تعداد میں چھوٹے ڈیموں کی تعمیر کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ یہاں تک کہ دریائوں اور ندی نالوں کے ساتھ ساتھ موجود آبادی کے اشتراک سے حکومتی سرپرستی میں چھوٹے چھوٹے آبی ذخائر بنانے کے رجحان کو بھی فروغ دیا جائے۔ ہماری نظر میں، ہر وہ منصوبہ جس میں عوام کی ایک بڑی تعداد شامل ہو، وہ انفرادی اور قومی سطح کے فوائد حاصل کرنے کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ ایسے منصوبوں کی طرف خصوصی توجہ دینا ہمارے لیے بڑے بڑے منصوبوں پر عمل درآمد سے زیادہ بہتر نتائج کا ذریعہ ثابت ہو گا۔
مزید یہ کہ زیرزمین پانی کے ذخائر کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر ’الیکٹرک ری سسٹیویٹی سروے‘ (Electric Resistivity Survey) اور اس قسم کے دیگر طریقوں کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ خاص طور پر بارانی اور ریگستانی علاقوں میں اس قسم کے سروے اور ’ہائیڈرلوجک ماڈلنگ‘ سے مدد لے کر زیرزمین پانی کے ذخائر کے مناسب استعمال کی منصوبہ سازی کی جائے۔ ایسا کرنے سے دریائی پانی کی قلّت کے پیش نظر اس پر انحصار کو کم کیا جاسکے گا۔ چولستان جیسے علاقوں میں دریا کی پرانی گزرگاہیں زیرزمین پانی کی تلاش کے لیے موزوں علاقے ہوسکتے ہیں۔
اس مسئلے سے جڑے ایک اہم سوال پر غور و خوض ضروری ہے، اور وہ یہ کہ شعبۂ زراعت کے لیے مستقبل میں پانی کی کتنی ضرورت ہوگی؟ یہ بھی کہ اس ضمن میں ایسی کون سی نئی راہیں ہیں جنھیں اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ پانی کی متوقع ضرورت کو پورا کیا جا سکے؟ مختلف تخمینے بتاتے ہیں کہ زراعت کے لیے کل پانی کا ۹۰ سے ۹۵ فی صد کاشت کاری کے لیے نہری نظام کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے، مگر اس میں سے ۵۰ سے ۶۰ فی صد ضائع ہو جاتا ہے، جس کی بعض وجوہ اُوپر بیان کی گئی ہیں۔ مقدار کے حساب سے یہ ضائع ہونے والا پانی ۶۰ سے ۷۰ ملین ایکڑ فٹ بنتا ہے۔ اس ضیاع کو جس قدر مؤثر انداز میں کم کیا جا سکے اتنا ہی قومی خزانے پر نئے ڈیموں کی تعمیر کے حوالے سے کم بوجھ پڑے گا۔ کیونکہ یہ اقدامات نسبتاٌ کم خرچ اور بآسانی قومی اتفاقِ رائے پیدا کرکے کیے جا سکتے ہیں۔ انھیں ہنگامی بنیادوں پر، بڑے پیمانے پراور بلا کسی تاخیر کے شروع کرنا ناگزیر ہے۔ ان اقدامات کی ایک فہرست درج ذیل ہے:
اس مضمون میں ایسی بہت سی تفصیلات شامل نہیں کی گئیں، جنھیں انٹرنیٹ پر موجود رپورٹ میں دیکھا جا سکتا ہے، جس میں مختلف مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ یہاں پر صرف پاکستان کے مخصوص اقتصادی حالات سر فہرست ہیں، اور منصوبوں کے قابلِ عمل ہونے کے اعتبار سے ترجیحات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں اور ان کے حساب سے نئی ترجیحات مرتب کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے کہ آئی پی پیز وغیرہ کے مسائل سے چھٹکارا پانے کی صورت میں اور ملک کی اقتصادی صورتِ حال بہتر ہوجانے پر دوبارہ پن بجلی کے منصوبوں کی طرف توجہ کرنا، وغیرہ۔ اس بنا پر تمام مسائل اور ان سے نبردآزما ہونے کے ممکنہ طریقوں کونظر میں رکھنا ضروری ہے۔ ہماری ٹیم کی تیار کردہ جس رپورٹ کا حوالہ دیا گیا، اس مجموعی صورت حال کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔
یہ بات امید افزا ہے کہ پاکستان میں پانی کی قلت سے متعلق خطرات کو حکومتی سطح پر، ماہرین سائنس و ٹکنالوجی نے اور سماجی مسائل پر نظر رکھنے والے اہلِ علم و دانش نے شدّت سے محسوس کیا ہے اور پچھلے چند برسوں میں اس ضمن میں تحقیق کے نتیجے میں متعدد معیاری مقالے شائع ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین اور اداروں کا بھی اس کام میں بڑا حصہ ہے۔ مگر جو بات تشویشناک ہے وہ یہ کہ ایسی آگہی عوامی سطح پر موجود نہیں۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے ہدف کو ہم نے مقدّم رکھا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہماری غذائی اور دیگر ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں اور ساتھ ہی ہماری بین الاقوامی زرعی تجارت کا میزانیہ درآمد کی جانب کئی بلین ڈالر بڑھ گیا ہے ( External Trade, Pakistan Bureau of Statistics 2023)۔
۲۰۲۳ء میں یہ خسارہ۵۵ء۲۷ بلین ڈالر تھا (Agricultural Performance Finance Division 2022-2023 )۔ یہ صورت حال اس کے باوجود رہی کہ اس سال پاکستان نے گندم اور چینی کی ریکارڈ مقدار برآمد کی۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ زرعی پیداوارمیں اضافہ اپنی موجودہ صورت میں زرعی تجارت کے خسارے کو کم کرنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے، کہ پاکستان کی کل برآمدات میں ۷۰ فی صد حصہ براہِ راست زرعی پیداوار اور اس سے وابستہ اشیاء کا ہے۔ یہ صورت حال درج ذیل اقدامات کا تقاضاکرتی ہے:
اُوپر بیان کیے گئے نکات کی روشنی میں قابلِ کاشت زمین میں اضافے سے پہلے ہمارے لیے موجودہ قابل کاشت زمین کی زرعی پیداوار میں اضافے اور فصلوں کے انتخاب میں بہتری لانے کے مواقع پر توجہ کرنا اہم ہو گا، جن سے زرعی تجارت کے خسارے میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ مزید یہ کہ زراعت سے وابستہ مصنوعات جن میں کپاس سب سے اہم ہے۔ ان کی پیداوار، ان کی قدر بڑھانے اور زیادہ قیمتی اور قابلِ قدراشیاء کی تیاری وغیرہ پر توجہ دینا بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس سلسلے میں ٹیکسٹائل کی صنعتوں کو جدید نہج پر اٹھانے کی سعی کرنا ہوگی، تاکہ ہم محض کپاس کی بیلز اور دھاگے سے آگے بڑھ کر زیادہ قدرو قیمت والی اشیا برآمد کرسکیں۔ اس سلسلے میں حکومتی سرپرستی میں توانائی کی سستے داموں فراہمی کو یقینی بنانا ہماری مصنوعات کے لیے بین الاقوامی مسابقت میں اہم کردار ادا کرے گا۔
زرعی اجناس کی برآمدات کو متنوع بنانے پر توجہ دینا ہو گی تاکہ زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ اُٹھایا جاسکے۔ اس سلسلے میں بتدریج زراعت پر انحصار والی معیشت سے ایک کثیرالجہت معیشت کی طرف پیش قدمی کرنا ہوگی۔ ایسا کرنا مستقبل میں پانی کی قلت کے دباؤ کو کم کرنے میں بھی معاون ہو گا۔
دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ’’کیا پانی کی قلت پر قابو پانا آج ہمارے لیے اہم ترین مسئلہ ہے؟‘‘ اگرچہ اس تحریر کے ابتدائی حصے میں اس مسئلے کی اہمیت اور شدت پر گفتگو ہو چکی ہے اور اس سے نبردآزما ہونے کے لیے چند تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔ تاہم، یہاں ہم اپنے پہلے سوال سے وابستہ گزارشات کی روشنی میں چند مزید معروضات پیش کرتے ہیں۔
اس بات میں کوئی کلام نہیں کہ مستقبل قریب میں پانی کی قلت پاکستان کے لیے اہم ترین مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ بن کراُبھر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں، ایک جانب تو عوام الناس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، قومی ترقی متاثر ہو گی، اوردوسری جانب اس سے بین الاقوامی اور اندرونی تنازعات بھی سر اٹھا سکتے ہیں۔ انڈیا سے سندھ طاس معاہدے سے جڑے مسائل کا ذکر اوپر ہو چکا، جن سے نمٹنے کی تدابیر ضروری ہیں۔ پانی کی اندرونِ ملک تقسیم کے سلسلے میں ۸۰ کے عشرے میں ہم ’کالا باغ ڈیم‘ کے معاملے میں صوبوں کے درمیان کشیدگی کے شاہد ہیں۔ بعدازاں بھی اس قسم کے چھوٹے بڑے تنازعات سر اٹھاتے رہے ہیں۔ اگرچہ ان تنازعات کو ۱۹۹۱ء کے پانی کی تقسیم کے معاہدے کے مطابق اور سی سی آئی جیسے فورمز پر حل کیا جانا چاہیے۔ تاہم، ہم دیکھتے ہیں کہ ان راستوں کے موجودگی کے باوجود پانی سے تعلق رکھنے والے منصوبے عوام اور میڈیا میں موضوعِ بحث بن جاتے ہیں۔ ان بحثوں کے شرکاء میں مکمل معلومات کے فقدان کے سبب بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو عوامی سطح پر پھیل جاتی ہیں۔
اس سلسلے میں حالیہ دنوں کی مثال چولستان کا نہری منصوبہ ہے:
ہم اس منصوبے کے بارے میں چند حقائق پیش کرتے ہیں، جسے ’چولستان کنال پروجیکٹ‘ کہا جا رہا ہے، جو ’گرین پاکستان انیشیٹیو‘ کا ایک جزو ہے۔ اس کے ذریعے پہلے مرحلے میں چولستان کی ۴۵۲ ہزارایکڑصحرائی زمین کو قابلِ کاشت بنایا جائے گا اور اس منصوبے کی اہم شریان یعنی نہرچولستان ۱۷۶ کلو میٹر طویل ہو گی، جب کہ اس سے مشرق کی طرف نکلنے والی مروٹ نہر ۱۲۰ کلومیٹر طویل ہوگی، جس سے آگے چھوٹی نہروں کا ایک جال بچھایا جائے گا جو مجموعی طور پر ۴۵۲ کلومیٹرطویل ہوگا ۔ منصوبے کے اس پہلے حصے پر ۲۱۱ بلین روپے خرچ ہوں گے۔ IRSA (انڈس ریور سسٹم اتھارٹی) نے فروری ۲۰۲۵ء میں اس منصوبے کے لیے پنجاب حکومت کو پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، جس کی صوبہ سندھ نے مخالفت کی ہے۔ اس کے باوجود کہ موجودہ صدرِ مملکت مبینہ طور پر اس سے پہلے جولائی ۲۰۲۴ء میں اس منصوبے کی توثیق کرچکے ہیں۔ چولستان کی سیرابی کے دوسرے مرحلے میں نہری نظام کو مزید توسیع دے کر اس سے ۷۴۴ ہزار ایکٹر اضافی رقبے کو سیراب کرنے کا منصوبہ ہے۔
۲۰۲۳ءمیں ۱۰ اور ۱۴؍اگست کے درمیان سیلابی صورت حال کے باعث انڈیا نے ۸۰سے ۱۰۰ ہزار کیوسک کا ریلا ستلج اور بیاس کے مشرقی دریاؤں کے ذریعے پاکستان کی طرف چھوڑا، جس سے پاکستان کے کئی شہروں میں سیلاب سے تباہی آئی۔ تاہم، ریکارڈ بتاتا ہے کہ ایسی سیلابی صورت ۳۵ برسوں میں ایک بار ہی پیدا ہوئی، جب کہ اس سے برعکس یعنی خشک سالی کی کیفیت متعدد بار سامنے آئی ہے۔ مزید یہ کہ ایشین ڈویلپمنٹ بینک کی ۲۰۱۰ء کی رپورٹ جو گلیشیروں کے پگھلنے کے بارے میں ہے، آنے والے برسوں میں پانی کی شدید قلت کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایسی صورت حال میں پانی کے استعمال کے بڑے منصوبوں سے اس وقت تک اجتناب بہتر ہوگا، جب تک ہم واٹر مینجمنٹ کے دیرینہ مسائل کو حل نہیں کر لیتے۔
اُوپر بیان کردہ تفصیلات کی روشنی میں مستقبل میں پانی کی دستیابی میں کمی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ایسے حالات میں قابلِ کاشت رقبے کو بڑھانے کے ایسے منصوبوں پر عمل درآمد، جن میں اضافی پانی درکار ہو گا، تشویش پیدا کرتے ہیں۔ چولستان کی سیرابی جیسے منصوبوں کو محض سیلابی پانی پر تکیہ کر کے نہیں بنایا جا سکتا۔ غرض یہ کہ چولستان میں بنائے جانے والے نہری نظام کے لیے پانی کی ضروریات کو موجودہ زرخیز زمینوں کے پانی میں کٹوتی کر کے ہی پورا کیا جا سکے گا، جہاں پہلے ہی پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ اس اضافی کٹوتی سے جنوبی پنجاب ہی نہیں بلکہ صوبہ پنجاب کی تمام نہری زمینیں متاثر ہوسکتی ہیں، کیونکہ پنجاب حکومت کو اپنے طے شدہ حصے ہی میں سے یہ پانی چولستان کی سیرابی کے لیے مہیّا کرنا ہوگا۔ مزید یہ کہ اگر کسی انداز میں بھی دریائے سندھ کے زیریں بہاؤ کے لیے مقرّرہ پانی کے حصے کو کم کیا جاتا ہے تو جنوبی پنجاب سے لے کر دریا کی انتہا پر موجود ڈیلٹا سے متصل اراضی تک بلکہ ڈیلٹا کی آبی حیات اور ماحولیات بھی متاثر ہوں گے۔
اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ، زرعی پیداوار اپنی موجودہ صورت میں زرِ مبادلہ حاصل کرنے کا کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اس کے لیے قابلِ کاشت رقبے کو بڑھانے کے نتیجے میں ہم پانی کے استعمال میں اضافہ کریں گے اور اس اعتبار سے مزید دباؤ کی کیفیت میں آ جائیں گے۔ اس بنا پر چولستان کی سیرابی جیسے منصوبوں کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے یہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے پانی کے ترسیلی نظام کی مرمت اور اس کے استعمال کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے درست کرکے پانی کی بچت کا سامان کرنے پر توجہ دیں، اور پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں۔ ان اقدامات کے نتیجے میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہمیں جو اضافی پانی دستیاب ہوگا، وہ وقت قابلِ کاشت زمین میں اضافے کے لیے موزوں ہوگا۔ کیونکہ چولستان کی سیرابی جیسے منصوبے کی تکمیل میں کئی سال لگ جائیں گے، لہٰذا اس طرف سوچا جا سکتا ہے کہ اس منصوبے کو دو بڑے حصوں کے بجائے، چھوٹے چھوٹے کئی مراحل میں مکمل کیا جائے، اور جیسے جیسے دیگر اقدامات کے نتیجے میں پانی کی اضافی مقدار دستیاب ہوتی جائے، اسی رفتار سے یہ منصوبہ اپنی تکمیل کی طرف گامزن رہے۔ کیونکہ اس منصوبے کے بعض پہلو ہماری دفاعی ضروریات سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس پہلو کے پیشِ نظر منصوبے کی ترجیحات کو ترتیب دینا مناسب ہوگا۔
اس ضمن میں یہ بات بھی اہم ہوگی کہ پانی کا وہ حصہ جو ریگستان کی طرف ارسال کیا جانا ہے اور بالخصوص سیلابی پانی کو مجوزہ نہروں میں ایک عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے تدابیر کی جائیں، تاکہ بعدازاں وقت ِضرورت استعمال کیا جا سکے۔ اس میں پانی کو بخارات بن کر ضائع ہونے سے روکنے کی تدابیراہم ہیں۔
پاکستان کی نا قابلِ کاشت زمین کے مفید استعمال کے موضوعات پر سوچنا اور ایسے قابلِ عمل منصوبوں پر آگے بڑھنا قابلِ تحسین عمل ہوگا کہ جس سے چولستان، تھرپارکر یا تھل وغیرہ کی زمینوں کو ملک کے لیے اور ان علاقوں میں بسنے والوں کے لیے منفعت بخش بنایا جاسکے۔ ایسی کسی بھی پیش رفت کے لیے ملک کی تمام اکائیوں اور بالخصوص منصوبوں کے لیے زیرِ غور علاقوں اور منصوبوں سے متاثر ہونے والے علاقوں میں بسنے والوں کو منصوبہ بندی کے لیے مشورے میں شامل رکھا جائے اور تمام اقدامات ایک مشترکہ اور قابلِ قبول لائحہ عمل کے تحت ہی کیے جائیں۔