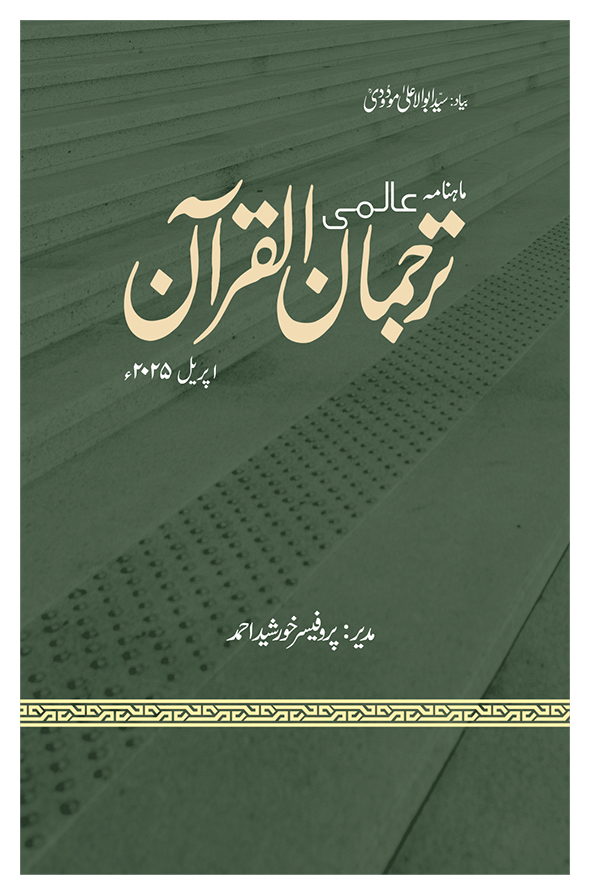
عالم عرب میں علّامہ محمد اقبال کے پہلے پہل تعارف کے سلسلے میں مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ [م: ۱۹۹۹ء]کی کتاب روائع اقبال کو زیادہ تر کریڈٹ دیا جاتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اس کتاب کے چند ایک مضامین اسلامی ادب کا شاہکار ہیںاور اپنی اثر انگیزی میں جواب نہیں رکھتے۔ روائع اقبال کا پہلا ایڈیشن دارالفکر، دمشق سے ۱۹۶۰ء میں شائع ہوا تھا۔ اس مجموعے سے پہلے مولانا ابوالحسن کا اقبال پر ایک مختصر سا کتابچہ شاعر الاسلام الدکتور محمد اقبال کے عنوان سے ۱۹۵۱ء میں دارالکتاب العربی، مصر سے شائع ہوا تھا۔ لیکن ان دونوں کتابوں سے بھی پہلے مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب کے رفیق مولانا مسعود عالم ندوی [م:۱۹۵۴ء]نے ہفت روزہ الرسالہ مصر کے ۸نومبر ۱۹۴۸ء کے شمارے سے محمد اقبال شاعر الشرق والاسلام کے عنوان سے مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جو پانچ قسطوں پر مشتمل تھا۔
الرسالۃ اُن دنوں استاد احمد حسن الزیات [م:۱۹۶۸ء]کی ادارت میں جاری عالم عرب کا سب سے معیاری ادبی پرچہ شمار ہوتا تھا۔ اس مجلے نے شیخ علی طنطاوی [م:۱۹۹۹ء] جیسے کئی عظیم ادیبوں کو دنیائے ادب سے روشناس کرایا تھا۔ اس زمانے میں کسی ادیب کی شہرت اور اعتبار کے لیے اس مجلے میں شائع ہونا کافی سمجھا جاتا تھا، جس طرح ہمارے یہاں اردو مجلات میں مولانا صلاح الدین احمد [م: ۱۹۶۴ء] کے ادبی دنیا لاہور کو کسی زمانے میں یہ حیثیت حاصل تھی، لیکن الرسالہ اپنے معیار میں اس سے کافی بلند تھا۔ مولانا مسعود عالم ندوی نے ۴۳ سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کیا، وہ زندگی بھر دمے کا شکار رہے۔ انھیں اس کی کمی کا سامنا رہا کہ چند رفقا کے علاوہ، ان کے احباب اور پھر اگلی نسل کو عربی زبان وادب سے سروکار نہیں ہے۔ عربی زبان میں بانی ٔجماعت اسلامی سیّدمودودی کی کتابوں کے جن تراجم نے شہرت ومقبولیت پائی تھی، ان میں سے کئی کتابیں مترجم کی حیثیت سے آپ کے نام کے بغیر بھی شائع ہوئیں۔
لہٰذا مسعود عالم صاحب کو عرب دُنیا میں وہ مقام نہیں مل سکا جس کے وہ بجا طور پر مستحق تھے۔ ]دراصل وہ اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، اُن کے تھوڑے کام کو بھی بہت بہتر بنا کر اُنھی کے نام سے پیش کرتے تھے، اور اکثر صورتوں میں اپنے نام کو شائع نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان تراجم کو مؤثر بنانے کے لیے بڑی محنت اور جاں کاہی سے کام لیتے تھے۔ س م خ[
مولانا ابوالحسن علی ندوی نے نقوش اقبال کے دیباچہ میں اپنے اس رفیق کے بارے میں لکھا ہے کہ ’’مولانا مسعود عالم صاحب کی اقبال کے بارے میں حمایت، حمیت تک پہنچی ہوئی تھی، وہ ان کے بڑے پُرجوش مبلغ تھے۔ انھیں یہ بات کھلتی تھی کہ ٹیگور [۱۸۶۱ء-۱۹۴۱ء] اقبال کے مقابلے میں بلاد عربیہ میں زیادہ روشناس ہیں‘‘۔ مولانا مسعود عالم ندوی نے اپنے اسی احساس کے جذبے سے اقبال پر اپنے سلسلۂ مضامین کا آغاز کیا ہے‘‘۔
اقبال خوش نصیب تھے کہ آپ کی زندگی ہی میں ڈاکٹر عبد الوہاب عزام [م:۱۹۵۹ء]کی شکل میں آپ کو عربی زبان کا ایک مترجم نصیب ہوا، جس نے آپ کے فارسی کلام کوعربی نظم میں ڈھال کر عام کیا۔ عزام کے ترجموں کے بارے میں یہ عمومی احساس پایا جاتا ہے کہ اگر وہ عربی نثر میں اقبال کا ترجمہ پیش کرتے تو یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا، اور اس سے اقبال کی بہتر ترجمانی ہوتی ،جس کا ایک نمونہ آپ کی نثر میں لکھی ہوئی کتاب محمد اقبال سيرته وفلسفته وشعره میں ملتا ہے۔ ویسے علامہ اقبال کی وفات سے تین سال قبل مصری مجلہ الرسالۃ میں سید ابوالنصر احمد الحسینی کے پانچ سلسلہ وار مضامین الدكتور محمد إقبال: فلسفۃ، معالم الاتفاق والاختلاف بينه وبين فلاسفة الغرب کے عنوان سے مارچ ۱۹۳۵ء میں شائع ہوئے تھے۔ سید ابوالنصر غالباً حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتے تھے۔
ہمارے خیال میں علامہ اقبال کی شاعری کو عالم عرب میں مقبول بنانے کا اصل سہرا، ڈاکٹر محمد حسن الاعظمی کو جاتا ہے۔کراچی میں ۱۹۴۹ء میں مؤتمر اسلامی کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اعظمی صاحب اس زمانے میں مؤتمر سے وابستہ تھے ۔ اس کا نفرنس کے انعقاد اور کامیابی کے لیے انھوں نے بھر پور کوششیں کی تھیں ۔آپ نے کانفرنس کے دوران عرب مندوبین کے لیے ترجمانی کا فریضہ انجام دیا۔ اس زمانے میں نواب زادہ لیاقت علی خان [م:۱۹۵۱ء] پاکستان کے وزیراعظم تھے۔ اس کانفرنس میں سیدامین الحسینی [م: ۱۹۷۴ء] مفتی اعظم فلسطین بھی شریک ہوئے۔ اس وقت پاکستان نیا نیا بنا تھا۔ وزرا اور سیاسی قائدین قومی خدمت اور ملک کو ترقی دینے کے جذبے سے سرشار تھے۔ اسلامی نظریۂ حیات کے بارے میں بھی بیش تر سیاست دان مخلص تھے۔ اعظمی صاحب قائدین کے نزدیک آ گئے اور انھوں نے ان حضرات کو عربی سیکھنے کی افادیت سے آگاہ کیا۔ سردار عبدالرب نشتر[م:۱۹۵۸ء] ،ڈاکٹرفضل الرحمٰن [م:۱۹۶۰ء] اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی [م:۱۹۸۱ء]جو مرکزی کابینہ میں وزیر تھے، اور خود وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان، اعظمی صاحب سے عربی سیکھنے لگے اور یہ سلسلہ چند ماہ تک جاری رہا۔
ڈاکٹر محمد حسن الاعظمی ۲۵ دسمبر ۱۹۲۲ء کو مبارک پور، اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے، اورآپ کی وفات ۸ستمبر ۱۹۹۵ء کو کراچی میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی عربی زبان وادب کی تعلیم مبارک پور، الجامعۃ السیفیۃ، سورت میں یمنی علما کے ہاتھوں ہوئی تھی، جس کے بعد آپ نے جامعہ ازہر میں داخلہ لیا، اوریہاں سے ۱۹۳۸ء میں درجہ اول امتیاز کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ سند کی حصول یابی کے اس مقابلے میں عالم اسلام کے ایک سو گیارہ اسکالرز شریک ہوئے تھے، اور ان میں سے صرف تیرہ اسکالرز کے حصے میں کامیابی آئی تھی، جن میں سے صرف آپ اکیلے غیر عرب تھے۔ یہ اعزاز پانے والے آپ پہلے ہندستانی تھے۔ ابھی علامہ اقبال زندہ تھے تو ۱۹۳۷ء ہی میں آپ نے آپ کے کلام کا عربی میں ترجمہ کرکے اسے عربی مجلات میں عام کرنا شروع کیا تھا۔
آپ کی زندگی کے دو ہی مقصد تھے: عربی زبان کی ترویج اور مسلمانوں میں باہمی بھائی چارہ، جس کے فروغ کے لیے آپ نے ۱۹۳۸ء میں جماعۃ الاخوۃ الاسلامیہ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تھی ، جس کے صدر ڈاکٹر عبدالوہاب عزام ، اور ممبران میں مشہور مفسر قرآن طنطاوی جوہری اور شیخ الازہر مصطفیٰ المراغی [م:۱۹۴۵ء]شامل تھے۔ طنطاوی جوہری نے وہ تمام کتابیں جو تفسیر الجواہر کی تصنیف میں استعمال ہوئی تھیں، اس ادارے کے کتب خانے کو وقف کردی تھیں۔
آپ پیدائشی طور پر بوہرہ اسماعیلی فرقے سے نسبت رکھتے تھے، لیکن سلطان بوہرہ برہان الدین کی شدید مخالفت کی وجہ سے آپ کو اپنے فرقہ سے نکال دیا گیا تھا۔ آپ نے سو سے زیادہ عربی و اردو تصانیف یادگار چھوڑیں۔ علاوہ ازیں ۱۹۳۹ء میں حکومت مصر کی ایما پر جامع ازہر کی ہزار سالہ تقریبات کی مناسبت سے آپ نے فاطمی حاکم امیر تمیم کا دیوان مرتب کیا۔شاہ فاروق کے دور میں آپ کی تحریک پر ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی دلچسپی سے جامعہ ازہر میں اردو زبان کا شعبہ پہلی مرتبہ کھولا گیا۔پانچ جلدوں میں آپ کی عربی اردو لغت المعجم الاعظم بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
آپ نے پہلے پہل بانگ درا کے مشہور ترانوں اور نظموں کا عربی نثر میں ترجمہ کیا تھا، جسے آپ کے دوست الصاوی علی شعلان[۱۹۰۲ء-۱۹۸۲ء] نے شعر میں ڈھالا۔ ان نظموں کو جو شہرت ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آسکی۔ان میں سے چند اہم نظمیں یہ ہیں: ’شکوہ‘، ’جوابِ شکوہ‘، ’فاطمۃ الزہراء صوت اقبال إلى الأمة العربية ، النشيد الإسلامي : الدِّينُ لَنَا وَالْعُرْبُ لَنَا وَالْهِنْدُ لَنَا وَالْكُلُّ لَنَا (چین وعرب ہمارا)۔ ان کے علاوہ بھی کئی نظمیں ہیں، جو ایک زمانے میں عرب بچوں کے نوکِ زبان تھیں اور ابتدائی اور ثانوی درجات میں کورس میں ترانے کی حیثیت سے گائی جاتی تھیں۔
ان نظموں کا مجموعہ ایک طویل عرصہ بعد ان دونوں کے اشتراک سے فلسفۃ اقبال والثقافۃ الاسلامیہ فی الھند والباکستان کے عنوان سے ۱۹۵۰ء میں عیسٰی البابی الحلبی سے شائع ہوکر مقبولِ عام ہوا۔ اس مجموعے میں اقبال کے کلام کے علاوہ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبیؐ کے شاہکار دیباچہ کا ترجمہ ، اور علامہ سید سلیمان ندوی کی سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعارف، اور دوسرے بہت سے دلچسپ مضامین شامل ہیں۔ پروفیسر محمد حسن الاعظمی نے بانگ درا کی ان نظموں کو پہلے نثر میں ترجمہ کیا تھا، پھر اسے الصاوی علی شعلان نے نظم میں ڈھالا۔ ان نظموں میں یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اقبال کی اردو نظم اور اس کے عربی ترجمے میں سے کون سی زیادہ پُرجوش اور مؤثر ہے۔ان نظموں میں ’شکوہ‘ اور ’جوابِ شکوہ‘ جسے عربی زبان میں حدیث الروح نام دیا گیا تھا، مقبول ترین نظم ہے۔
اس کے سلسلے میں ڈاکٹر عقیل عباس جعفری لکھتے ہیں: ۱۹۶۷ءمیں عرب اسرائیل جنگ کے بعد عوام کے جذبات اور احساسات کے پیش نظر اُمِ کلثوم [م:۱۹۷۵ء]نے ایک نیا نغمہ تیار کیا۔ ان کی آواز سامعین کو سرخوشی میں مبتلا کرتی تھی مگر اس روز وہ جو نغمہ گا رہی تھیں وہ غیر روایتی نغمہ تھا۔ حدیث الروح کے نام سے گایا جانے والا یہ نغمہ علامہ اقبال کی نظم ’شکوہ‘ کا الصاوی الشعلان کے ہاتھوں منظوم عربی ترجمہ تھا۔ جس کا آہنگ ریاض الضباطی نے ترتیب دیا تھا۔ اللہ کے حضور مسلمانوں کی زبوں حالی کا یہ شکوہ کروڑوں عرب عوام کے دل کی دھڑکن بن گیا۔ الصاوی علی الشعلان، بینائی سے محروم تھے اور فارسی میں ایم اے کی سند کے علاوہ اردو پر بھی کمال دسترس رکھتے تھے۔ ان سے قبل پاکستان میں مصر کے سابق سفیر عبدالوہاب عزام نے بھی اقبال کے فارسی اور اردو کلام کو عربی میں منتقل کیا تھا، مگر اہل عرب میں عوامی سطح پر اقبال کا تعارف بہرحال اُمِ کلثوم کی بدولت ہوا۔ اُم کلثوم کے اس نغمے کی شہرت جب پاکستان تک پہنچی تو حکومت وقت نے ۱۸ نومبر۱۹۶۷ء کو انھیں ستارۂ امتیاز عطا کرنے کا اعلان کیا، جو ۲؍ اپریل ۱۹۶۸ء کو انھیں ایک خصوصی تقریب میں مصر میں پاکستان کے سفیر سجاد حیدر نے عطا کیا۔
اُمِ کلثوم کی خواہش تھی کہ اقبال کی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نظم کو بھی اسی طرح اسٹیج پر پیش کرے لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ ایک زمانہ تھا کہ عالم عرب کے ریڈیو اسٹیشنوں سے ہرجمعہ کو اُمِ کلثوم کی آواز میں قصائد، ولد الھدٰی، نہج البردہ، اشرق البدر باری باری نشر ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک اقبال کی حدیث الروح بھی تھی۔ تین ہفتوں کے وقفے سے پابندی سے بروزِجمعہ ایک بجے آتے جاتے ہوئے چائے خانوں میں ریڈیو دوبئی سے اسے بجتے ہوئے سالہاسال تک ہم نے سنا ہے۔ ان دونوں کے اشتراک سے ایک اور مجموعہ الاعلام الخمسہ للشعر الاسلامی کے عنوان سے بھی شائع ہوا تھا۔ اس میں عطار، سعدی، رومی ، حافظ اور اقبال کے منتخب اشعار کا عربی ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔
برصغیر میں استاد محمد حسن الاعظمی کے ہاتھوں عربی زبان کے فروغ اور عالم عرب میں ہندستانی مصنّفین کے تعارف کے لیے کی گئی خدمات کا کماحقہٗ تعارف نہیں ہوا۔ ڈاکٹر محمد حسن الاعظمی کو اب شاذو نادر ہی جانا جاتا ہے۔ ان کی پانچ جلدوں میں لکھی المعجم الاعظم بھی شاید ایک سے زیادہ مرتبہ نہ چھپ سکی، اور وہ طلبۂ مدارس عربیہ میں متعارف نہ ہوسکی۔