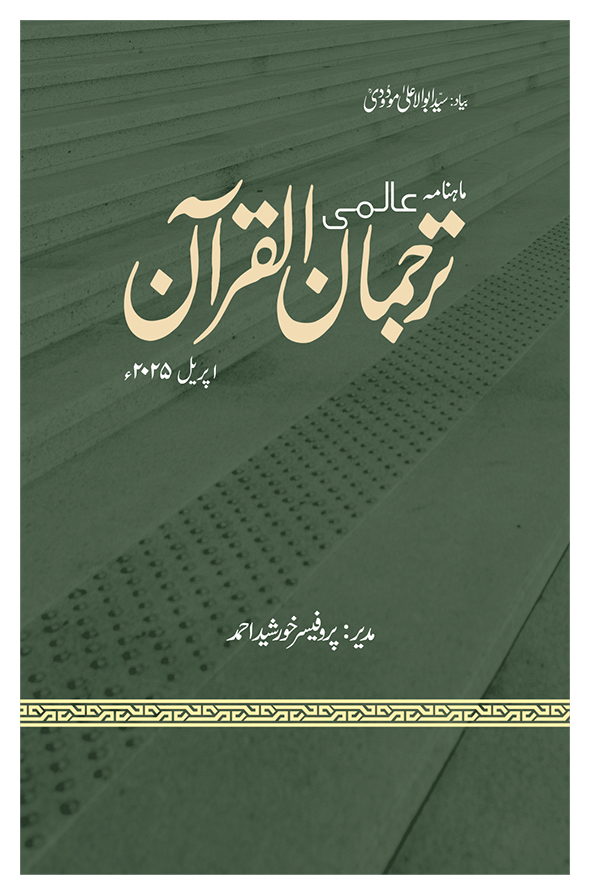
بدقسمتی سے یہ بات مشہور ہوگئی ہے کہ قرآن ایک مشکل کتاب ہے، اس کو سیکھنے کے لیے بہت سے علوم درکار ہیں ، اس کا سیکھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ علما کاکام ہے۔
کیا قرآن سیکھنا واقعی مشکل ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۂ قمر کی آیت ۱۷میں دے دیا ہے: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَہَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ۱۷’’اوریقیناً ہم نےاس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے ، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنےوالا؟‘‘
مفسرین کرام اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں :’’قرآن کریم نے اپنے مضامین عبرت و نصیحت کو ایسا آسان کر کے بیان کیا ہے کہ جس طرح بڑے سے بڑا عالم و ماہر، فلسفی اور حکیم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح ہر عالم اور بے علم جس کو علوم سے کوئی مناسبت نہ ہو وہ بھی عبرت و نصیحت کے مضامین قرآنی کو سمجھ کر اس سے متاثر ہوتا ہے۔’’اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کررکھا ہے،کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟‘‘،اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید آسان تو بے شک ہے، لیکن صرف عبرت وتذکیر، ترغیب و ترہیب کے اعتبار سے،تاہم استنباطِ مسائل بجائے خود ایک مستقل ودقیق فن ہے ، جو کہ خصوصی مہارت اور تحقیق کا محتاج ہے۔
علمائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کو معنی ا ور مضامینِ عبرت و نصیحت کے اعتبار سے عام لوگوں کے لیے بھی سمجھنا آسان ہے، البتہ مسائل اور احکام کا استنباط و اجتہاد صرف علمائے کرام ہی کاکام ہے جس کے لیے علوم قرآن وحدیث اور دوسرے کئی علوم کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔
سورئہ قمر میں یہ آیت چار مرتبہ دہرائی گئی ہے اورہربار اس سے پہلے فرمایا گیا ہے: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ۱۶ (القمر۵۴:۱۶)’’دیکھ لو، کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات‘‘ ، یعنی اگر اس آسان کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو پھر میرے عذاب کے لیے تیار رہو۔
یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ عام آدمی کی حیثیت ایک طالب علم کی ہے اور وہ تذّکر(زندگی گزارنےکے لیے احکام و نصیحت) کی حد تک قرآن کو سیکھے گا۔ تذکّر سے مراد قرآن کو اتنا سمجھنا ہے جس سے ہم زندگی گزارنے کے عمومی اوامر(DOs۔احکامات) و نواہی (DONTs -ممنوعات)کو جان لیں۔یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، ویسے تو ہر مسلمان کو قرآن پر تدبر کرنا چاہیے لیکن یہاں تدبّرسے مراد قرآن پر ایسے غور و فکر کرنا ہےجس سے عصری دینی مسائل کا استنباط یا اجتہاد کیا جائے اور فقہی مسائل معلوم کیے جائیں۔یہ صرف علمائےکرام و فقہائےعظّام کا کام ہے جس کے لیے علومِ قرآن اور دین کی مجموعی تعلیم اورتفہیم ضروری ہے، یہ ہر کسی کا کام نہیں۔ اس بات کو قرآن حکیم میں یوں بیان کیا گیا ہے:كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰہُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِہٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ۲۹ (صٓ۳۸:۲۹)’’یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو (اے محمدؐ!) ہم نے تمھاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر والے اس سے سبق لیں‘‘۔ اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق روزِ قیامت تک اس کی تشریح و تفسیر ہوتی رہے گی اور اس کے مطالب ختم نہیں ہوں گے۔
قرآن سیکھتے وقت یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم اسے کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا اہم ہے کہ قرآن کے اسرارو رُموز پر تدبر کرنا ، علم میں اضافہ کرنا، اس کے ادبی اعجاز پر سردھننا، سائنسی علوم کی روشنی میں آیات کی تکوینی تشریحات سے لطف اندوزہونا یا اس میں بیان کردہ عقائد، معاشرتی،سماجی ، معاشی، معاملات پرغور وفکر کرنے میں اس کتاب کے برحق ہونے کے دلائل ہیں لیکن یہ اس کے ضمنی فوائد ہیں۔قرآن کا اصل مقصدیہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑپر اس سے عملی راہنمائی حاصل کی جائے تاکہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں،جس کا ذکرسورئہ فاتحہ میں بیان ہوا اورہم نماز میں روزانہ کم ازکم ۳۲ مرتبہ اللہ سے یہی درخواست کرتے ہیں۔
قرآن نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کی کایا پلٹ دی اس لیے کہ ان کا قرآن سیکھنا ’علم برائے عمل‘ تھا۔ابی عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ سے مروی مسند احمد کی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ’’ایک صحابی سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس دس آیات پڑھتے تھے اور اگلی دس آیات اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ پہلی دس آیات میں علم و عمل سے متعلق چیزیں اچھی طرح سیکھ نہ لیتے ،یوں ہم نے علم وعمل کو حاصل کیا ہے‘‘۔
قرآن سے ہماری زندگی اسی لیے تبدیل نہیں ہو رہی کہ عام طور پر قرآن پڑھتے یا سیکھتے وقت یہ مقصد نہ ہمارے ذہن میں واضح ہوتا ہے اور نہ ہمارے عمل سے اس کا اظہار۔ قرآن کو ’علم برائے عمل‘کے مقصد سے پڑھنے اور سیکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر ہر آیت میں اپنی زندگی کےلیےعملی نکات تلاش کرنے کی کوشش کریں اور ان کو ترجیحاً اپنی انفرادی زندگی میں نافذکریں اور ساتھ ہی اجتماعی زندگی میں اس کے نفاذ کی جد و جہد کا حصہ بنیں۔
یہ بات یاد رکھنا بھی انتہائی اہم ہےکہ اجتماعی نظام، افراد کے مرہون ِ منت ہے۔ انفرادی عقائد و تصورات میں کمزوری ،اجتماعی نظام کی پوری عمارت کو کمزور کرنے یا گرانے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ اصول اجتماعی جدوجہد کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ افراد کی اپنی فکر اوردین کا منہج صحیح نہ ہو تو اجتماعی اصلاح کا تصور خیالِ خام کے سوا کچھ نہ ہوگا ؎
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ
اس لیے اقامت دین کی اجتماعی جدوجہد میں ہمیں انفرادی حیثیت میں قرآن فہمی کو اپنی ترجیح بنانا ہوگا۔
قرآن سیکھنے کے لیے چند اہم باتوں کی طرف توجہ ضروری ہے:
اللہ تعالیٰ نے سورۂ آل عمران میں فرمایا ہے :ھُوَالَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْہُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ ھُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِہٰتٌ۰ۭ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِہِمْ زَيْـغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَہَ مِنْہُ ابْتِغَاۗءَ الْفِتْنَۃِ وَابْتِغَاۗءَ تَاْوِيْلِہٖ۰ۚ۬ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَہٗٓ اِلَّا اللہُ ۰ۘؔ (اٰلِ عمرٰن ۳:۷)’’وہی خدا ہے، جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں: ایک محکمات، جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
شیطان محکمات کی بجائے انسان کو متشابہات اور عملی زندگی کے لیےغیرضروری مباحث میں اُلجھا دیتاہے ۔ اقبالؒ نےشیطان کے اس حربے کو شیطان کی زبانی یوں بیان کیا ہے ؎
ہے یہی بہتر الہٰیات میں اُلجھا رہے
یہ کتابُ اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے
خلاصۂ کلام یہ ہے کہ اوّلین ترجیح اور بہتر صورت یہی ہے کہ قرآن کریم استاد سے سیکھیں ، استاد میسر نہ ہو تو انفرادی طور پر کسی تفسیر کا مطالعہ کریں ( زیادہ مناسب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ تفاسیر پیشِ نظر رکھیں)۔ بہتر یہ ہو گا کہ گروپ بنا کے مطالعہ کریں اور یہ اصول ہمیشہ پیش نظر رکھیں جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کردیا ہے : ’’جس نے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے‘‘۔ (ترمذی)
عربی زبان سیکھنا ایک احسن کام ہے، لیکن اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو یہ قرآن نہ سیکھنے کا بہانہ نہیں ہوسکتا۔ الحمد للہ! ہمارے علمائے کرام کا ہم پر بہت احسان ہے کہ آج تقریباً ہر زبان میں قرآن کے تراجم اور تفاسیرموجود ہیں جن سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عربی سمجھنا فی نفسہٖ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں جب ہم قرآن مجید کو سمجھ جائیں تو اس پر عمل کی فکر کریں۔ کیا ابولہب، ابوجہل ، مغیرہ بن ولید، عمرو بن یکرب جیسے ادیب اور لبید جیسے شاعر کو عربی نہیں آتی تھی؟لیکن جب ان کا مقصد قرآن کو سمجھ کر اسے دل میں اتارنا اور اس پر عمل کرنا نہیں تھا تو ’عربی دان‘ ہونے کے باوجود گمراہ ہی رہے۔ان کی عربی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ یہی حالت مستشرقین کی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھتے تو ہیں لیکن اس کے نتیجے میں انھیں ہدایت نہیں ملتی کیونکہ قرآن سے ہدایت لینا ان کا مقصد ہی نہیں ہوتا ۔البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم اتنی عربی سیکھنے کی کوشش ضرور کریں کہ جب تلاوت ہورہی ہو تو ہم اسے سمجھ رہے ہوں اور اگر زبان میں مزید مہارت حاصل کرلی تو یہ قرآن کی تاثیر کوبھی مزید بڑھائے گی اور ہم قرآن پر تدبر اور اس کے رُموز و اسرار سے لطف اندوز بھی ہو سکیں گے۔
نماز کے معیار کو اللہ تعالیٰ نے سورۂ عنکبوت کی آیت۴۵میں یوں بیان فرمایا ہے: اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْہٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ۰ۭ ’’بے شک نماز بےحیائی سے اور فحش کاموں سے باز رکھتی ہے‘‘، یعنی نماز کا اصل معیار (standard) یہ ہے کہ اس کا ایک مسلمان پر یہ اثر ہو کہ وہ فحاشی اور بےحیائی سے رُک جائے۔ ہمیں اپنی نماز کو اس معیار کا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔
اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ایک مسلمان قرآن پڑھے تو اس پر قرآن کے کچھ اثر ات ہونے چاہئیں:
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللہُ وَجِلَتْ قُلُوْبُہُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْہِمْ اٰيٰتُہٗ زَادَتْہُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰي رَبِّہِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ۲ۚۖ (الانفال۸:۲)سچے اہلِ ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سُن کر لرز جاتے ہیں اورجب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنےربّ پر اعتماد رکھتے ہیں۔
اَللہُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِہًا مَّثَانِيَ۰ۤۖ تَــقْشَعِرُّ مِنْہُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّہُمْ۰ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُہُمْ وَقُلُوْبُہُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللہِ۰ۭ ذٰلِكَ ہُدَى اللہِ يَہْدِيْ بِہٖ مَنْ يَّشَاۗءُ۰ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللہُ فَمَا لَہٗ مِنْ ہَادٍ۲۳ (الزمر۳۹:۲۳) اللہ نے بڑا اچھاکلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوجاتےہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے اس کے ذریعے وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ۔
وَاِذَاسَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓي اَعْيُنَہُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَـقِّ۰ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰہِدِيْنَ۸۳(المائدہ۵:۸۳) جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسولؐ پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوجاتی ہیں،اور کہتےہیں کہ ’’پروردگار ! ہم ایمان لے آئے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے ‘‘۔
یہ ہے قرآن پڑھنے اصل معیارِ مطلوب کہ جب مسلمان قرآن پڑھیں تو ان کے دل کی کیفیت ایسی ہو جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے، یعنی ان کےدل لرز جائیں،رونگٹے کھڑے ہوجائیں، بدن نرم پڑ جائیں اورکانپنے لگیں، آنکھوں سے آنسو امڈ پڑیں اورایمان مزیدمضبوط ہوجائے۔ کسی مسلمان کے دل پر قرآن کا ایسا اثر ہو تو وہ تبدیل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب قرآن سمجھ کر پڑھا جائے ۔
یہ بات تو پہلےبیان کی جاچکی ہے کہ اتنا قرآن سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس سے وہ اپنی روزمرہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے۔ اگر استاد میسر ہو تو اس سے سیکھنا افضل ہے لیکن اگر کسی وجہ سے استاد میسر نہ ہو،تو سیکھنے کا ایک نہایت فائدہ مند طریقہ اجتماعی قرآن کلاس ہے۔ اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ایسے گوشے سامنے آجاتے ہیں جو انفرادی مطالعہ میں اکثر کھل کر سامنے نہیں آتے۔
یہ بات ضروری ہے کہ شرکاء دل کی دنیا صاف کرکے شریک ہوں تاکہ قرآن کی امانت اٹھانے کے لیے دل میں صلاحیت پیدا ہو اوربیان کردہ مطلوبہ اثرات مرتب ہوں۔ شرکاء میں یہ ذہنی ہم آہنگی ہو کہ ہم قرآن کا مطالعہ اپنے فائدے اور عمل کےلیے کررہے ہیں۔کلاس سے پہلے ہر فرد اپنے زیر مطالعہ تفسیرسے سیکھنےکی کوشش کرے اور صرف دوسرے شرکاء کی گفتگو اور علم پر اکتفا نہ کرے۔ اس طرح اجتماعی مطالعہ کرنے کی افادیت بہت بڑھ جاتی ہے۔درج ذیل سطورمیں قرآن کلاس کی ترتیب بیان کی گئی ہے:
کلاس کی ابتدا میں ایک فرد(جس کا تعین پہلےسے گذشتہ کلاس میں ہوچکا ہوگا اور جو عمومی طور پر میزبان ہی ہوگا)، اپنی مقررکردہ تفسیر سے رکوع کی تلاوت، رواں ترجمہ، الفاظ کے معانی اور رکوع کا عمومی پیغام بیان کرے ۔
متعلقہ فرد کی تشریح کے بعد ہر ممبر اپنی زیر مطالعہ تفسیر سے اس رکوع میں فکر و عمل کے حوالے سے پیغام سے شرکا کو آگاہ کرے ۔پھر تمام شرکا بحث میں حصہ لیں تاکہ رکوع کا پیغام کھل کر سامنے آجائے،البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک فرد کی طرف سے بیان شدہ تفصیلات دوبارہ بیان نہ کی جائیں تاکہ وقت کا بہتر استعمال ہو سکے۔
عصری حالات کے تناظر میں رکوع کے پیغام پر غور و فکر کریں اور اہم نکات نوٹ کرلیں۔ مطالعہ میں جو نکات تفصیل طلب رہ جائیں اور جن کا جواب زیر مطالعہ تفاسیر میں موجود نہ ہو تو اپنے طور پر کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہ کیا جائے بلکہ ہر فرد بعد میں ان نکات کی تفصیل اور وضاحت کے لیے علمائے کرام سے رجوع کرے اور ان کی بتلائی ہوئی تشریح اگلی میٹنگ میں بیان کرے اور ان آراء کے مطابق حتمی تشریح پر اتفاق کیاجائے ۔
بہتر ہے کہ قرآن کلاس مسجد میں ہو ، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو باری باری ساتھیوں کے گھروں یا کسی متعین جگہ پر بھی کلاس ہو سکتی ہے۔ہر کلاس میں اگلی کلاس کے وقت اور مقام کا تعین کرلیا کریں۔ کھانے پینے سے حتی الوسع اجتناب کیا جائے یا بندوبست میں لازماً سادگی کااہتمام کیا جائے۔
سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے سمجھیں اور جوجو حکم سمجھ آتا جائے اس کے مطابق عمل کرتے جائیں۔ یہی وہ بات تھی جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کی کایا پلٹ دی۔ایک اُجڈ اور جاہل عرب قوم دنیا کی مہذب ترین قوم بن گئی اور ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا جو چشم فلک نے نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں دیکھ سکی۔ جب قرآن کی آیات نازل ہوتیں تو صحابہؓ فوراً عمل کی سوچتے تھے۔ انھوں نے قرآن کو اپنے لیے سمجھا اور اسی لیے ان کی زندگی تبدیل ہوئی۔ اگرمسلمان قرآن اسی طرح پڑھیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنھم پڑھتے اورسمجھتے تھے تو آج بھی ویسی ہی تبدیلی آسکتی ہے جیسے ان کی زندگیوں میں آئی۔صاحبِ تفہیم القرآن نے یہی بات یوں بیان فرمائی ہے:’’اسے تو پوری طرح آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ اسے لے کر اٹھیں اور دعوت الی اللہ کا کام شروع کریں اور جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی ہے اسی طرح قدم اٹھاتے جائیں۔ قرآن کے احکام، اس کی اخلاقی تعلیمات، اس کی معاشی اور تمدّنی ہدایات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اس کے بتاۓ ہوۓ اصول و قوانین آدمی کی سمجھ میں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتے جب تک وہ عملاً ان کو برت کر نہ دیکھے، نہ وہ فرد اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی انفرادی زندگی کو اس کی پیروی سے آزاد رکھا اور نہ وہ قوم اس سے آشنا ہو سکتی ہےجس کے سارے ہی اجتماعی ادارے اس کی بنائی ہوئی روش کے خلاف چل رہے ہوں‘‘ (مقدمہ تفہیم القرآن، جلداول،ص ۳۴-۳۵)
قرآن کلاس کےدرج بالا طریقۂ کار کے مطابق ذیل میں سورئہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی تشریح بطور مثال دی جاتی ہے:
اللہ فرماتا ہے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لے آؤ گے اورپھر یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ ایک دھماکا خیز بیان ہے کہ صرف زبانی کلامی ایمان سے کام نہیں چلے گا۔ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں اچھے اور بُرے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ ایمان لانے کے فوراً بعد آزمائش شروع ہو جاتی ہے اور دین پر قائم رہنے میں مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں۔ اللہ کو تمھارے سب اعمال کا پہلے ہی سے علم ہے لیکن وہ چاہتا ہے تم پر حجّت تمام ہو جائے اور تمھاری اصلیت بھی کھل کر سامنے آجائے کہ مشکلات کے وقت تم اللہ کے کتنے وفادار ہو؟
مومنین کا امتحان، دشمنوں کے مقابلے میں مادی وسائل کی کمی، جسمانی، جذباتی، اور روحانی تکالیف، دنیاوی لالچوں اور بہت سی دوسری مشکلات سے ہوتا ہے۔ غربت، نفسانی خواہشات، دنیا کی کشش ،اقتدار اورشہوانی لذات کی شدت بھی وہ مشکلات ہیں جو دنیا میں پیش آتی ہیں۔موجودہ زمانے میں ایک بہت اہم معاملہ حلال و حرام کی پہچان اور حرام سے بچنا ہے۔ ان سب کا مقابلہ صبر اور استقامت سے تب ہی کیا جا سکتا ہے جب انسان میں اس کے مقابلے کی قوّت موجود ہو۔ یہاں بتا دیا گیاہے کہ وہ قوت اللہ پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے، جس سے وہ زمین پر انفرادی اور اجتماعی طور پر اقامت دین کی جدوجہدکا حق ادا کرنے کے قابل ہوجاتا ہے۔ایمان صرف قولی اقرار نہیں بلکہ اس کا عملی اظہار بھی ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کو پرکھا جا سکے۔ کمزور مسلمانوں اور منافقین پر کوئی مشکل آئے تو وہ ڈگمگا جاتےہیں۔ اللہ لوگوں کے اعمال دیکھ کر ان کو سزا و جزا دیتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی،البتہ یہ اس کا کلّی اختیار ہے کہ کسی کے ساتھ کیا سلوک کرتاہے۔
انسان اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں ہوتا جب تک اس کے اعمال سے یہ واضح نہ ہوجائے کہ وہ اس کا مستحق ہے اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں گیا۔ انصاف وہی ہے جونظربھی آئے، ورنہ اللہ کو تو سب کچھ پہلے ہی سے علم ہے کہ کس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم ہے۔اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ برے اعمال کر کے اللہ کی گرفت سے بچ جائے گا تو یہ ایک انتہائی احمقانہ سوچ ہے، وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بھاگ سکتا۔ بے شک اللہ سننےاور ہرچیز کا علم رکھنے والا ہے، البتہ ایمان کے قولی اور عملی اظہار کے بعد اگر مومنوں سے بشری کمزوریوں کے سبب کوئی گناہ ہوجائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور ان کی نیکیوں کا اجر دیتا ہے۔
ان آیات میں مشرک ہونے کے باوجود والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے،البتہ اگروہ پورا زور لگائیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ تواس کا انکار کیاجائے گا۔وہ ایسی بات کسی دلیل یا علم کی بنیاد پر نہیں کہتے۔ والدین سے حسن سلوک کے بارے آیات سےیہ نکتہ بھی واضح ہے کہ جب اللہ کی محبت اور اطاعت کی بات آئےتو وہ نسب کے قریب ترین رشتوں پر بھی غالب ہوگی۔
آیت۱۰ میں فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد تمھارے پاس آگئی ہے، حالانکہ بظاہر ایسا نہیں تھا اور مسلمان مکہ میں انتہائی مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ یہ قرآن کا منفردطرز استدلال اور اعجازِ بیان ہے کہ وہ چیزوں کو ماضی میں بیان کردیتا ہے جس کا مطلب قطعی یقین کا اظہار ہوتا ہے کہ گویا یہ تو ہوکر رہے گا ۔ علما نے فرمایا کہ یہ دراصل آنے والی مدد(غزوہ بدر اور دوسری فتوحات وغیرہ) کے بارے میں پیشن گوئی تھی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ اللہ زمان و مکان کی قید سے مبّراہے اور اسے ماضی، حال اور مستقبل کی سب حقیقتوں کا علم ہے۔
دورِ نبویؐ میں ایسے بدقسمت اور احمق کفاربھی تھے جو لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ہماری (شرک و کفرمیں) اتباع کرلو ،قیامت کے دن ہم تمھاری جگہ جواب دےدیں گے کہ ہم نے انھیں ایسا کرنے کوکہاتھا اور اس کی سزا ہمیں دی جائے۔ بدقسمتی سےآج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دنیاوی مفادات یا دوسرے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کو اسی طرح کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانےکے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنھیں انھوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں اور ان کی شیطانی چالوں میں نہ آئیں۔
مسلمان مشکلات و مصائب سے مایوس نہ ہوں۔ یاد رکھیں دنیا میں مشکلات مؤمنوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ انھیں کندن بنانے اور اجر دوبالا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہر حال اور مشکل میں دعوت و اقامت دین کا کام جاری رکھیں۔
مسلمان حق پر استقامت سے قائم رہیں تو بالآخر اللہ ان کو دنیا میں فتحیاب کرتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم اس زمانے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بعض اوقات نزدیک ترین لوگ بھی دین میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ان کو کھلم کھلا بتا دیا جائے کہ دین کی بنیادوں پرکوئی سمجھوتا نہیں ہوسکتا ،چاہےوہ ناراض ہوجائیں۔
یہ بڑی تسلی کی بات ہے کہ مؤمنوں سے بشری کمزوری کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہوجائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے،البتہ کوشش کی جائے کہ گناہ سے اجتناب کیا جائے او ر توبہ و استغفار کی طرف توجہ دی جائے۔
کسی کی ایسی کوئی بات گناہ کا سبب نہ بنے کہ وہ قیامت میں آپ کے گناہ کا ذمہ دارہوگا۔ یہ انتہائی احمقانہ اور خطرناک طرزِعمل ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ایسی شیطانی باتوں سے بچ کر رہیں۔
چند مجوزہ تفاسیر: ان کے علاوہ دوسری تفاسیر سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے:
جدید تفاسیر(عصری مسائل): تدبّر قرآن(مولانا امین احسن اصلاحیؒ)،تفہیم القرآن (سید ابوالاعلیٰ مودودی ؒ) فی ظلالِ القرآن (سید قطبؒ شہید)، بیان القرآن (ڈاکٹر اسرار احمدؒ)، روح القرآن (مولانا ڈاکٹر اسلم صدیقیؒ)، محاسن القرآن (مفتی غلام الرحمٰنؒ) تفسیر القرآن کریم (عبد السلام بن محمد بھٹویؒ)
جدید تفاسیر(عصری دینی مسائل):معارف القرآن(مفتی محمد شفیعؒ) ، تفسیر ماجدی (عبدالماجد دریا بادیؒ)، تیسیر القرآن(عبد الرحمٰن کیلانی ؒ) ضیاء القرآن (پیرکرم شاہ الازہریؒ)، آسان ترجمہ و تفسیر قرآن (مفتی تقی عثمانیؒ)
دیگر تفاسیر: بیان القرآن (اشرف علی تھانویؒ)، ترجمان القرآن (ابوالکلام آزادؒ)، تفسیر ابن کثیر (ابو الفدا ابن کثیرؒ)، تفسیر جلالین(جلال الدین السیوطیؒ)، تفسیر عثمانی ( شبیر احمد عثمانی ؒ)، تفسیرمظہری (قاضی ثناءاللہ پانی پتیؒ)،تفسیرقرطبی (ابوبکر قرطبیؒ)،
الفاظ معانی: تدریس لغات القرآن(ابومسعود حسن علوی ؒ)، صفوت التفاسیر(محمد علی صابونیؒ)، مدارک التنزیل (عبداللہ بن احمد محمدبن محمود النسفیؒ)، مفردات القرآن (مولانا محمد عبدہٗ فیروز پوریؒ)، اور مصباح القرآن جس میں مترادف الفاظ رنگین ترجمے کے ساتھ دیے گئے ہیں (آخر الذکر تینوں تفاسیرموبائل ایپ [EasyQuranWaHadith] ) پربھی موجود ہیں۔