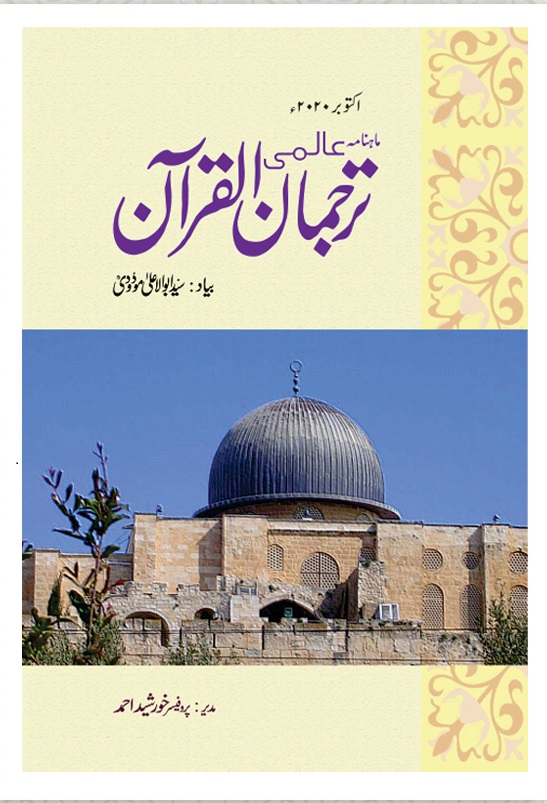
بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم
مولانا سیدابوالاعلیٰ مودودیؒ کا یہ مضمون آج سے ۸۲ سال پہلے ۲۲ جون ۱۹۲۰ء کے روزنامہ زمیندارلاہور میں شائع ہوا تھا۔ اس وقت برطانوی استعمار مسلم دنیا کے حصے بخرے کرنے میں مصروف تھا۔ آج پس کردار امریکہ (برطانیہ کے تعاون سے) انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس خطرناک کھیل کا سب سے عبرت ناک پہلو یہ ہے کہ سامراجی قوتیں مسلمانوں کو بانٹنے اور ان میں سے کچھ کو دوسروں کے تعاون یا کم از کم خاموش تائید سے مغلوب کرنے کی سعی کرتی ہیں۔ یہ کھیل ۵۰۰ سال سے کھیلا جا رہا ہے لیکن مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلتیں اور جو بڑے دانش ور بنتے ہیں وہ یہ فلسفہ بگھارنے سے نہیں تھکتے کہ ہماری باری نہیں آئے گی۔ ہم ’’دوستوں‘‘کی پناہ میں رہیں گے۔ تاریخ کا المیہ یہی ہے کہ اس سے کم ہی لوگ سبق سیکھتے ہیں۔ جو سبق سیکھ لیتے ہیں وہی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج شرق اوسط کے نئے نقشے (restructuring) کا جو ڈراما رچایا جا رہا ہے وہ اس سے مماثل ہے جو سو سال پہلے دولت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کے لیے کیا گیا تھا‘ افغانستان اور عراق اس جنگ کا پہلا مرحلہ ہیں۔ سید مودودیؒ کا یہ مضمون ان کی بالغ نظری اور تاریخی فہم کا شاہکار ہی نہیں آج کی اُمت مسلمہ کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی ایک تازیانے سے کم نہیں۔ یہ مضمون سید مودودیؒ نے اس وقت لکھا تھا جب وہ ۱۷ سال کے نوجوان تھے۔ (مدیر)
ایک ترک مدبر کا یہ قول کتنا صحیح اور مبنی برحقیقت ہے کہ ’’دنیا کی کسی چیز نے ترکوں کو اس قدر نقصان نہیں پہنچایا جس قدر انگریزوں کی دوستی پر اعتماد اور ان کی ایمان داری پر حُسنِ ظن نے پہنچایا‘‘۔
۱۵۸۷ء میں جب اسپین کا بادشاہ فلپ ثانی اپنا عظیم الشان بیڑہ لے کر انگلستان پر حملہ آور ہو رہا تھا تو ملکہ الزبتھ نے سلطان مراد سے نہایت الحاح و زاری کے ساتھ مدد کی درخواست کی تھی۔
’’اگر حضور والا اپنی عظیم الشان سلطنت کی پوری بحری طاقت بھیجنے پر تیار نہیں تو خدارا ساٹھ ستر ہی جنگی جہاز بھیج دیجیے تاکہ اسپین کے اس بت پرست بادشاہ کو سزا دے جو پوپ اور تمام بت پرستوں کی مدد کے غرور پر انگلستان کو تباہ کرنے کے درپے ہے اور پھر اس کا ارادہ ہے کہ انگلستان کو فتح کرکے جناب کی مملکت پر حملہ کرے اور دنیا کا بادشاہ بن جائے۔ اگر آلِ عثمان کا پرشکوہ فرماں روا اور انگلستان کی ملکہ‘ اسپین کی بڑھتی ہوئی ہوس کو دبانے کے لیے متحد ہوجائیں تو نہ صرف اس کا مغرور بادشاہ‘ بلکہ روما کا بت پرست پوپ اور اس کے تمام گمراہ ساتھی تباہ ہو جائیں گے۔ خداوند اپنے نیک بندوں کا محافظ ہے اور وہ ضرور دولت ِ عثمانیہ اور انگلستان کے ذریعے سے دنیا کو بت پرستوں کے وجود سے پاک کر دے گا‘‘۔
اس واقعہ سے تین صدی بعد ہی جب آلِ عثمان کے اس پُرشکوہ بادشاہ کی اولاد کی حالت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو خدا کی قدرت کا عجیب تماشا نظر آتا ہے کہ اسی آلِ عثمان کے شہنشاہ کو اسی ملکہ الزبتھ کے فرزند درئہ دانیال لے کر‘تھریس لے کر‘ آبنائے باسفورس لے کر اگر قسطنطنیہ میںرہنے کی اجازت دیتے ہیں تو لارڈ چمسیفرڈ کے نزدیک یہ بھی ’’ان کا ایک احسان ہے‘‘۔
کیا ہم سامراجیوں کو اپنا دوست سمجھ سکتے ہیں؟
ترکی کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا وتعزّمن تشاء وتزلّ من تشاء کی صداقت پر سب سے زیادہ مضبوط ایمان رکھنے والا ہوگا۔ ترکی کی بدقسمتی کا آغاز تو اٹھارہویں صدی سے شروع ہوگیا تھا۔ اور اس ’’مردبیمار‘‘ کے لیے ڈیڑھ دو سو برس پہلے سے ہی یورپ سے نکل جانے کا نسخہ تجویز کیا گیا مگر واقعہ یہ ہے کہ ’’دنیا کی کسی چیز نے ترکوں کو اس قدر نقصان نہیں پہنچایا‘ جس قدر انگریزوں کی دوستی پر اعتماد اور ان کی ایمان داری پر حسنِ ظن نے پہنچایا ہے‘‘۔
پیٹراعظم اور نکولس تو ترکوں کو یورپ سے نکل جانے کی نصیحت کرتے مرگئے۔ مگر آج الزبتھ کے فرزندوں نے محب ِ شفیق اور رفیقِ صمیم بن کر انھیں نہ صرف یورپ سے بلکہ دنیا سے نکل جانے کا پیام سُنا دیا ہے۔
لیکن یہ عجیب معمّہ ہے کہ ترکوں کی عظیم الشان سلطنت کو ریاستِ نظام بنا کر بھی انگریز اپنے آپ کو ترکوں کا دوست کہتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے۔ اینگلو انڈین کو تو جب کبھی اس لڑائی اور اس تباہی کا الزام ترکوں پر رکھنا ہوتا ہے تو وہ نہایت سنجیدگی سے کہہ دیتا ہے کہ ’’ہم ترکوں کے ہمیشہ دوست بنے رہے۔ مگر انھوں نے ہم سے دشمنی پیدا کی‘‘--- لیکن صداقت اور سچائی کے جنازے پر مجھے بہت آنسو بہانے کی ضرورت ہوئی جب میں نے لارڈ چمسیفرڈجیسے ذمہ دار شخص کی زبان سے یہ سُنا کہ ’’اس جنگ سے پہلے انگریزوں کے تعلقات ترکوں سے نہایت دوستانہ رہے ہیں‘‘۔ تعجب ہے انگلستان کا اتنا بڑا آدمی جسے ملکِ معظم نے ہندوستان پر اپنا نائب بناکر بھیجنے کے لائق سمجھا‘ اس تہذیب و تمدن کے زمانے میں ایسی شدید بے باکی سے اتنا صاف جھوٹ بول سکا۔میں یقین نہیں کرسکتا کہ لارڈ چمسیفرڈ نے دوستی کا لفظ اسی مفہوم کے لیے استعمال کیا ہے جو اس لفظ کے لیے ہمارے دماغوں میں ہے۔ کیا کریمیا میں ساتھ دینے کے ایک دو سال بعد ہی جدّہ پر گولہ باری کرنے والے کو ہم دوست کہہ سکتے ہیں؟ کیا عہدنامہ سین سٹی فانو کی سختیوں کو کم کرانے کا وعدہ کرکے خود قبرص لینے اور آسٹریا کو بوسنیا اور ہرذی گونیا دلوانے کو ہم دوست کہہ سکتے ہیں؟ کیا محمدعلی والی ٔ مصر کی بغاوت میں اسکندریہ پر گولہ باری کرانے اور تمام مصر پر قبضہ کرنے والے کو ہم دوست کہہ سکتے ہیں؟ یقینا ہماری مصطلحاتِ سیاست سے ناآشنا زبان میں دوست اور دوستی کی تعریف اس سے جدا ہے۔ مگر برطانوی لغت میں دوست اسی کو کہتے ہیں جس کے بارے میں مرزا غالب نے کہا تھا ؎
یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے
ہوئے تم دست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو
اس دوستی کا مفہوم ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجیے
انگریزوں کی اسی دوستی کی حیرت انگیز تاریخ اگر لکھنا چاہوں تو شاید کئی جلدوں میں تیار ہو۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ وثائق و حقائق کے دفتر سے انگریزی دوستی کی پوری تشریح کر دوں‘ تاکہ آیندہ اگر کسی انگریز کے منہ سے ’’دوستی‘‘ کا لفظ نکلے تو لوگوں کو اس کے سمجھنے میں کوئی دقّت نہ ہو۔
یہاں میں اٹھارہویں صدی سے آخری جنگ روس تک کے چند واقعات پیش کرتا ہوں۔
ہر شخص جانتا ہے کہ روس ابتدا سے ترکوں کا جانی دشمن رہا ہے۔ اس دشمنی کا جوش پیٹر کے بعد اس کی بیوی کتھرائن میں بہت زیادہ موجزن تھا۔ اس کو مشیروں نے مشورہ دیا کہ اب تک تو ترکوں پر بّری حملے کیے گئے تھے۔ مگر اب ایک بحری حملہ بھی کرنا چاہیے۔ چنانچہ تجویز ہوئی کہ بحیرئہ بالٹک سے یورپ کا چکر کاٹ کر بحیرئہ روم میں جہاز داخل کیے جائیں اور درّۂ دانیال پر حملہ کرکے قسطنطنیہ چھین لیا جائے۔ انگریز اس تجویز کے حامی تھے اس لیے یہ رائے قرار پائی کہ روسی بیڑہ انگلستان کی بندرگاہ میں جاکر جملہ سازوسامان سے آراستہ کیا جائے اور کپتان اور ملاح بھی وہیں سے حاصل کیے جائیں۔ چنانچہ فوراً تیاریاں شروع ہوئیں اور روسی جہاز انگلستان پہنچ گئے۔ یہاں بیڑہ تیا رکیا گیا۔ امیرالبحر انفنسٹن اور بہت سے انگریزی کپتان اس پر سوار ہوئے اور انگریزوں ہی کی مدد سے یہ جہاز اتنا طویل سفرطے کر سکے۔
انگریزی حکومت نے اسپین اور فرانس کی حکومتوں کو لکھ دیا کہ اگر ترکوں کی حمایت میں تم نے اس بیڑے کو کوئی نقصان پہنچایا تو پہلے سے اعلانِ جنگ قبول کرلو--- آخر انگریزوں کی کوشش سے یہ بیڑہ ۱۷۶۹ء میں بحیرئہ روم میں داخل ہوا۔ اور ۱۷۷۰ء کی ابتدا میں شام کے سواحل پر پہنچ گیا۔ قسطنطنیہ پر حملہ نہ کیا جا سکا۔ لیکن محض انگریز افسروں کی ہوشیاری سے نہ صرف یہ بیڑہ بچ کر نکل گیا بلکہ بندرچشمہ پر تمام ترکی بیڑہ صرف انھی کی چالاکی سے تباہ ہو گیا۔ ورنہ روسی امیرالبحر اورلوف تو تمام بیڑے کو خطرے میں ڈال چکا تھا۔
اس جنگ کا سلسلہ عرصہ تک جاری رہا۔ فرانس ترکوں کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح ترکی کی حمایت کا موقع مل جائے مگر انگلستان کی مخالفت کا ڈر تھا اس لیے مجبوراً خاموش رہا۔
لڑائی میں برابر نقصان اٹھانے اور زیادہ طویل عرصہ تک سلسلہ جنگ جاری رہنے سے بیزار ہوکر وزراے عثمانیہ نے خفیہ طریقہ سے آسٹریا سے مصالحت کرانے کی درخواست کی۔
’’باوجودیکہ انگریزی جہاز اور فوجیں روسی بیڑے میں شامل ہیں انگریزوں کو ثالث بنتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ثالث بن کر وہ ہم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں‘‘۔
’’دوسری عیسائی قومیں تو کچھ نہ کچھ سچی بھی ہیں۔ مگر انگریزوں کے قول و فعل کا توکسی طرح اعتبارہو ہی نہیں سکتا‘‘۔
’’تمھارا معبود صرف پیسہ ہے۔ تمھارا مذہب صرف طمع ہے اور بس--- تم نے عیسائیت کو محض دھوکابازی کے لیے ایک آڑ بنایا ہے جو تمھاری مکّاری و بدنیتی کی پردہ دری کر رہی ہے‘‘۔
اس حملہ کی تجویز روسیوں کی تھی اور جہاز بھی زیادہ تر روسی تھے‘ اس لیے مجبوراً اسے روسیوں ہی سے منسوب کرنا پڑتا ہے لیکن درحقیقت اسے انگریزی مہم کہنا چاہیے۔ کارآمد افسر انگریز تھے۔ اس زمانہ کا بہترین سامان جنگ انگریزی تھا۔ پورا سفر صرف انگریزی کوششوں سے ہوسکا اور کامیابی محض انگریزوں کی بدولت ہوئی۔ پھر اس حملہ کو انگریزی حملہ کہنے میں کون سی چیز مانع ہے۔
سرویا کے معاملات میں دل چسپی لینے اور برابر غاصبانہ ارادوں سے دلاشیا اور مالڈیویا کے حکام اعلیٰ سے بغاوت کراتے رہنے کی وجہ سے روس اور ٹرکی کے تعلقات نہایت کشیدہ تھے۔ روس نے جو مطالبات پیش کیے تھے وہ دلاشیا اور مالڈیویا سے ٹرکی کے اقتدار کا بالکل خاتمہ کرنے والے تھے--- انگریز اس وقت بھی روس کے ساتھی تھے یعنی لارڈ چمسیفرڈ کی زبان میں ترکوں کے ’’دوست‘‘ تھے اور روسی سفیرکے ساتھ معاملات طے کرانے کے لیے انگریزی سفیرآرتھ ناٹ بھی قسطنطنیہ آیا ہوا تھا۔ سفراء بابِ عالی سے گفتگو کر رہے تھے اور ابھی کوئی تصفیہ نہ ہوا تھاکہ روس نے بلااعلانِ جنگ دلاشیا اور بالڈیویا پر حملہ کر دیا اور باقی صوبوں پر تصرف کرکے بلغاریہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ظاہر ہے کہ یہ حرکت بالکل خلافِ آئین اور سخت وحشیانہ تھی۔ روسی سفیرنے بہت افسوس کا اظہار کیا اور قسطنطنیہ سے چلا گیا۔ مگر انگریزی سفیرنے نہایت ڈھٹائی کے ساتھ دولت ِ عثمانیہ کے سامنے چند عجیب و غریب شرطیں پیش کیں۔ مثلاً:
۱- نپولین کے سفیرکو (جو روس کے مقابلہ میں دولت ِ عثمانیہ کو بہت ہمت دلا رہا تھا) قسطنطنیہ سے نکال دو۔
۲- مالڈیویا اور دلاشیا روس کو دے دو۔
۳- درّہ دانیال کے قلعے اور توپ خانہ ہمیں دو۔ ورنہ ہم قسطنطنیہ پر حملہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔
’’آپ کو انصاف سے کام لیناچاہیے۔ روس نے بلااعلانِ جنگ ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور برابر خلاف آئین و خلافِ تہذیب حرکات کررہاہے۔ مگر ہم صرف امن کی خاطر یہ سب ذلّتیں برداشت کر رہے ہیں۔ جلالت سلطانی نے دلاشیا اور مالڈویا کے باغی گورنروں کو محض امن کی خاطر بحال کرنے کی بھی ذلّت گوارا کر لی ہے۔ مگر پھر بھی روس اپنی حرکات سے باز نہیں آتا۔ لہٰذا اب ہم اعلانِ جنگ پر مجبور ہیں۔ اور ہمارے اُوپر فرض ہے کہ اپنی حفاظت کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انگریز ہماری امن پسندی اور صبروتحمل کی ضرور قدر کریں گے۔ لیکن اگر وہ اس صریح خلافِ آئین ظلم کے بعد بھی روس کی مدد پر آمادہ ہیں تو ہم مدافعت کا ارادہ کرچکے ہیں۔ اور اگر ترکی کی قسمت میں بربادی ہی ہے تو یقین رکھو کہ وہ آخر وقت تک اپنی عزت کے لیے لڑتا رہے گا‘‘۔
اس کے بعد مزید نامہ و پیام نہایت تہدید آمیز انداز میں ہوتا رہا اور آخرکار جنوری ۱۸۰۷ء کو انگریزی بیڑہ امیرالبحرڈک ورتھ کے ماتحت طمنی ڈرس پہنچ گیا۔ ۱۹ فروری کو عین عیدالفطر کے دن جب کہ ترک عید کی مسرتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے‘ انگریزی بیڑہ کسی اعلانِ جنگ کے بغیر درّہ دانیال میں داخل ہو گیا۔ یہ وقت دولت ِ عثمانیہ کے لیے بہت نازک تھا۔ انگریزی بیڑہ جزائر شہزادگان تک پہنچا۔ وہاں ٹھہر کر انگریزی سفیرآرتھ ناٹ نے دوبارہ اپنے مطالبات باب عالی کے پاس بھیجے اور دھمکی دی کہ انھیں قبول کرلو ورنہ قسطنطنیہ پر گولہ باری کی جائے گی۔ سلطان کو وزرا نے مشورہ دیا کہ فرنچ سفیرکو دارالخلافہ سے چلے جانے کا حکم دیا جائے۔ مگر فرنچ سفیر نے اس کی نہایت شدومد کے ساتھ مخالفت کی اور سلطان کے سامنے ایسی پُرجوش تقریر کی کہ سلطان نے فوراً مدافعت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور دیکھتے دیکھتے تمام سامان تیار ہو گئے۔ انگریزی امیرالبحر نے جب دیکھا کہ قسطنطنیہ تو خطرے سے نکل گیا مگر ہم مصیبت میں پھنس گئے تو وہ فوراً درّہ دانیال سے بھاگا۔ مگر پھر بھی اس کے چند جہاز غرق کر دیے گئے۔ درّہ دانیال میں کافی نقصان اُٹھا کر انگریزی بیڑہ مالٹا چلا گیا اور کوشش شروع کر دی کہ ترکوں کے کسی اور صوبہ پر حملہ کا موقع ہاتھ آجائے۔
اس زمانہ میں محمدعلی پاشا اور مملوکیوں کے درمیان مصر میں لڑائی ہو رہی تھی۔ انگریزوں کی تاریخ میں ایسے موقعوں پر فائدہ نہ اُٹھانے کی منحوس مثال ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی۔ وہ فوراً پانچ ہزار سپاہی لے کر اسکندریہ اور اسے فتح کرکے قاہرہ کی طرف بڑھے۔ محمد علی پاشا مقابلہ کے لیے نکلا اور پے درپے شکستیں دیتا ہوا اسکندریہ تک پسپا کرتا چلا گیا۔ وہاں چند مہینے محصور رہے اور بصد حسرت و یاس ڈیڑھ ہزار جانیں لے کر رخصت ہو گئے۔
۱۸۴۱ء میں محمد علی پاشا نے خود سلطان کے خلاف بغاوت کر دی۔ اور اس کی فوجیں قسطنطنیہ سے تھوڑے ہی فاصلہ پر رہ گئیں۔ سلطان محمد مرحوم نے مجبوراً بہت کمزور شرائط پر صلح کرلی۔ دوبارہ چند ہی برسوں کے بعد اس نے پھر ۱۸۳۹ء میں بغاوت کی اور خراج دینے سے انکار کر دیا۔ اور روضہ نبوی پر سے ترکی محافظین و خدام کو علیحدہ کرکے مصریوں کو مقرر کیا۔ سلطان عبدالمجید مرحوم حرم کا تصفیہ کرنے اور تمام حرکات سے چشم پوشی کرنے پر تیار ہو گئے تھے کہ دول عظمیٰ نے انھیں روکا اور مدد کا وعدہ کیا--- دول کے ساتھ انگریزوں نے بھی فوجی مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن فوراً ہی اپنے اس وعدے کی قیمت میں عرب کی بہترین بندرگاہ عدن پر بھی قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ ایک روسی جنرل نے عجیب و غریب لکھا ہے:
’’انگریزوں کو ہندوستان کے راستہ میں ایک بحری مستقرکی ضرورت تھی۔ اس کے لیے عدن سے بہترین مقام اور کون سا ہو سکتا تھا۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے انگریزوں نے جو تدبیر استعمال کی‘ اس کی نظیر صرف انھی کی تاریخ میں مل سکتی ہے۔ انھوں نے ایک انگریز کمپنی کے جہاز کو عدن کے قریب سمندر میں غرق کر دیا۔ اور پھر فوراً اس کی حمایت کے لیے پہنچ گئے۔ جہاز کے غرق ہونے کا الزام عدن کے عربوں پر لگایا اور شیخ یمن کو گولہ باری کی دھمکی دی۔ وہ بے چارہ اس آفت سے سہم گیا اور مجبوراً تاوانِ جنگ جیب میں رکھ کر ان حضرات نے شیخ کو عدن کی فروخت پر آمادہ کر لیا اور بہت سی رقم کا لالچ دے کر بیع نامہ لکھوا لیا۔ جب قیمت ادا کرنے کا وقت آیا توشیخ کی خاص مُہرکسی طرح چُرا کر یا چوری کرا کے رسید پر لگا لی اور قانوناً شیخ کو ایک پیسہ دیے بغیر عدن پر قبضہ کر لیا۔ سلطان ترکی اس وقت اپنی ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے‘ عدن کی کیا فکر کرتے‘‘۔
اس واقعہ کی صحت و عدم صحت کا ذمّہ دار تو جنرل فیڈروف ہے لیکن اس سے کون انکار کرسکتا ہے کہ عدن پر انگریزی قبضہ آج بھی موجود ہے۔
جماعت اسلامی پاکستان ملک و ملت کی خیرخواہ تمام قوتوں کو ساتھ لے کر ۲۰ سے ۳۰مارچ ۲۰۰۳ء تک اتحاد اُمت کا عشرہ منا رہی ہے۔ یہ دراصل اس امر کی کوشش ہے کہ خیبر سے کراچی اور گوادر تک بسنے والے پاکستانیوں میں یہ شعور بیدار کیا جائے اور اس احساس کو طاقت ور بنایا جائے کہ ہر مسلمان اُمت محمدؐ کا ایک رکن ہے۔ اُمت کی طاقت اس سے ہے اور اس کی طاقت اُمت سے ہے۔
اتحاد اُمت کی دو سطحیں ہیں اور دونوں ہی اہم ہیں۔ پہلی‘ پاکستان کی سطح پر اور دوسری‘ عالمی سطح پر۔
پاکستان کی سطح پر اگر اُمت کا تصور ایک زندہ تصور ہو‘ اتحاد کا رشتہ اُمت ہو‘ معاشرے کی تنظیم اور سرگرمیاں اُمت کی بنیاد پر ہوں تو یہ ہمارے بہت سے مسائل کا حل ہے۔ صوبائیت اور علاقائیت کے لیے تریاق ہے۔ فرقہ پرستی جو مسائل پیدا کرتی ہے ان کا حل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اُمت کا تصور ایک ایسا حیات بخش اور قوت افزا تصور ہے جس کی برکتوں کا احاطہ اسے عملاًاپنانے سے ہی ہوگا۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں جسے کسی وقتی سیاسی ضرورت کے لیے اختیار کیا جائے‘ بلکہ یہ اُمت مسلمہ کی بنیاد ہے۔ جس کو اقبال نے اس اُمت کی خصوصیت اور شناخت قرار دیا تھا اور اسے اس الہامی انداز میں بیان کیا تھا کہ ’’خاص ہے ترکیب میں قومِ رسول ؐہاشمی‘‘۔ یہی وجہ ہے کہ اس تصور کے اصل ثمرات اسی وقت حاصل کیے جا سکتے ہیں جب اس تصور کو خلوص اور ایقان سے اختیار کیا جائے اور اسے ایک طویل المیعاد پالیسی بنایا جائے۔ جب اتحادِ اُمت کی بنیاد تصورِ اُمت ہوگا تو لامحالہ جو اخلاقی معائب ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں ان کا علاج ہوگا اور ملک میں اسلام کی تہذیبی اقدار کو فروغ حاصل ہوگا۔ اُمت کا تصور فرزندان اور دختران اُمت میں بجا طور پر احساس فخر پیدا کرے گا جو مفرب سے مرعوبیت اور اس کی نقالی کا توڑ ہوگا۔
عالمی سطح پر اتحاد اُمت کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ ۶۰‘ ۷۰ کے عشروں میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ متعین تجاویز پیش کرتے رہے کہ اتحاد اُمت کے لیے ٹھوس منصوبوں پر کام کیا جائے۔ اگر ان پر عمل کیا جاتا تو شاید اُمت مسلمہ آج عالمی استعمار کی سازشوں کے لیے نرم چارہ نہ بنتی۔ اب‘ جب کہ دشمن دروازے پر دستک دے رہا ہے بلکہ سر پر آیا ہوا ہے اگر اس وقت بھی بیداری کی ایک عام لہر اُمت کی بنیاد پر نظر آجائے تو یقینا دشمن کے لیے اپنے عزائم کی تکمیل ممکن نہ ہو۔
ذکر ہوتا رہتا ہے کہ وسائل کے لحاظ سے اُمت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا ہے۔ محل وقوع ایسا ہے کہ دنیا پر حکمرانی کرسکتے ہیں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک اُمت سے وابستگی کا احساس کمزور ہے۔ ہماری حکومت کو افغانستان کی تباہی کے لیے کندھے فراہم کرنے میں کوئی تکلف نہ ہوا (اور جانتے بوجھتے اس غلط فہمی کو پھیلایا کہ ہم نے اپنے آپ کو بچالیا ہے)۔ آج جب عراق پر حملے کے لیے امریکہ اپنے دانت تیز کر رہا ہے تو مغربی دنیا تو مجسم احتجاج بن کر کھڑی ہوئی ہے‘دنیا کے ۶۰ ممالک میں ۴۰۰ شہروں میں ۲کروڑ عوام نے ایک ہی دن عراق پر امریکہ کی جارحانہ جنگ کے خلاف علَمِ بغاوت بلند کیا ہے لیکن اُمت مسلمہ میں بیداری کی رمق تلاش کرنا پڑتی ہے۔حج کا ۲۰ لاکھ مسلمانوں کا اجتماع ہو اور وہاں سے دشمن کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے! عیدالفطر اور عیدالضحیٰ کے بڑے بڑے اجتماع جکارتہ سے نائیجیریا تک ہر شہر اور ہر قصبے میں سڑکوں پر آکر ۱۰ منٹ کا مظاہرہ کر دیتے تو امریکہ کو حملہ کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچنا پڑتا اور اس کے جارحانہ عزائم پر اوس پڑ جاتی۔
حقیقت یہ ہے اُمت کا تصور آج مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ رشتہ مضبوط اور توانا ہو‘ ایک عضو کی تکلیف واقعتا سارے جسم کی تکلیف ہو‘ تو مسلمان ایک نئے دَور میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں‘ مسلم اور غیرمسلم ممالک میں جو کوئی بھی احیاے اسلام کے لیے کام کر رہا ہے اس کا فرض ہے کہ اپنے منصوبوں‘ سرگرمیوں اور پروگراموں میں اتحاد اُمت کو اولیت اور ترجیح دے۔ اس حوالے سے جماعت کے عشرۂ اتحاد اُمت میں ملک کے ہر مرد و زن کو شرکت کرنی چاہیے۔
اس سال ملک میں بسنت کی سرگرمیاں جس طرح منعقد کی گئی ہیں وہ سوچنے والوں کے ذہن کے لیے بہت سے سوالات چھوڑ گئی ہیں۔ کیا واقعی ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کے لیے لہوولعب میں اتنی کشش ہے کہ بالکل سر پر منڈلاتے ہوئے خطرات بھی ان سے باز نہ رکھ سکیں؟ کیا حکومت نے تعمیروترقی کے سارے پروگرام مکمل کر لیے ہیں کہ صدر اور گورنر اور صوبہ پنجاب اور لاہور شہر کی ساری انتظامیہ اس ’’مقدس‘‘ سرگرمی میں دل و جان سے مصروف ہو گئیں۔
بسنت منانے کے آغاز کے حوالے سے جو تاریخی روایت مستند طور پر پیش کی گئی ہے اس کے بعد تو یہ بات عقل سے ماورا ہے کہ ہم یہ تقریب اس ذوق و شوق سے منانے پر کیوں مصر ہیں۔ محض تفریح کے لیے کوئی اور سبب کیوں نہیں ڈھونڈھ لیتے؟ یقینا تفریح انسانی زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی طلب رزق کی جدوجہد‘ اخلاقی اور اجتماعی مقاصد کے لیے محنت اور قربانی۔ یہی وجہ ہے کہ دن اور رات کو کام اور آرام کے لیے الٰہی نشانیاں قرار دیا گیا۔ لیکن اس میں اہم چیز توازن و اعتدال اور ان مقاصد اور حدود کا احترام ہے جو اسلام اور اُمت مسلمہ کا شعار ہے۔ اگر تفریح کے نام پر طاؤس و رباب کے طوفان میں قوم کو بہا لے جانا اور غیروں کی ثقافت اور کلچر کو ہم پر مسلط کرنا ہو تو پھر اسے اجتماعی خودکشی کی طرف ایک اقدام کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح اور جس نازک وقت میں اس سال بسنت کے نام پر یہ شرم ناک کھیل کھیلا گیا ہے وہ ان خدشات کو مزید تقویت دینے کا باعث ہے۔
اس سے پہلے بھی اور اس سال بھی اہل درد نے یہ بات بہت شدت سے محسوس کی کہ ان تقریبات میں بڑھتی ہوئی سرکاری سرپرستی کے ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے کاروباریوں نے بھی دل کھول کر حصہ لیا اور کسی کام میں وسائل کی کمی نہ آڑے آئی۔ ایسا معلوم ہوا ہے کہ کوئی سوچا سمجھا پروگرام ہے کہ اس اُمت کو میلوں ٹھیلوں اور تفریحات میں غرق کر دیا جائے تاکہ یہ اپنے اصل مشن اور پروگرام سے غافل ہو جائے اور اخلاقی لحاظ سے اتنی پست ہو جائے کہ کسی حوصلے والے کام کا تصور ہی نہ کرے۔ اس طرح کی تقریبات معاشرے کے مجموعی کلچر پر اثرانداز ہوتی ہیں۔ خاص طور پر نوجوان نسل ان سے اثر لے کر اپنی زندگی کے لیے رویے تشکیل دیتی ہے۔ معاشرے کو دُوراندیش اور بالغ نظر قیادت میسر ہو تو یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اپنے شہریوں کو اس طرح کی سرگرمیوں میں مشغول کرے۔
ہم پاکستانی دنیا کی کوئی عام قوم نہیں ہیں‘ نہ کوئی ایسا گروہ ہیںجس کی اپنی تہذیب اور اقدار نہ ہوں۔ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اعمال کی جواب دہی کے تصور سے آشنا ہیں۔ دنیا کو ایک آزمایش جانتے ہیں۔ پاکستان کا قیام کچھ خاص مقاصد کے لیے ہوا تھا۔ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ہم وہ کچھ کریں جو ہندو ہم سے کروانا چاہے۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا اور اللہ نے ہمیں یہ مملکت دی۔ اسی لیے اسے مملکت خداداد پاکستان کہا جاتا ہے۔
ڈر لگتا ہے کہ اگر ہمارے لچھن یہی رہے جس کا مظاہرہ لاہور کی سڑکوں‘ چھتوں‘ پارکوں‘ کلبوں اور ہوٹلوں میں ۷‘۸‘۹ فروری ۲۰۰۳ء کو حج اور عیدِقربان سے صرف چند دن پہلے اور عراق کے خلاف امریکی جارحیت کے خلاف عالمی احتجاج کے دن سے صرف ایک ہفتہ پہلے کیاگیا ہے‘ وہ ملت اسلامیہ پاکستان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ہی نہیں‘ العیاذباللہ‘ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ (اللہ ہمیں اپنے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے)
یہ وقت یہ عزم کرنے کا ہے کہ آیندہ سال ایسی فضا تیار کی جائے گی کہ بسنت کی تقریب ہمارے ملک میں نہ منائی جائے۔ حکومت اور ملکی اور غیرملکی سرپرستوں کو یہ نظرآجائے کہ وہ اس میں حصہ لے کر لوگوں کو خوش نہیں ناراض کریں گے۔ دستورپاکستان کے تحت ہماری حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ شہریوں کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کو ممکن اور آسان بنائے۔ حکومت کو اپنا یہ فرض ادا کرنا چاہیے اور اس میں معاشرے کی خیر کی طاقتوں سے تعاون لینا چاہیے۔
مسٹر فورڈ اور مسٹرکسنگر٭کے حالیہ بیانات پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کے سفیدفام لوگ اخلاقی حیثیت سے آج بھی اسی مقام پر ہیں جس پر وہ اپنی تاریخ کے ابتدائی دَور میں تھے۔ اُس وقت انھیں نئی دریافت شدہ دنیا کی زمین اور اس کی دولت مطلوب تھی‘ اس لیے وہاں کے اصل باشندوں سے زبردستی ان کی زمین چھین لینا انھیں سراسر جائز نظرآیا اور اس صریح ڈاکا زنی میں انھوں نے اپنے آپ کو بالکل حق بجانب سمجھا۔ اب اُن کو تیل کی ضرورت لاحق ہے اس لیے وہ اِس بیسویں صدی کی آخری چوتھائی میں کسی شرم و حیا کے بغیر ساری دنیا کے سامنے بے جھجک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیل پیدا کرنے والے ملکوں نے ان کے مفاد کو خطرے میں ڈالا تو وہ فوجی کارروائی کرکے ان کی دولت کے چشموں پر زبردستی قبضہ کرلیں گے۔ یہ باتیں اُن کا کوئی عام راہ چلتا آدمی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ خود ان کا صدرِمملکت اور ان کا وزیرخارجہ کہہ رہا ہے اور ان کے پورے ملک میں کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا باضمیر نہیں ہے جو اُٹھ کر ان سے یہ کہے کہ پوری قوم کے نمایندے ہونے کی حیثیت سے دنیا کے دوسرے ملکوں پر ڈاکا مارنے کے یہ ارادے ظاہر کرتے ہوئے تمھیں کچھ تو شرم آنی چاہیے۔
لُطف یہ ہے کہ ان دھمکیوں کا پس منظر خود ان دھمکیوں سے بھی زیادہ شرم ناک ہے جس پر پچھلے ۲۷ برس میں کبھی امریکہ کے لوگوں اور ان کے سیاسی نمایندوں اور ان کے حکمرانوں‘ حتیٰ کہ ان کے مذہبی اور اخلاقی رہنمائوں کے ضمیر نے بھی کوئی خلش محسوس نہ کی۔ پہلے انھوں نے یہ ظلم کیا کہ فلسطین کے عربوں کو ان کے وطن سے جبراً بے دخل کر کے اسے ان یہودیوں کا وطن‘ اور پھر ان کی ریاست بنوایا جو ۲۰ صدیوں سے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ ان کی اس ناجائز ریاست کو بے حساب مالی‘ فوجی‘ فنی اور افرادی طاقت بہم پہنچاتے رہے یہاں تک کہ وہ پے درپے جارحیت کاارتکاب کر کے عربوں کے مزید علاقے چھینتی اور اپنا تسلط وسیع سے وسیع تر کرتی رہی۔ اس کی ان زیادتیوں پر اسے ٹوکنا تو درکنار‘ امریکہ اُلٹی اس کی پیٹھ ٹھونکتا رہا۔ عربوں کے خلاف ہر جنگ میں اسے خفیہ اور علانیہ ہر طرح کی مدد دیتا رہا ‘ اور شرق اوسط میں توازنِ قوت قائم رکھنے کے بہانے اسے اتنی زبردست فوجی طاقت بناتا رہا کہ تمام عرب ریاستیں مل کر بھی اکیلی اس یہودی ریاست کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ گئیں۔
ا س ظلم کو مسلسل ایک چوتھائی صدی تک برداشت کرنے کے بعد تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک جب اسرائیل کے مددگاروں اورحامیوں کے خلاف تیل کا ہتھیار استعمال کرنے پر مجبور ہوگئے تو اب بھی امریکہ کا گمراہ ضمیر اسے یہ محسوس نہیں کراتا کہ یہ مظلوم لوگ صرف انصاف حاصل کرنے کے لیے یہ آخری چارئہ کار اختیار کر رہے ہیں‘ اور اس کی اوندھی عقل اُسے یہ نہیں سجھاتی کہ عربوں کے ساتھ اپنی بے انصافی سے باز آکر وہ ہر اُس دشواری کا سدِّباب کرسکتا ہے جو تیل کی بہم رسانی میں واقع ہو سکتی ہے‘ بلکہ اس کے برعکس وہ عربوں کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے ہمارا تیل بند کیا تو ہم فوجی طاقت سے کام لے کر وہ علاقے ہی تم سے چھین لیں گے جن سے تیل نکلتا ہے۔ دوسرے الفاظ میںاس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو بے انصافی ہم نے تمھارے ساتھ کی ہے وہ جاری رہے گی۔ ہمارا برخوردار اسرائیل تمھارے علاقے چھینتا رہے گا اور چھینے ہوئے علاقوں کو واپس دینے سے انکار کرتا رہے گا۔ تم خون کا گھونٹ پی کر اس ظلم‘ اور ذلّت کو گوارا کرتے رہو‘ اور ہمیں تیل بھی دیتے جائو--- لیکن اگر تم نے انصاف حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی حرکت کی جس سے ہم پر دبائو پڑتا ہو تو ہم پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر بے انصافی کریں گے کیونکہ ہم سوپرپاور ہیں---
خدا رحم کرے اُس دنیا پر جس میں اِس کردار کی قوم سوپرپاور بن جائے۔ (امریکی صدر اور وزیرخارجہ کی طرف سے تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک کو دی جانے والی دھمکیوں پر تبصرہ‘ ۲۸ جنوری ۱۹۷۵ئ)
مغربی محققین واضح تاریخی حقائق کا دیدہ دلیری سے مذاق اڑاتے ہوئے خود قرآن کریم کے حوالے سے وہ بہت سی باتیں دوبارہ اٹھا رہے ہیںجو صدیوں سے زیربحث آتی رہی ہیں اور جن پر مسلم علما اور دانش وروں نے علمی سطح پر بغیر کسی معذرت کے حقائق کو بلاکم و کاست پہلے ہی پیش کر دیا ہے۔
بعض مغربی ناقدین قرآن کریم کی ان آیات کے حوالے سے جن میں جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ایسی آیات کی موجودگی میں‘ جو ان کے بقول ان آیات کو منسوخ کر دیتی ہیں جن میں امن ‘ترقی اور محبت کا پیغام دیا گیا ہے‘ اسلام کو کس طرح ایک امن پسند مذہب کہا جا سکتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ۷۴ کو اس کے سیاق و سباق سے نکال کر بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ ’’اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجرعظیم عطا کریں گے‘‘ (النساء ۴:۷۴)۔
اس آیت مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد مغربی مستشرق یہ کہتے ہیں کہ اسلام لوگوں کو لڑائی اور قتل پر اُبھارتا ہے۔ کاش! یہی مستشرق اس آیت سے اگلی آیت کو بھی پڑھ لیتے اور پھر دونوں آیتوں کو ملا کر ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے۔ رب کریم اگلی آیت میں فرماتا ہے: ’’آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں‘ عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگارپیدا کر دے‘‘ (النساء ۴:۷۵)۔ اس آیت کو اگر صرف ایک غیرجانب دار نظرڈال کر پڑھ لیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلی آیت کس کے خلاف جنگ پر اُبھارتی ہے ؟اگر ظلم‘ تشدد‘ حقوق انسانی کی پامالی کرنے والے سفاک افراد کو ان کے حال پر یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے کہ ہم تو امن کے پرستار ہیں‘ ہم تلوار کو ہاتھ لگا کر گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتے تو کیا یہ رویہ اخلاق کے کسی بھی پیمانے پر پورا اُترے گا؟
اسلام اور قرآن کو کوئی معذرت پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اگر جہاد کی بات کرتا ہے تو دوٹوک‘ سیدھے اور غیرمبہم انداز میں یہ بات کہتا ہے کہ ہر ظالم‘ جابر‘سفاک کے خلاف جنگ کرنا انسانی فریضہ ہے۔ اسلام کا مقصد قیامِ امن و عدل ہے اور اس میں گفت و شنید‘ اخلاقی دبائو‘ترغیب‘ مکالمہ ہرچیز ناکام ہو جائے اور عورتیں‘بچے اور بوڑھے مسلسل ظلم کا شکار ہو رہے ہوں تو پھر اس سے قطع نظر کہ وہ مظلوم مسلمان ہیں یا غیرمسلم‘ ان کی نصرت و امداد مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو یہ دو آیتیں دیتی ہیں۔ ان میں کس جگہ یہ کہا گیا ہے کہ بلاکسی سبب کے جب اور جہاں چاہو مذہب کے نام پر خون بہائو؟
اسی طرح سورۂ توبہ کی ایک آیت کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں غیرمسلموں اور اہل کتاب کے خلاف قتل عام کی اجازت دی گئی: ’’جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روزِ آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسولؐ نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اوردین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ (ان سے لڑو) یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں‘‘ (التوبہ ۹:۲۹)۔ یہاں بھی قرآن کریم یہ بات واضح الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ غیرمسلم اہل کتاب ہوں یا کوئی اور‘ ان کے خلاف صرف اس وقت تک جنگ کی جا سکتی ہے جب تک وہ اسلامی ریاست کی امارت تسلیم نہ کرلیں۔ اصل مقصد ان کو قتل کرنا‘ ختم کرنا‘ تباہ کرنا نہیں ہے بلکہ قانون کی حکمرانی اور امن و عدل کا قیام ہے۔ جہاد کا مدعا انھیں مار مار کر قوت کے زور سے مسلمان بنانا یا صفحۂ ہستی سے مٹانا نہیں ہے۔ اسلام کسی بھی ذی روح بلکہ غیر ذی روح کو بھی تشدد کے ذریعے تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا‘ خواہ وہ حیوان ہوں یا نباتات۔ یہ صرف مغربی سامراجی طاقتوں کا طریقہ ہے کہ وہ جہاں چاہیں ’’تورابورا‘‘ کرنے کا پیدایشی حق بزعم خود استعمال کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ وہ ویت نام ہو‘ کوریا ہو‘ بوسنیا ہرذی گوونیاہو‘ چیچنیا ہو‘ آذربائیجان ہو‘ افغانستان ہو یا عراق وہ جب اور جہاں چاہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا اپنا’’انسانی فرض‘‘سمجھتے ہیں۔
سورۃ المائدہ کی آیت ۵۱ کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ یہود اور عیسائیوں کو دشمن کے مقام پر رکھ دیتی ہے اور اس طرح ان کے خلاف نفرت کے جذبات کو ہوا دیتی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: ’’اے لوگو جو ایمان لائے ہو‘ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بنائو‘ یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انھی میں ہے‘ یقینا اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے‘‘۔ (المائدہ ۵:۵۱)
سلسلۂ مضامین پر غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ آیت ۴۲ سے جس موضوع پر بات کی جا رہی ہے وہ اہل کتاب کا عناد‘ جھوٹ اور دھوکا دہی پر مبنی طرزِعمل ہے جس میں ان کے مذہبی رہنمائوں کا اپنے ذاتی مفاد کے لیے تورات و انجیل کی تعلیمات کو بدل دینا اور اللہ کے ساتھ حضرت عزیر ؑ اور حضرت عیسٰی ؑ کو شریک بنانا ہے۔
پھربتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعتیں مختلف ادوار میں نازل کی ہیں ان میں بہت سی تعلیمات مشترک ہیں۔ اسلامی شریعت بھی انھی اصولوں پر مبنی اور من جانب اللہ ہے‘ اس لیے یہود و نصاریٰ کے بہکائے میں آئے بغیر فیصلے اللہ کی شریعت کے مطابق کیے جائیں‘ باوجود اس کے کہ یہود و نصاریٰ کی کوشش یہ ہو کہ اہل ایمان کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح گمراہ کر دیں۔
اس تفصیل کے بعد جو آیت ۴۲ سے آیت ۵۰ تک بیان کی گئی ہے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہود اور عیسائیوںکو رفیق نہ بنایا جائے کیونکہ یہ تو آپس ہی میں گمراہوں کے رفیق ہوسکتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو سیاق و سباق کی روشنی میں اس سے زیادہ سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس سورہ کے حوالے سے مستشرقین یہ الزام اسلام کو دیتے ہیں‘ اس کا آغاز جن الفاظ سے کیا جا رہا ہے وہ ان محققین کی نگہ انتخاب سے نہ جانے کیوں اوجھل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے: ’’آج تمھارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمھارے لیے حلال ہے اور تمھارا کھانا ان کے لیے۔ اور محفوظ عورتیں بھی تمھارے لیے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی‘ (یہودی یا عیسائی) بشرطیکہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو‘‘۔ (المائدہ ۵:۵)
ایک معمولی عقل کا انسان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جن یہودی یا عیسائی نیک خواتین کے ساتھ رشتہ مناکحت کی اجازت دی جا رہی ہو گویا انھیں اپنے گھر اور اپنے معاشرے میں ایک قابلِ احترام بیوی کا مقام دیا جا رہا ہو اور جن کے ساتھ کھانے پینے کے معاشرتی تعلقات قائم کرنے کی اجازت دی جا رہی ہو‘ ان کے بارے میں کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ تمھارے دشمن ہیں‘ جہاں کہیں مل جائیں انھیں تہ تیغ کر دو‘ تہس نہس کر دو اور صفحۂ ہستی سے مٹا دو!
دوسری جانب کیا قرآن کریم کو یہ چاہیے کہ جو یہودی اور عیسائی بظاہر دوست بن کر آئیں‘ جب کہ ان کا واضح مقصد فتنہ و فساد ہو‘ اہل ایمان کو آپس میں لڑانا ہو‘ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلّم کو دعوت کے بہانے بلا کر زہر بھرا گوشت کھلا کر قتل کرنے کی نیت ہو تو کیا قرآن یا تورات کو ایسے افراد کو جگری دوست بنانے کا مشورہ دینا چاہیے؟ قرآن کریم ہی نہیں‘ کسی بھی کتاب سے ایک جملہ نکال کر اس کو اپنے من مانے معنی پہنانا نہ تو فکری دیانت ہے اور نہ اس کتاب کے ساتھ انصاف۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہا تھا کہ ’’اے لوگو جو ایمان لائے ہو‘ اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھرجائو۔ عدل کرو‘ یہ خداترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے‘‘۔ (المائدہ۵:۸)
ایک اور قرآنی آیت: ’’پس جب ان کافروں سے تمھاری مڈبھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے‘ یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو‘ اس کے بعد (تمھیں اختیار ہے) احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو‘ تاآنکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے‘‘ (سورہ محمد ۴۷:۴)۔ مغربی مستشرق اس آیت کی یہ تعبیرکرتے ہیں کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو جہاں کہیں کفار مل جائیں ان کی گردنیں مارتے چلے جائیں اور کشتوں کے پشتے لگادیں‘ بالکل اسی طرح جیسے کہ بوسنیا ہرذی گوونیا میں بہت سے مقامات پر اجتماعی قبروں کی دریافت سے معلوم ہوا کہ کروٹ اور سرب عیسائیوں نے مسلمانوں کو بلاتفریق جنس و عمرتہ تیغ کیا۔
اس آیت مبارکہ کے نزول سے قبل سورۃ الحج کی آیت ۳۹ اور سورۃ البقرہ کی آیت ۱۹۰ جہاد کی اجازت کے سلسلے میں آچکی تھیں۔ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ اسلامی قانونِ جنگ کی وضاحت جنگ پیش آنے سے قبل ہی کر دی جائے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر مشرکین و کفار کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تحریک کو دبانے اور مٹانے کے لیے اورتمھیں مدینہ سے بے دخل کرنے کے لیے پوری قوت سے مدینہ پر حملہ آور ہو کر اس دعوتِ حق کی روشنی کو بجھا دیں تو جہاد کی اجازت کی روشنی میں تم بھی ان کی قوت توڑنے میں تکلف نہ کرو۔ ’’گردنیں مارنا‘‘ محض قتل کرنے کے معنی میں نہیں بلکہ واضح طور پر ان کی قوت توڑنے کے معنی میں استعمال ہواہے۔
کسی بھی جنگ کی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ مخالف کی قوت کو توڑا جائے۔ اس لیے قرآن کا یہ کہنا اخلاق و عدل کے اصولوں پر مبنی صحیح ترین عمل نظر آتا ہے۔ ہاں اگلی بات یہ سمجھا دی گئی کہ مقصود ان کا بے رحمانہ قتل نہیں بلکہ اگر ان کی قوت ٹوٹ جائے تو انھیں قید میں آنے کے بعد قتل نہیں کیا جا سکتا‘ہرقیدی کو عزت و احترام کے ساتھ لباس‘ کھانا‘ تحفظ دیا جائے گا اور اس کے سامنے یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو فدیہ دے کر آزاد کرا لے یا اسلامی ریاست ان پر احسان کر کے رہا کر دے یا تبادلۂ اسیران میں اسے رہا کر دیا جائے۔ ہمارے علم میں کسی انتہائی ’’پُرامن‘‘ فلسفے پر مبنی مذہب کا کوئی ایسا اصول نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ جب دشمن تم پر حملہ آور ہو تو اپنے دروازے کھول کر سرجھکا کر ادب سے اس کا استقبال کرتے ہوئے اپنی گردنیں قلم کرانے کے لیے پیش کرو اور یقین کرلو کہ تمھاری طرف سے ایک انگلی بھی نہ اُٹھے‘ نہ اس میں سے ایک قطرہ خون ٹپکے!
مستشرقین کے بعض اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش یہ علم کے مدعی بات کرنے سے قبل حصول معلومات بھی کرلیتے‘ مثلاً یہ کہنا کہ مسلم معذرت خواہ (apologists) یہ کہتے ہیں کہ تمام غلط فہمی اس بنا پر پیدا ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے انگریزی تراجم ناقص ہیں‘ اس بنا پر جہاد اور قتال کے بارے میں غلط تصورات پائے جاتے ہیں (الراوندی "Islam and Armageddon")۔ یہ نصف سچائی پر مبنی ایک بیان ہے۔ ہمارے خیال میں بعض صورتوں میں اس کا امکان تو ہے لیکن اصل مسئلہ ترجمے کا نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کا مفہوم اپنے ذہنی مفروضوں کی روشنی میں متعین کرنا ہے۔
تحقیق کا بنیادی اصول ہے کہ زیربحث مسئلے کو براہِ راست اس کے سیاق و سباق میں دیکھا جائے‘ اس کے بعد کوئی رائے قائم کی جائے۔ یہی سبب ہے کہ مستشرقین بعض ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو بنیادی اسلامی علمی اصطلاحات سے ان کی ناواقفیت کا اظہار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ مکّی آیات رحم و عفو و محبت سے بھری ہوئی ہیں‘ جب کہ مدنی آیات‘ مثلاً ’’مشرکین کو جہاں پائو قتل کر دو‘‘ نے ۱۳۴ ایسی آیات کو جو رحم و لطف سے متعلق تھیں منسوخ کر دیا ہے (الراوندی‘ایضاً) نہ صرف مکی و مدنی آیات سے ناواقفیت ظاہر کرتا ہے بلکہ نسخ فی القرآن جیسے اہم مضمون سے مکمل لاعلمی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔
حقیقت واقعہ یوں ہے کہ ۹ ہجری میں جب مسلمانوں نے حضرت ابوبکرؓ کی قیادت میں پہلا حج کیا تو سورۂ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ اور اس کے رسولؐ نے ان مشرکین سے اپنی برأت کا اعلان کیا جن سے اس سے قبل بعض معاہدے ہوئے تھے اور وہ ان کی خلاف ورزی کرتے رہے تھے۔ انھیں مہلت دی گئی کہ وہ آیندہ چار ماہ تک اپنے بارے میں طے کرلیں اور اگر کہیں اور جاکر آباد ہونا ہو تو بلاروک ٹوک چلے جائیں یا اپنی روش بدلنی ہو تو ایساکرلیں۔ اس کے بعد ان کے خلاف عام اعلان جنگ کرتے ہوئے یہ بات سمجھا دی گئی کہ ان چار ماہ کے بعد مشرکین کے خلاف اس وقت تک جنگ ہوگی جب تک وہ اپنی غلطی کا اعتراف (توبہ) کرنے کے بعد نماز اور زکوٰۃ پر عامل نہ ہو جائیں۔
چنانچہ اس آیت سے اگلی آیت میں مشرکین کے حوالے ہی سے یہ ہدایت کی گئی کہ گو ان کے خلاف جارحیت کی اجازت ہے لیکن اگر کوئی مشرک حالت جنگ میں بھی اہل ایمان سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دی جائے اور اسے قرآن سننے اور اہل قرآن کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ پھر اسے مجبور کیے بغیر اور اس پر کسی قسم کا تشدد کیے بغیر اس کے گھر تک اپنی امان اور حفاظت میں پہنچانا مسلمانوں کا فرض ہے۔ چنانچہ فرمایا: ’’اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمھارے پاس آنا چاہے (تاکہ اللہ کا کلام سنے) تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ پھر اسے اس کے مامن تک پہنچادو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے‘‘۔ (التوبہ ۹:۵)
دونوں آیات کو ملا کر پڑھیے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ’’مشرکین کو قتل کرو جہاں پائو‘‘ کے حکم کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ یہ ایک مطلق اجازت نہیں ہے کہ جہاں کسی مشرک کو دیکھا اور نشانہ بنا دیا بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہماری اصل جنگ شرک و کفر کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی مشرک حصولِ معلومات کے لیے اہل ایمان سے پناہ طلب کرتا ہے تو قرآنی حکم کی اطاعت میں اسے نہ ہاتھ لگایا جائے گا نہ قیدی بنایا جائے گا بلکہ اپنی حفاظت میں اسے اس کے گھر تک لے جایا جائے گا۔ یہاں بھی آیت کے ایک حصے کو سیاق و سباق سے الگ کرنے کے نتیجے میں مستشرقین ایک گمراہ کن تعبیرکرکے یہ سمجھتے ہیں کہ انھوں نے خود قرآن سے فلسفۂ تشدد کو ثابت کردیا۔
آقاے دوجہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تمام پہلو اور زاویے حیرت انگیز اور بے مثل ہیں۔ ایسا ہی ایک یگانۂ روزگار پہلو اور انوکھا معجزہ ہے: انسانی دلوں اور ذہنوں کی تسخیر___! انسان کائنات کی سب سے پُراسرار‘ پیچیدہ اور حیرت انگیز چیز ہے‘ جسے آنحضورعلیہ السلام نے بیک نظر مسخرکرلیا۔ یہ تسخیر جسموں کی نہیں‘ دلوں کی تھی۔ جس نے ایک بار ذاتِ گرامی کو دیکھا‘ دیوانہ ہوگیا۔ ایک بار سنا‘ فریفتہ و شیدا ہوگیا۔ نبیؐ کے فیضانِ نظر نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ عقل و فکر‘ شعوروآگاہی‘ سب یکسر بدل کر رہ گئے۔ ان پاکیزہ نفوس نے نور کے اس نیروتاباں منارہ سے روشنی لے کر اپنے مَن میں اُجالے کیے۔ انھیں دیکھا‘ سنا تو ہر حرف‘ ہر لمحہ اور ہر جنبش کو اسوۂ عمل بنا لیا۔ لمحوں میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اونٹوں کے چرانے والے دنیا میں تہذیب و تمدن کی شمعیں روشن کرنے لگے۔ بات بات پر تلوار نکالنے ‘ خون کے دریا بہانے اور صدیوں کی دشمنیاں پالنے والے‘ اب سمعنا واطعنا--- ہم نے سنا اور مان لیا کا اعلان کرنے لگے۔ اپنے حسب ونسب پر فخر و غرور کرنے‘ شان و شوکت پر اِترانے والے اُس ذاتِ والاتبار پر فداہ ابی وامی--- اپنے ماں باپ قربان کرنے لگے۔ پتھروں کی طرح سخت دل خوفِ الٰہی سے معمور ہوگئے۔ اپنی خاطر مٹنے والے دوسروں کے لیے قربانی و ایثار کے خوگر ہوگئے۔ کفرونفاق کی جگہ صدق و صفا‘ خلوص و وفا نے لے لی۔ حرص وہوس کے بجائے فقروغنا‘ خونریزی اور سفاکی کے بجائے اخوت و محبت کا چلن ہوا۔ دنیا کی راحتوں پر مر مٹنے والے آخرت کی نعمتوںکے متمنی اور مشتاق ہوگئے۔
یقینا یہ معجزہ ہی تھا--- ایک تاابد زندۂ و جاوید رہنے والا معجزہ--- کہ بیک نظر‘ بیک لمحہ اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا کہ چند ہی سالوں میں حجۃ الوداع تک ایک لاکھ ۲۴ ہزار سے بھی زائد ایسے پاکیزہ نفوس کی جماعت وجود میں آگئی جن میں سے ہر ایک کی حیات--- ہر ایک کا کردار--- سرکارِ دوجہاں کی حیاتِ مقدسہ کا عکس تھا۔ اعلیٰ اخلاق‘ عفت و پاک بازی‘ حق گوئی و بے باکی‘ دیانت و امانت --- عدل و انصاف‘ گفتار و کردار‘ توکل و استغنا‘ شجاعت و استقامت‘ قربانی و ایثار‘ جاں فروشی و جانثاری کے روشن ستارے دشت وچمن میں سحر کرنے لگے۔ روشنی و ہدایت کے یہ ستارے قیامت تک آنے والوں کے راہنما و راہبر قرار پائے۔ انھی کے بارے میں تو آنحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: أصْحَابی کالنُّجومُ‘ میرے صحابہؓ ستاروں کی مانند ہیں--- بِأیِّھِمُ اقْتَدَیْتُمْ اِھْتَدَیْتُمْ‘ ان میں سے جسے بھی تم پیشوا بنا لو‘ ہدایت پالوگے۔ اپنے صحابہؓ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو تنبیہہ کی: اللّٰہ اللّٰہ فِی اَصْحَابِی‘ میرے اصحاب کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لاَ تَتَّخِذُوْھُمْ مِنْم بَعْدِیْ غَرَضًا ‘ میرے بعد اُنھیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ اور آپؐ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے محبت کا معیار میرے صحابہؓ سے بھی محبت ہے۔ ان سے نفرت و بُغض مجھ سے نفرت و بُغض ہے۔ انھیں ایذا دینا مجھے ایذا دینے کے مصداق ہے‘ اور مجھے ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا ہے۔
یہ پاکیزہ نفوس اور مقدس ہستیاں وہ ہیں جنھیں قرآنِ حکیم نے بڑی عظمت و مرتبت سے نوازا ہے۔ نہ صرف قرآن میں بلکہ ان کا ذکر اپنے آقا و مولا کے ساتھ تورات و انجیل میں بھی بیان ہوا ہے۔ مَثَلُھُمْ فِی التَّوْرٰۃِ وَالْاِنْجِیْلِ۔
قرآنِ مجید میں اصحاب نبیؐ کی عظمت و بلند مرتبت کا جابجا ذکر موجود ہے۔ سورئہ فاطر میں اللہ نے انھیں اپنے منتخب بندے اور کتاب کے وارث قرار دے کر خصوصی سلام بھیجا: وَسَلاَمٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی--- اور فرمایا: اَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِیْنَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا--- دراصل یہ وہ لوگ تھے جنھوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دعوتِ حق سنی تو فوراً اُسے قبول کیا اور اس کی خاطر ہر طرح کا ستم اور ظلم سہا۔
قرآن نے خود ان صحابہؓ کا قول بیان کیا: رَبَّنَا ٓاِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُّنادِیْ لِلاِْیْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّکُمْ فَاٰمَنَّا (آل عمران ۳:۱۹۳) ۔اللہ کریم نے ان کے لیے اپنے فضل اور رضا کا اعلان کیا جنھوں نے راہِ حق میں اپنے گھر اور مال لٹا دیے--- لِلْفُقَرَآئِ الْمُھَاجِرِیْنَ الَّذِیْنَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ وَاَمْوَالِھِمْ یَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰہِ ورِضْوَاناً (الحشر ۵۹:۸)۔ قرآن نے انھیں دین حق کی راہ پر ’’السابقون الاولون‘‘ قرار دیا اور فرمایا: رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُمْ ورَضُوْا عَنْہُ --- کہ اللہ بھی اُن سے راضی ہوا اور یہ بھی اپنے مالک و آقا کی نعمتوں اور عنایات پر راضی ہو گئے۔ اور ان کے لیے جنت کا انعام اور وہاں ہمیشہ قیام کا وعدہ فرمایا۔ اور اسے ’’اَلْفَوْزُالْعَظِیْمُ‘‘ یعنی بڑی کامیابی قرار دیا (توبہ ۹: ۱۰۰)۔ قرآن مجید نے ان صحابہؓ کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا: رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاھَدُوا اللّٰہَ عَلَیْہِ (الاحزاب ۳۳:۲۳)’’یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا‘‘۔
قرآن نے انھیں خیر اُمت اور اُمت وسط قرار دے کر نیکی پھیلانے اور بدی کی بیخ کنی کا منصب سونپا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز‘ جب لوگ رسوائی کے خوف سے پریشان ہوں گے‘ اللہ انھیں رسوائی سے بچائے گا۔ یَوْمَ لَا یُخْزِی اللّٰہُ النَّبِیَّ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَہٗ ج (التحریم ۶۶:۸)
قرآن کریم نے ان اصحاب نبی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبہ کے علاوہ ان کی صفات بھی بیان فرمائیں۔ جن کی وجہ سے انھیں نبی کی قربت اور اپنے مالک و آقا کی رضا و مغفرت اور اجرِعظیم‘ رزقِ کریم اور فوزِ عظیم کی بشارتیں عطا ہوئیں۔ قرآن نے انھیں اُولٰٓئِکَ ھُمُ الْمُؤمِنُوْنَ--- حقیقی مومن --- الصادقون--- سچے لوگ--- الراشدون --- ہدایت یافتہ --- المفلحون --- فلاح یافتہ --- الفائزون--- کامیاب قرار دیا۔ اس لیے کہ انھوں نے ایمان کو اپنے دلوں میں جگہ دی۔ کفر‘ فسق اور آقا کی نافرمانی سے قولی و عملی کنارہ کشی اختیار کی۔ یہ لوگ گناہِ کبیرہ-- الفواحش--- یعنی فحش باتوں اور برے اعمال سے اجتناب کرتے رہے اور جب غصہ میں ہوتے تو معاف کر دیتے۔ وَاِذَا مَا غَضِبُوْاھُمْ یَغْفِرُوْنَ (الشوریٰ ۴۲:۳۷)--- یہ لوگ اپنی خواہشات اور ضروریاتِ کو قربان کر کے اپنے ساتھیوں کی ضروریات کو ترجیح دینے والے تھے۔ یُؤثِرُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِھِمْ وَلَوْ کَانَ بِھِمْ خَصَاصَۃٌط (الحشر۵۹:۹)۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی قرآن کی نظر میں رُحْمَآئُ بَیْنَھُمْ --- حلقۂ یاراں میں بریشم کی طرح نرم‘ اور اَشِدَّآئُ عَلَی الْکُفّارِ--- رزمِ حق و باطل میں فولاد--- یعنی دشمن کے لیے سخت اور دوست کے لیے نرم۔ شب و روز اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز‘ رُکَّعًا سُجَّدًا--- ایک اور جگہ یوں بیان فرمایا: یَبِیْتُوْنَ لِرَبِّھِمْ سُجَّدًا وَّقِیَامًا ---کہ یہ لوگ اپنی راتیں قیام و سجود میں گزارتے ہیں اور ہر دم یَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰہِ ورِضْوَاناً --- اپنے پروردگار کی رضا اور فضل کے طلب گار رہتے ہیں۔
سورئہ السجدہ میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا کہ تَتَجَا فٰی جُنُوبُھْمْ عَنِ المَضَاجِعِ یَدْعُوْنَ رَبَّھُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا --- کہ اپنے رب کے خوف اور مغفرت کی امید میں ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ ان کی ایک صفت وَمِمَّا رَزَقْنٰھُمْ یُنْفِقُوْنَ--- کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں‘ بھی بیان کی گئی۔قرآن نے ہدایت کے ان میناروں کی کچھ اور صفات بیان کیں۔ ’’یَمْشُوْنَ عَلَی الْاَرْضِ ھَوْنًا--- یہ زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں‘ یعنی فخروتکبر سے پاک چال--- اور اِذَا ٓ اَنْفَقُوْا لَمْ یُسْرِفُوْا وَلَمْ یَقْتُرُوْا--- جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی اور اِسراف نہیں کرتے اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں۔
اصحاب نبیؐ اپنے رب پر ایمان لائے‘ اپنے آقا و مولا پر فدا و نثار ہوئے‘ اُن کے فرمان پر سرتسلیم خم کیا اور اُن کے ہر قول و عمل کے مطابق اپنی ساری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اپنے مولا کے حکم پر جان و مال سے جہاد کیا اور راہِ خدا میں ہجرت بھی کی۔ یہ وہ لوگ تھے--- اَلَّذِیْنَ اِذَا ذُکِرَ اللّٰہُ وَجِلَتْ قُلُوْبُھُمْ (انفال ۸:۲)‘ جب اللہ کا ذکر ہوتا تو اُن کے دل خوف زدہ ہو جاتے۔ وَاِذا تُلِیَتْ عَلَیْھِمْ اٰیٰتُہٗ زَادَتْھُمْ اِیْمَانًا (۸:۲۰)‘ اور جب اُن کے سامنے رب کی آیات تلاوت کی جاتیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے--- کہ اپنے آقا و مولا کے فرمان کو نہیں ٹالا‘ نہ لیت و لعل سے کام لیا۔ نہ سوچ بچار میں پڑے اور نہ کسی مصلحت کا شکار ہوئے۔ جونہی اللہ اور رسولؐ کا حکم پہنچا‘ رضا معلوم ہوئی‘ اپنا سب کچھ مطیع بنا دیا۔
اِن صحابہؓ کی حیاتِ طیبہ کے یہ نقوش قرآن عظیم کے صفحات پر تاابد روشن رہیں گے‘ اور قیامت تک انسانیت کے لیے راہنما اور ہدایت کا مرکز و منبع رہیں گے۔ اُمت مسلمہ آج بھی اور ہر دور میں انھی سے ایمان کا نور حاصل کرتی رہے گی۔ مگر محض تذکروں--- یادوں اور باتوں سے نہیں--- اسی طرزِحیات ‘ اِسی اسوئہ عمل کو اپنا کر --- انھی مقدس ہستیوں کے نقشِ قدم پر چل کر --- !
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!
اﷲ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کی ایک مٹھی اور روح کی ایک پھونک سے پیدا فرمایا۔ مٹی کے جزو کے لیے کھانا پینا آسان کر دیا جس سے جسم نشوونما پاتا ہے اور بدن میں قوت آتی ہے‘لیکن جہاں تک روح کا تعلق ہے وہ ایک بڑا راز ہے جس کی حقیقت کو انسان نہیں سمجھ پاتا۔
روح کی غذا‘ قوت‘ زندگی اور اس کی حفاظت اس کے خالق اور موجد کے مقرر کردہ طریق کار سے ہی ممکن ہے: اَلاَ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَط وَھُوَ الَّلطِیْفُ الْخَبِیْرُ (الملک ۶۷:۱۴) ’’کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے‘‘۔ اﷲ تعالیٰ نے روح کے لیے وہ چیز بنائی ہے جس سے اسے بلندی‘ ارتقا‘ لطافت اور سرور حاصل ہو۔
]’’ذکر‘‘ کا لفظ قرآن میں اصطلاحاً کلامِ الٰہی کے لیے استعمال ہوا ہے جو سراسر نصیحت بن کے آتا ہے۔ پہلے جتنی کتابیں انبیا پر نازل ہوئی تھیں وہ سب بھی ’’ذکر‘‘ تھیں اور یہ قرآن بھی ’’ذکر‘‘ ہے۔ ذکر کے اصل معنی ہیں ’’یاد دلانا‘‘، ’’ہوشیار کرنا‘‘، اور ’’نصیحت کرنا‘‘۔ (تفہیم القرآن‘ ج ۲‘ ص ۴۹۸)[
’’روح کو جس چیز سے سب سے زیادہ توانائی اور راحت حاصل ہوتی ہے وہ اس کے خالق کا ذکر ہے۔اسی سے وہ غذا پاتی ہے اور وہی اس کی معراج اور زینت ہے۔ وہی اس کا ہتھیار ہے جس سے وہ تقویت پاتی ہے۔یہ وہ پروانۂ ولایت ہے کہ جسے دیا گیا وہ منزل پر پہنچا اور جس سے روک لیا گیا وہ محروم رہا۔ یہ لوگوں کے دلوں کی خوراک ہے کہ جب وہ نہیں ملتی تو ان کے جسم قبریں بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ان کے گھروں کی آبادی ہے کہ جب وہ اس سے خالی ہو گئے تو وہ برباد ہو گئے۔ یہ وہ اسلحہ ہے جس کے ساتھ وہ رہزنوں سے لڑتے ہیں۔یہ وہ پانی ہے جس سے وہ آگ کے شعلے بجھاتے ہیں اور یہ بیماریوں کی وہ دوا ہے کہ جب نہیں ملتی تو ان کے دل بیمار پڑجاتے ہیں۔ یہ قرب کا وہ وسیلہ ہے جو انھیں علام الغیوب تک پہنچاتا ہے۔ اسی کے ذریعے وہ آفات سے اپنا دفاع کرتے ہیں‘ اسی سے تکالیف دور ہٹاتے ہیں اوراسی کے باعث مصیبتیں ان پر آسان ہوجاتی ہیں ۔ جب ان پر کوئی آزمایش آتی ہے تو وہی ان کی پناہ گاہ ہے۔جب بلائیں ان پر نازل ہوتی ہیں تو وہی ان کو بچاتا ہے۔ وہی ان کے جنت کے باغات ہیں جن میں وہ چلتے پھرتے ہیںاور ان کی خوش بختی کا راس المال بھی وہی ہے جس سے وہ تجارت کرتے ہیں۔وہ افسردہ دل کو مسرت سے ہم کنار کر دیتا ہے۔ وہ ذاکر کو مذکور سے ملاتا ہے اور اسے ذاکر و مذکور بنا دیتا ہے‘‘ (تہذیب المدارج‘ ص ۴۶۳) --- کتنی عمدہ ہے ذکر کی یہ تعریف جو ابن القیمؒ نے کی ہے۔ وہ کتنے بڑے صاحب فہم ہیں۔ ان معانی پر غور تو کرو!
اﷲ تعالیٰ کا فرمان ہے: یٰٓاَیُّھَاالَّذِیْنَ اٰمَنُوا اذْکُرُوا اللّٰہَ ذِکْرًا کَثِیْرًا (الاحزاب ۳۳: ۴۱ ) ’’اے لوگو!جو ایمان لائے ہو‘ اﷲ کو کثرت سے یاد کرو‘‘۔ اور اس کے لیے وقت کی کوئی تخصیص نہیں۔ اﷲ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمِنْ آنَائِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّھَارِ لَعَلَّکَ تَرْضٰی (طٰہٰ ۲۰: ۱۳۰) ’’اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی‘ شاید کہ تم راضی ہو جاؤ‘‘۔اور کوئی حالت بھی ذکر سے مستثنیٰ نہیں‘ فرمایا: اَلَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ قِیٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰی جُنُوْبِھِمْ (آل عمران ۳:۱۹۱) ’’وہ ہوش مند لوگ جو اٹھتے ‘بیٹھتے اور لیٹتے ‘ ہر حال میں اﷲ کو یاد کرتے ہیں‘‘۔
ذکر غفلت اور نسیان کی ضد ہے۔ غفلت ذکر کو عمداً ترک کر دینا اور نسیان غیر ارادی طور پر ذکر کا ترک ہوجانا ہے۔ قرآن کریم میں غفلت کا حوالہ اس سے ممانعت اور اس سے پرہیزکے ضمن میں دیا گیا ہے۔ وَاذْکُرْ رَبَّکَ فِیْ نَفْسِکَ تَضَرُّعًا وَّ خِیْفَۃً وَّ دُوْنَ الْجَھْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَ لاَ تَکُنْ مِّنَ الْغَافِلِیْنَ(الاعراف ۷:۲۰۵) ’’ا پنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو‘دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ ‘اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں‘‘۔ نیز اﷲ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلاَ تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَہٗ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ ھَوَاہُ وَ کَانَ اَمْرُہٗ فُرُطًا (الکہف ۱۸:۲۸) ’’کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہشِ نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریق کار افراط و تفریط پر مبنی ہے‘‘۔ نسیان اس طرح کا نہیں ہوتا کیوں کہ اس کا صدور ارادے سے نہیں ہوتا اور اس سے متعلق قرآن عظیم نے وضاحت کی ہے: وَاذْکُرْ رَّبَّکَ اِذَا نَسِیْتَ (الکہف ۱۸:۲۴) ’’اوراگر بھول ہو جائے تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید اور اس سے استغفار کرو‘‘۔
قلبی ذکر : تذکر کے معنی کسی شے کا ذہن میں اس طرح استحضار ہے جیسا کہ تمھارا یہ کہنا’’ مجھے ایک ایسا اور ایسا حادثہ یا د آتا ہے ‘‘جب کہ تم نے اس حادثے کو اپنے ذہن میں حاضر کر لیا اور اس کی تفصیلات ذہن کے پردے پر آگئیں۔ یہ معنی ہیں نسیان کی ضد کے۔اور اسی سے متعلق اﷲ تعالیٰ کا قول ہے: وَالَّذِیْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَۃً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَھُمْ ذَکَرُوا اللّٰہَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِھِمْ (آل عمران ۳:۱۳۵) ’’ایسے نیک لوگ جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اﷲ انہیں یا د آجاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں‘‘۔پس ذکر کی بنیاد دل میں مذکورہ شے کی یاد اور توجہ ہے۔
قولی ذکر: اس سے مراد زبان سے الفاظ کی ادایگی ہے اور اسی مفہوم میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا جب یہ کہا جائے کہ:’’ فلاں صاحب پابندی سے اذکار کرتے ہیں‘‘ تو مفہوم یہی ہوتا ہے کہ وہ الفاظ سے انھیں ادا کرتے ہیں۔ اﷲ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یٰٓاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اذْکُرُوا اللّٰہَ ذِکْرًا کَثِیْرًا (الاحزاب۳۳:۴۱) ’’اے لوگو‘ جو ایمان لائے ہو اﷲ کو کثرت سے یاد کرو‘‘۔
زبان سے قول کو ذکر کا نام دیا گیا ہے۔ کیوں کہ وہ دل کے ذکر پر دلیل ہے۔ اور زیادہ تر زبانی قول کو ذکر کا نام دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ شعوری طور پر وہی ذہن میں آتاہے۔ (المفہم‘۶-۷)
لہٰذا ہمارے نزدیک ذکر دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ذکر تذکر کے معنی میں‘ جس سے مقصود اﷲ کی یاد‘ اس کی عظمت و خشیت‘ اس کی حفاظت و نگرانی‘ اس کی نعمت کااحساس ‘ حتیٰ کہ بندے کے دل میں اس کی بڑائی سما جائے۔ وہ اﷲ سے ڈرے اور سمجھے کہ وہ اس کی نظر میں ہے اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح سے زبان سے ذکر ہے جو قلبی ذکر کا ثمرہ ہے‘ اس پرگواہ ہے اور اس کی ترجمانی کرنے والا ہے۔ پس جس نے اﷲ کی عظمت کو دل میں جگہ دی‘ اپنی زبان سے اﷲ کی تسبیح ‘ تہلیل اور تکبیر کی‘ اس کے حضور میں گریہ وزاری اور دعا کی‘ وہی صحیح معنوں میں ذاکر ہے۔
]اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام آتا رہے۔ یہ کیفیت آدمی پر اُس وقت تک طاری نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں خدا کا خیال بس کر نہ رہ گیا ہو۔ انسان کے شعور سے گزر کر اس کے تحت الشعور اور لاشعور تک میں جب یہ خیال گہرا اُتر جاتا ہے تب ہی اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو کام اور جو بات بھی وہ کرے گا اس میں خدا کا نام ضرور آئے گا۔ کھائے گا تو بسم اللہ کہہ کر کھائے گا۔ فارغ ہوگا تو الحمدللہ کہے گا۔ سوئے گا تو اللہ کو یاد کرکے اور اُٹھے گا تو اللہ ہی کا نام لیتے ہوئے۔ بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم اللہ‘ الحمدللہ‘ ان شاء اللہ‘ ماشاء اللہ اور اس طرح کے دوسرے کلمات نکلتے رہیں گے۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے گا۔ ہر نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرے گا۔ ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلب گار ہو گا۔ ہرمشکل میں اس سے رجوع کرے گا۔ ہر برائی کا موقع سامنے آنے پر اس سے ڈرے گا۔ ہر قصور سرزد ہوجانے پر اس سے معافی چاہے گا۔ ہر حاجت پیش آنے پر اس سے دعا مانگے گا۔ غرض اٹھتے بیٹھتے اور دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہوئے اس کا وظیفہ خدا ہی کا ذکر ہو گا۔ یہ چیز درحقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے۔ دوسری جتنی عبادات ہیں ان کے لیے بہرحال کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ ادا کی جاتی ہیں اور انھیں ادا کر چکنے کے بعد آدمی فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ عبادت ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے اور یہی انسان کی زندگی کا مستقل رشتہ اللہ اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے خود عبادات اور تمام دینی کاموں میں بھی جان اسی چیز سے پڑتی ہے کہ آدمی کادل محض ان خاص اعمال کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت خدا کی طرف راغب اور اس کی زبان دائماً اس کے ذکر سے تررہے۔ یہ حالت انسان کی ہوتو اس کی زندگی میں عبادات اور دینی کام ٹھیک اسی طرح پروان چڑھتے اور نشو و نما پاتے ہیں جس طرح ایک پودا ٹھیک اپنے مزاج کے مطابق آب و ہوا میں لگا ہوا ہو۔ اس کے برعکس جو زندگی اس دائمی ذکر خدا سے خالی ہو اس میں محض مخصوص اوقات میں یا مخصوص مواقع پرا دا کی جانے والی عبادات اور دینی خدمات کی مثال اس پودے کی سی ہے جو اپنے مزاج سے مختلف آب و ہوا میں لگایا گیا ہوا اور محض باغبان کی خاص خبر گیری کی وجہ سے چل رہا ہو۔ (تفہیم القرآن‘ ج ۴‘ ص ۹۶-۹۷)[
ذکر اکبر: اﷲ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اﷲ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْکَ مِنَ الْکِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَط اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَآئِ وَالْمُنْکَرِط وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اَکْبَرُ ط وَاﷲ ُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ (العنکبوت ۲۹:۴۵) ’’اے نبیؐ، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمھاری طرف وحی کے ذریعہ سے بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کرو۔ یقینا نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اﷲ کا ذکر اس سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ اﷲ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو‘‘۔یہ آیت کریمہ واضح دلیل ہے اس پر کہ اﷲ کا ذکر فقط کبیر نہیں ہے بلکہ اکبر ہے اور یہی اس کی اہمیت اور عظیم مرتبے کی دلیل ہے۔
علما ومفسرین نے ذکر کے کئی واضح اور آسان معانی بیان کیے ہیں جو قابلِ توجہ ہیں اور ذکر اکبر کی وضاحت کرتے ہیں۔
اول: اﷲ کا ذکر ہر چیز سے بڑا اور افضل عبادت ہے کیوں کہ جملہ طاعات کا مقصود اﷲ کے ذکر کا قیام ہے ۔ وہ عبادات کا راز اور ان کی روح ہے۔ اس لیے کہ اس کی حقیقت اﷲ سے تعلق ‘اس کی عظمت کا استحضار ‘اس کی نگرانی کا شعور اور اس کے انعامات کی یاد ہے۔ لہٰذا عبادات سب کی سب ذکر ہیں۔
دوم: جب تم اﷲ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو تو وہ تمھارا ذکر کرتا ہے۔ اس کا تمھارے لیے ذکر ‘ اس کے لیے تمھارے ذکر سے بہت بڑا ہے‘ اوریہ عظیم بات ہے۔ اے ضعیف اور عاجز انسان! تو قوی اور قادر مطلق اﷲ کا ذکر کرتا ہے ‘ تو فقیر اور حقیر انسان غنی اور عظیم اﷲ کا ذکر کرتا ہے۔تیرے ذکر کے مقابلے میں اس کا ذکر کتنا عظیم اور کتنا بلند ہے!
سوم: اﷲ کا ذکر اس سے بلند و برتر ہے کہ اس کے ساتھ فحش اور منکر باقی رہے بلکہ جب ذکر مکمل ہوتا ہے تو خطا اور معصیت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ بخدا! ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ (تہذیب المدارج‘ ص ۴۶۳)
اجرعظیم: اگرچہ ذکر بذات خود بہت بڑی چیز ہے مگرا س کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ حضرت ابوالدرداء ؓ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اﷲعلیہ وسلم نے فرمایا : کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں جو تمھارے سارے اعمال میں بہتر اور تمھارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے۔وہ تمھاری روحوں کودوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور راہِ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیرہے‘ اور تمھارے لیے اس میں جہاد سے بھی زیادہ خیر ہے جس میں تم خدا کے دشمنوں کی گردنیں مارو اور وہ تمھاری گردنیں ماریں؟صحابہؓ نے عرض کیا : کیوں نہیں‘ یارسولؐ اﷲ! فرمائیے۔آپؐ نے فرمایا:وہ اﷲ عزوجل کا ذکر ہے۔ (مسند احمد‘ جامع ترمذی‘ ابن ماجہ)
اﷲ اکبر! کتنا بڑا درجہ ہے۔ وہ اﷲ کی راہ میں مال کے خرچ کرنے اوراس کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی بڑا ہے۔غور کرو کہ کس طرح سے نبی ؐ نے یہ بات فرمائی جو اس اجر کی عظمت کا اظہار کرتی اور اس کا شوق دلاتی ہے۔ آنحضورؐنے اس سوال سے ابتدا کی جو جاذب قلب ونظر ہے‘ اور سوال کا مضمون ایسا ترتیب دیا کہ جس سے اہل ایمان میں بے قراری‘ ان کے دلوں میں ولولہ اورجذبات میں تلاطم پیدا ہوا۔ وہ اسے جاننے کے لیے بے تاب ‘ اس پر لبیک کہنے کے مشتاق اور عملی اقدام کے لیے کمربستہ ہو گئے۔ یہ ذکر کی اہمیت ‘ اس کی بلند منزلت اور اس کے اظہار اور معانی کے واضح ابلاغ کا طریقہ تھا جو آنحضورؐ نے اختیار فرمایا۔
عبادات سے تعلق: ذکر طاعات کا نچوڑ اور عبادات کاجوہر ہے اور اکثر ظاہری فرائض اور شعائر کی بنیاد ہے۔ عبادات کی ادایگی سے قبل ان کے لیے تیاری ہوتی ہے اور ذکر ان کے اعمال اور ارکان کے ساتھ ان کے جزو کے طور پر ہوتا ہے اور عبادات سے فراغت پر اسی کے ساتھ ان کا اختتام ہوتا ہے۔
ہم نماز ہی کی مثال لیتے ہیں۔ ذکر نماز سے پہلے آتا ہے۔ اذان ذکر ہے جو تکبیر‘ تہلیل اور شہادتین کے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے اور مؤذن کی متابعت سنت ہے۔ نبی ؐنے فرمایا :اذان سے فراغت کے بعد جس نے کہا: اَللّٰھُمَّ رَبَّ ھٰذِہِ الدَّعْوَۃِ التَّامَّۃِ وَالصَّلاَۃِ الْقَائِمَۃِ اٰتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِیْلَۃَ وَالْفَضِیْلَۃَ وَابْعَثْہُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا نِ الَّذِیْ وَعَدْتَّہٗٓ(اے اﷲ اس دعوت تامہ ‘ کاملہ اور اس صلوٰۃ قائمہ کے رب ! محمد(ﷺ) کووسیلہ اور فضیلت کا خاص مرتبہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے) تووہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حق دار ہوگا (بخاری)۔ نماز سے قبل وضو ‘ شرائط نماز میں سے ہے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد بھی ذکر ہے‘ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب ؓ سے روایت کردہ حدیث میں ہے کہ نبی ؐ نے فرمایا: ’’ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کامل وضو کیا‘ پھر کہا: اَشْھَدُ اَنْ لاَّ اِلٰہَ اِلاَّ اللّٰہُ وَحْدَہٗ لاَ شَرِیْکَ لَہ‘ وَاَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ مگر یہ کہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل گئے‘ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے ‘‘ (مسلم)۔ اور ترمذی نے اَللّٰھُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَھِّرِیْنَ کا اضافہ کیا ہے۔
نص قرآنی کی رو سے نماز کا مقصود ذکر ہے۔ وَاَقِمِ الصَّلاَۃَ لِذِکْرِیْ(طٰہٰ ۲۰:۱۴) ’’اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر‘‘۔ اس کا رکن اول ‘تکبیر تحریمہ ذکر ہے اور اس کا رکن اعظم فاتحہ کی قرأت ذکرہے۔ اور اس کے رکوع میں اﷲ کے عظیم نام کی تسبیح ہے اوراس کے سجدے میں اس کے اسم اعلٰی کی تسبیح ہے اور رکوع سے اٹھنے پر حمد ہے اور ذکر ہے۔ اس کے دو سجدوں کے درمیان استغفار ہے اور ذکر ہے‘اور نماز کی ادایگی کے بعد ذکر کی ہدایت کی گئی ہے۔ فَاِذَا قَضَیْتُمُ الصَّلٰوۃَ فَاذْکُرُوا اللّٰہَ قَیَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰی جُنُوْبِکُمْ (النساء ۴: ۱۰۳) ’’ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ‘ ہر حال میں اﷲ کو یاد کرتے رہو‘‘۔ نبی ؐ السلام علیکم کہنے کے بعد تین مرتبہ استغفر اﷲ کہتے جیسا کہ حضرت ثعبان ؓسے روایت ہے کہ نبی ؐ جب نماز سے سلام پھیرتے تو تین مرتبہ استغفار کی دعا کرتے اور کہتے: اَللّٰھُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْکَ السَّلاَمُ تَبَارَکْتَ یَاذَالْجَلاَلِ وَاْلاِکْرَامِ (مسلم)۔ اور نمازوں کے بعد بہت سے اذکار مسنونہ کی روایت ہے۔ چنانچہ نماز ساری کی ساری ثنا ہے‘ خشوع و خضوع ہے اور دعا ہے۔
دوسری مثال حج کی ہے۔ اﷲ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ ط فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰہَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ص وَاذْکُرُوْہُ کَمَا ھَدَاکُمْ (البقرہ ۲ :۱۹۸) ’’اور حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ‘ تواس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو‘ تو مشعرحرام (مزدلفہ) کے پاس ٹھہر کر اﷲ کو یاد کرو اور اسی طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمھیں کی ہے‘‘۔ حج کا آغاز ذکرہی سے ہوتا ہے۔ احرام کی ابتدا تلبیہ سے ہوتی ہے اور یہ وہ ذکر ہے جس کے ساتھ آوازیں رب سموات وارض کی توحید اور اس کے حضور حاضری کے اعلان کے ساتھ بلند ہوتی ہیں۔طواف اور سعی ذکر ہے ‘اور تکبیر ہے اور تہلیل ‘ جیسا کہ نبی ؐنے فرمایا: ’’بیت اﷲ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی اور رمی جمار اﷲ کے ذکر کے لیے مقرر کیے گئے ہیں‘‘۔ عرفات کا وقوف پورے کا پورا اذکار اور دعائیں ہیں اور اس بار ے میں رسول اﷲ صلی اﷲعلیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کلمہ وہ ہے جو میں کہتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیا علیہم السلام نے کہا: لا الٰہ الا اﷲ۔ اور حج کے اختتام پر ذکر کی نصیحت ہے: فَاِذَا قَضَیْتُمْ مَّنَاسِکَکُمْ فَاذْکُرُوا اللّٰہَ کَذِکْرِکُمْ آبَآئَ کُمْ اَوْاَشَدَّ ذِکْرًا (البقرہ ۲: ۲۰۰) ’’ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو ‘ تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے‘ اس طرح اب اﷲ کا ذکر کرو‘ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر‘‘۔ حتیٰ کہ جہاد میں صف بندی‘ تلواروں کے ٹکرانے اور اس میں موت کے وقت بھی ذکر کی ہدایت ہے: یٰٓاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِیْتُمْ فِئَۃً فَاثْبُتُوْا وَاذْکرُوُا اللّٰہَ کَثِیْرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ (الانفال۸ :۴۵) ’’اے لوگو‘ جو ایمان لائے ہو ‘ جب کسی گروہ سے تمھارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اﷲ کو کثرت سے یا دکرو‘ توقع ہے کہ تمھیں کامیابی نصیب ہوگی‘‘۔
اہل ذکر‘ سبقت لے جانے والے: ذکر بہت بڑی چیز ہے ‘ اس کا اجربہت بڑا ہے اور اہل ذکر سبقت لے جانے والے ہیں۔جیسا کہ رسولؐ اﷲ نے فرمایا: مفردون سبقت لے گئے۔ عرض کیا گیا کہ اے اﷲ کے رسولؐ!مفردون کون ہیں؟ فرمایا: بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں۔ (مسلم)
مفردین کے معنی میں ابن قتیبہ نے کہا ہے : وہ لوگ جن کی نسل ہلاک ہو گئی اور وہ تنہا رہ گئے اور اﷲ کا ذکر کرتے ہوئے باقی رہے۔ اور ابن اعرابی نے کہا: وہ آدمی جس نے غوروفکر کیا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکرکے فریضہ کی ادایگی میں یکسو ہو گیا۔ اور ازہری نے کہا: وہ جو اﷲ کا ذکر کرتے ہوئے پیچھے رہ گئے ہیں(مسلم‘ بشرح النووی)۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اس اہم صفت کے باعث جس نے ان کو سبقت لے جانے والے بنا دیا دوسروں سے ممتاز اور منفرد ہیںاور وہ صفت کثرتِ ذکر ہے۔
اہل ذکر کا بلند مرتبہ : اہل ذکر فقط نوع بشر کے ہی سابقین نہیں بلکہ وہ بزرگ فرشتوں کے‘ جو کبھی اﷲ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انھیں دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں ‘ مشابہ اور ان کے ہاں فخرو مباہات کے مقام پر فائز ہیں۔ وہ فرشتے جو فرماں برداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ‘ جن کی تخلیق عبادت پر ہے اور جو دن رات بغیر توقف کے اﷲ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کیوں کہ ان کی پیدایش کی اصل اور ان کے وجود کی غایت ہی ذکر اور عبادت ہے۔ اور اس سب کچھ کے باوجود مومن اہل ذکر وہ بلند منزلت رکھتے ہیںکہ اﷲ تعالیٰ اہل ذکر کا فرشتوں سے فخرکے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ (تہذیب المدارج‘ ص۴۶۶)
اس دلیل کی وضاحت حضرت معاویہ ؓ کی روایت سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اﷲعلیہ وسلم اپنے اصحاب کے حلقہ میں تشریف لائے اور استفسار فرمایا:کس چیزنے تمھیں یہاں بٹھایا ہے؟ انھوں نے جواب دیا:’’ہم اﷲ کا ذکر اور اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور اس کے ساتھ ہم پر احسان فرمایا۔ آنحضور ؐ نے فرمایا:تمھیں اﷲ کی قسم!کیا صرف اسی چیز نے تمھیں بٹھایا ہے ؟ انھوں نے عرض کیا: بخدا! ہمیں صرف اسی چیزنے بٹھایا ہے۔ آپؐ نے فرمایا:’’خدا کی قسم! میں نے تم سے حلف تمھارے اوپر کسی بدگمانی کے باعث نہیں لیا بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انھوں نے مجھے بتایا ہے کہ اﷲ تعالیٰ فرشتوںکے سامنے تمھارے اوپر فخرفرما رہا ہے‘‘۔ (النہایہ‘ ۱۶۹؍۱)
فرشتے مجالسِ ذکر تلاش کرتے ہیں‘ وہاں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ان کی طرف بلاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابوہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ رسول اﷲ صلی اﷲعلیہ وسلم نے فرمایا : بے شک اﷲ تعالیٰ کے معزز فرشتے جو مجالس ذکر کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں ‘ جو نہی وہ کسی مجلس کو پالیتے ہیں جس میں ذکر ہورہا ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں‘ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں حتیٰ کہ زمین اور آسمان دنیا کے مابین کو بھر دیتے ہیں(مسلم)۔ مشہور حدیث ہے :’’جب اﷲ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ کتاب اﷲ کو پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے ‘رحمت انھیں ڈھانک لیتی ہے ‘ فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اﷲ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں سے فرماتے ہیں‘‘(مسلم) ۔اور سب سے بڑی بات تو وہ ہے جو اﷲ تعالیٰ نے فرمائی: فَاذْکُرُونِیْٓ اَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوْا لِیْ وَلاَ تَکْفُرُوْنِ(البقرہ ۲:۱۵۲) ’’تم مجھے یاد رکھو‘ میں تمھیں یا د رکھو ںگا اور میرا شکر کرو‘ کفران نعمت نہ کرو‘‘۔کون سا شرف اور کون سا فخر اس سے برتر ہے کہ اﷲ رب العالمین انھیں یاد فرماتا ہے۔حدیث قدسی ہے : ’’میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں‘ جب وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میںاسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ میرا ذکرمجمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع (فرشتوں) میں کرتا ہوں‘‘۔
ذکر کے فوائد و ثمرات
اجر و ثواب کا آسان نسخہ
مسلمان ثواب کے حصول کا حریص اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا طلب گار ہے۔طاعات میں کوشاں رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مصروفیات کی کثرت‘ مشکلات‘دل کش بہکاووں اور تفریح گاہوں کے ہوتے ہوئے بھی فکرمند رہتے ہوکہ اپنی نیکیوں کے کھاتے میں اضافہ کرو۔ آئو میں تمھیں بتاتا ہوں کہ ذکر اجر کے بہت بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ میں تمھیں ذکر کے بڑے اجر وثواب کا انکشاف کرنے والی نصوص کا چھوٹا سا مجموعہ پیش کروں گا جو سمندر میں سے ایک قطرے کے مصداق ہے ۔
(الف) حضرت ابوہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ رسولؐ اﷲ نے فرمایا:’’ جس نے ہر فرض نما زکے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اﷲ ‘ ۳۳ مرتبہ الحمد للّٰہ اور ۳۳ مرتبہ اﷲ اکبر کہا اور یہ ۹۹ ہوئے اور ۱۰۰ پورا کرنے کے لیے لا اِلٰہ الا اﷲ وحدہ لا شریک لہ‘ لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کل شیء قدیر کہا تو اس کی خطائیں معاف کر دی گئیں‘ اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں‘‘۔(مسلم)
(ب)۔ حضورؐ کا ارشاد ہے :’’ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے مگر میزان میں بہت وزنی ہیں‘ رحمان کو بہت پیار ے ہیں: سبحان اﷲ و بحمدہ‘ سبحان اﷲ العظیم‘‘- (متفق علیہ )
(ج) حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ:’’جس نے لا الہ الا اﷲ وحدہ لا شریک لہ‘ لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کل شیء قد یر دن میں ۱۰۰ مرتبہ کہا تو اس کے لیے ۱۰ غلاموں کو آزاد کرنے کے ساتھ ۱۰۰ نیکیاں لکھی جائیں گی اور ا س کے ۱۰۰ گناہ مٹا دیے جائیں گے‘ اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے بچا رہے گا۔ اور جس شخص نے یہ پڑھا تو کوئی اس سے بہتر عمل نہ کر سکے گا سوائے ا س کے جو اس عمل کو اس سے زیادہ کرے۔ (مسلم)
(د) حضور ؐ نے فرمایا : ’’مجھے سبحان اﷲ والحمد للّٰہ ولا الہ الا اﷲ واﷲ اکبر کہنا ہر اس چیز سے عزیز تر ہے جس پر سورج چمکتا ہے۔ (مسلم)
(ہ) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہم رسولؐ اﷲ کے پا س جمع تھے کہ آنحضورؐ نے فرمایا:’’ کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ روزانہ ہزار نیکیاں کما لے؟‘‘ مجلس میں سے کسی نے سوال کیا:’’وہ ہزار نیکیاں کیسے کما سکتا ہے ؟‘‘ تو آپ ؐ نے فرمایا:’’وہ ۱۰۰ مرتبہ سبحان اﷲ کہے تواس کے لیے ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی ہزار خطائیں مٹا دی جائیں گی۔‘‘ (مسلم)
اﷲ تعالیٰ نے ذکر کرنے والے کے لیے ذکر کو شیطان کے وسوسے‘ اس کی برائی ‘ اس کی پھونک اورتھوک سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ لہٰذا ذاکر‘ اﷲ کے اذن سے محفوظ رہتا ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں چھوتی۔ ذکر سے اسے محفوظ پناہ گاہ اور مضبوط باڑ حاصل ہے‘ اس لیے کہ اس کے دل میں اﷲ کی یاد ہے اور اس کی زبان پر اﷲ کا ذکر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے:
ا - حضرت عبداﷲ بن خبیب ؓ سے روایت ہے کہ رسولؐ اللہ نے فرمایا کہ :’’تم قل ھو اﷲ اور معوذتین صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھو‘ وہ تمھارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گی۔‘‘ (ابوداؤد‘ ترمذی)
ب- حضرت ابوہریرہؓ سے رسولؐ اﷲ کا ارشاد مروی ہے کہ ’’جب نماز کے لیے نداد ی جاتی ہے تو شیطان گوز اڑاتا ہوا پیچھے کو بھاگتا ہے اور جب اذان ہوچکتی ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے۔اور جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔جب اقامت ہو چکتی ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ وہ آدمی کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز یاد کر‘ فلاں چیز یاد کر۔جب تک کہ وہ یاد نہیں کر لیتا اس کو اس کی وسوسہ اندازی جاری رہتی ہے۔حتیٰ کہ بندے کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے‘‘۔(متفق علیہ)
ج- حضرت انس ؓ نے کہاکہ رسولؐ اﷲ کا فرمان ہے:’’ جو شخص اپنے گھر سے نکلا اور اس نے بِسْمِ اللّٰہَ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّٰہِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلاَّ بِاللّٰہِ پڑھ لیا توا سے کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے یہ کافی ہے اور تو بچ گیا اور تو نے ہدایت حاصل کرلی۔ اور شیطان کو اس سے ہٹا دیا جاتا ہے‘‘۔ (ترمذی)
د- حضرت عثمان بن عفان ؓ نے کہا کہ رسولؐ اﷲ نے فرمایا ہے کہ ’’جو مسلمان ہر روز صبح اور شام کو بِسْمِ اﷲِ الَّذِیْ لاَ یَضُرُّ مَعَ اسْمِہٖ شَیْئٌ فِی الْاَرْضِ وَلاَ فِی السَّمَآئِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ (اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی‘ وہ سننے اور جاننے والا ہے)۳مرتبہ پڑھے اسے کوئی شے نقصان نہیں دے گی ‘‘۔ (ابوداؤد ‘ ترمذی)
ھ- حضرت ابومسعود انصاری ؓ نے حضور ؐ سے روایت کیا ہے ’’ جو شخص سورہ البقرۃ کی آخری دو آیات رات کے وقت پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کفایت کریں گی۔‘‘ (متفق علیہ )
ذرا تم ان اثرات پر غور کرو جو ذاکر ہونے سے تم حاصل کرو گے۔ اپنے ماحول پر نظر دوڑاؤ اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو دیکھو۔ تم دیکھو گے کہ کسی کو جن نے چھو رکھا ہے ‘ کوئی سحر زدہ ہے یا اسے شیطان نے بہکا رکھا ہے‘اور تم اﷲ کے فضل سے اس سب کچھ سے محفوظ ہو۔ بلکہ اﷲ عز وجل کا ذکر نفاق سے امان ہے کیوں کہ منافقین اﷲ تعالیٰ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمان الٰہی ہے: لاَ یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ اِلاَّ قَلِیْلاً (النساء ۴:۱۴۲) ’’وہ خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں‘‘۔ حضرت کعبؓ نے کہا:’’ جس نے اﷲ کا ذکر کثرت سے کیا وہ نفاق سے بری ہو گیا (الوابل الصیب ‘ص ۱۷۲۔۱۷۳) ۔ابوخلاد المصری نے ذکر کی قلعہ بندی کے بارے میں کتنی عمدہ با ت کہی ہے:’’ جو اسلام میں داخل ہو ا وہ قلعہ میں داخل ہوا‘ جو مسجد میں داخل ہو ا وہ دو قلعوں میں داخل ہوااور جو اﷲ کا ذکر کرنے والی مجلس میں بیٹھا وہ تین قلعوں میں داخل ہوگیا‘‘۔(الوابل الصیب )
ذکر دلوں کی زندگی اور غفلت ان کی موت ہے۔ ذکر سے دلوں کو حقیقی ایمان کی زندگی ملتی ہے اور اﷲ کے ساتھ دائمی تعلق قائم ہوتا ہے۔ حضور ؐ سے روایت ہے:’’ اپنے رب کو یاد کرنے والے اور اسے یاد نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے‘‘ (بخاری)۔ مسلم کی روایت ہے:’’اس گھر کی مثال جس میں اﷲ کا ذکر ہوتا ہے زندہ کی ‘ اور جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا مردہ کی ہے‘‘۔ گھرکے زندہ اور مردہ سے مراد گھر کے رہنے والے ہیں۔ ذاکر کے زندہ ہونے کا ظاہری پہلو یہ ہے کہ وہ نور حیات سے مزین ہے‘ اور اس کا باطن نور معرفت سے‘ جب کہ ذکر نہ کرنے والوں کے گھر ظاہری طور پر بنجر اور باطنی طو رپر ویران اور تاریک ہوتے ہیں۔
جب دل زندہ ہوتا ہے تووہ ایما ن کے ساتھ آباد ہوتا ہے اور اسی وجہ سے نصیحت اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور یاد دہانی اسے فائدہ دیتی ہے‘ وعدہ اسے طمع اور ترغیب دلاتا ہے اور وعید اسے خوف دلاتی ہے۔پس وہ زندگی میں کامل اور بڑا اثر قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ:
(الف) وہ نرم ہوتا ہے نہ کہ سخت۔ اﷲ تعالیٰ کا فرمان ہے: ثُمَّ تَلِیْنُ جُلُوْدُھُمْ وَ قُلُوْبُھُمْ اِلٰی ذِکْرِ اللّٰہِ (الزمر ۳۹:۲۳) ’’اﷲ کا ذکر(قرآن مجید) سن کران لوگوں کے جسم اور ان کے دل نرم ہوکر اﷲ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں‘‘۔ اور جس کا دل سخت ہوا اور وہ اسی حال میں مر گیا ‘ اس کے بارے میں اﷲ کا فیصلہ ہے: فَوَیْلٌ لِّلْقَاسِیَۃِ قُلُوْبُھُمْ مِّنْ ذِکْرِ اﷲِ (الزمر۳۹:۲۲) ’’تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اﷲ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے‘‘۔ایک شخص نے حسن بصریؒ سے کہا ’’اے ابوسعید !میں تم سے اپنے دل کی قساوت کی شکایت کرتا ہوں‘‘۔ انھوں نے کہا:’’اسے ذکر سے پگھلاؤ۔ یہ اس لیے کہ دل میں جتنی شدید غفلت ہوتی ہے ‘ اتنی ہی شدید اس میں سختی آتی ہے اور جب اس میں اﷲ کی یاد آتی ہے تویہ قساوت تحلیل ہوجاتی ہے‘‘۔
بے شک قرآن کریم زندہ دلوں کوتحریک دیتا ہے ۔ اﷲ تعالیٰ کا فرمان ہے: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُکِرَوا اللّٰہُ وَجِلَتْ قُلُوْبُھُمْ وَ اِذَا تُلِیَتْ عَلَیْھِمْ اٰیَاتُہ‘ زَادَتْھُمْ اِیْمَانًا وَّعَلٰی رَبِّھِمْ یَتَوَکَّلُوْنَ (الانفال۸:۲) ’’سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اﷲ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اﷲ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ‘ اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں‘‘۔بلکہ ذکر کا اثر بہت بڑا ہے جیسا کہ اﷲ تعالیٰ کا فرمان ہے: لَوْ اَنْزَلْنَا ھٰذَا الْقُرآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاَیْتَہ‘ خَاشِعاً مُّتَصَدِعًا مِّنْ خَشْیَۃِ اﷲِ (الحشر۵۹:۲۱) ’’اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اﷲ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے ‘‘۔
(ب) وہ یاد رکھنے والا نہ کہ بھلا دینے والا اور غور وفکر کرنے والا نہ کہ غفلت شعار ہوتا ہے۔ اﷲ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّیْلِ وَالنَّھَارِ لَاٰیٰتِ لِّاُ ولِی الاَلْبَابِo اَلَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ قِیَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِھِمْ وَ یَتَفَکَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ھٰذَا بَاطِلاً ج سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(آل عمران۳:۱۹۰-۱۹۱) ’’زمین اور آسمانوں کی پیدایش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے‘ بیٹھتے اور لیٹتے‘ ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور وفکر کرتے ہیں۔ (وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں) ’’ پروردگار‘ یہ سب کچھ تونے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے‘ تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔پس اے رب‘ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے‘‘۔ جب اس نے عظمت تخلیق دیکھی تو اس نے خالق کو یاد کیا‘ اس کی تسبیح بیان کی‘ اسی کے بارے میں غور وفکر کیا اور نتیجتاً دل کی گہرائیوں سے توجہ اورعجز و نیاز کے ساتھ ا س کو یاد کیا۔پھر اس کے حضور میںآتش دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعا اور گریہ وزاری میں مشغول ہوا۔ ذکر کی بدولت زندہ ہونے کی تاثیر سے جس کے دل کی یہ کیفیت ہو تواس کا دل علم و عمل اور فہم و ادراک کی بہترین حالت میں ہوتا ہے۔ اﷲ تعالیٰ کا فرمان ہے : وَاتَّقُوا اللّٰہَط وَیُعَلِّمُکُمُ اللّٰہَط وَاللّٰہُ بِکُلِّ شَیْئٍ عَلِیْمٌ (البقرہ ۲:۲۸۲) ’’اﷲ کے غضب سے بچو ‘ وہ تم کو صحیح طریق عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے‘‘۔
پس جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اس کا دل پاک و صاف ہو گیا‘ اس کا فہم بڑھ گیا ‘ اﷲ نے اس کے علم و فہم میں اضافہ کر دیا حتیٰ کہ اس کا دل صفائی اورشفافیت میں اس درجہ کو پہنچ گیا کہ وہ حق و باطل میں تفریق کر سکتا ہے۔ یٰٓاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْآ اِنْ تَتَّقُوا اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّکُمْ فُرْقَانًا وَّ یُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّاٰتِکُمْ وَیَغْفِرْلَکُمْ ط وَاللّٰہُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِیْمِ (الانفال۸:۲۹) ’’اے لوگو‘ جوایمان لائے ہو‘ اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اﷲ تمھارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمھاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمھارے قصور معاف کرے گا‘ اﷲ بڑا فضل فرمانے والا ہے‘‘۔ لیکن وہ جس کا دل مردہ ہو گیا وہ فہم و ادراک سے محروم ہو گیا کیوں کہ دل دو چیزوں ‘ غفلت اور گناہ سے زنگ آلود ہوتا ہے‘ اور اس کی جِلا دو چیزوں‘ استغفار اور ذکر سے ہوتی ہے۔ پس جو اکثر اوقات غفلت میں رہتا ہوتواس کے دل پر زنگ تہہ بہ تہہ چڑھ جاتا ہے اور وہ زنگ اس کی غفلت کی نسبت سے ہوتا ہے۔ اور جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے توا س میں معلومات کی صورتیں اپنی اصلی حالت میں منعکس نہیں ہوتیں ۔ وہ باطل کو بصورت حق دیکھتا ہے اور حق کو بصورت باطل۔ کیوں کہ تہہ بہ تہہ زنگ سے دل تاریک تر ہو جاتا ہے اور اس میں حقائق کی صورتیں اصلی حالت میں نہیں آتیں ۔ پس جب دل پر تہہ بہ تہہ زنگ چڑھ گیا اور وہ بہت سیاہ اور میلاکچیلا ہو گیا توا س نے اس کے فہم و ادراک کوروک دیا۔(الوابل الصیب ‘ ص ۸۹)
ذاکر‘ ذکر کے ساتھ اپنے رب کی بندگی کی حقیقت اور اس سے استعانت کی طلب کو اپنے ذہن میں تازہ کرتا ہے‘ کیوں کہ اذکار کے الفاظ اﷲ کی عظمت کا اقرار ‘ اور اس کی نعمتوں پر اس کی حمد اور اس کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ جب ذاکر کہتا ہے : سبحان اﷲ والحمد للّٰہ ولا اِلٰہ الا اﷲ واﷲ اکبر ‘تو اس کو اس کا شعور بھی ہوتا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے اپنے رب کو واحد باور کیا‘ اس کی تعظیم کی تو وہ اس کی جناب میں اپنے فقر کا شعور رکھتا ہے ‘اور اپنے آپ کو اس کے حضور میں گرا پڑامحسوس کرتا ہے اور اس کی مدد کا طلب گار ہوتا ہے۔ اگر دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو ذاکر ہر طرح کے حالات میں ذاکر ہوتا ہے ‘ نتیجتاً وہ ہر عمل کی ابتداء میں یا حالات کے بدلنے پر اﷲ کو یاد کرتا ہے تواسے اپنی حاجت یاد آ جاتی ہے جس کے لیے وہ اﷲ سے مدد کی درخواست کرتا ہے‘مثلاً جب وہ گھر سے نکلتا ہے تواس موقع کے لیے ایک ذکر ماثور ہے۔ جب اس نے ذکر کے وہ الفاظ کہے تواسے اپنے رب سے اپنی حفاظت اور اپنے رزق کے لیے مدد مانگنا یا د آگیا اور جب وہ کسی موٹر کار یا کسی جانور پر سوار ہوا اور ا س نے اﷲ کا زبان سے ذکر کیا تو اس کے دل میں اﷲ کی یاد آگئی اور اسے اپنی حاجت کے لیے اﷲ سے مدد مانگنے کا خیال آگیا‘ اور اسی طرح سے جب اس نے لباس پہنایا اسے اتارااور جب وہ سویا یا بیدار ہوا تو اس نے اﷲ سے استعانت کی حاجت محسوس کی۔
ہم بسم اﷲ کی واضح مثال لیتے ہیں جس کاہرکام کے آغاز میں پڑھنا نبی ؐ کی حدیث کی روسے مستحب ہے۔ آنحضورؐ نے فرمایا:’’ہر وہ عمل جو بسم اﷲ سے شروع نہ کیا گیا وہ بے برکت ہوا‘‘۔ اعمال کے آغاز میں‘ نیز کثیر اذکار میں بسم اﷲ وارد ہے۔پس کھانا کھانے کے وقت بسم اﷲہے‘ گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت بسم اﷲ ہے اور اس کے دو معانی ہیں:
۱- جب بندے نے کہا بسم اﷲ تواس کو اپنا خالق و مالک یاد آیا اور یہ کہ وہ عاجز بندہ ہے جومسلسل اﷲ کا ذکر کرتا اور اسی کا نام لیتا رہتا ہے اور اس کے فضل کااعتراف کرتا رہتا ہے۔ دنیا میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں اپنے مالک کا ذکرکرتے رہتے ہیں۔ فرد کا نام اس کے مالک کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اعلیٰ مثال تو اﷲ ہی کی ہے۔پس اے انسان! تو بندگی میں اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اﷲ کے نام کے ساتھ لوگوں سے مخاطب ہو۔
۲- بسم اﷲ کہنے میں اللہ کی مدد کی طلب بھی ہے۔جس طرح کہ کھانے کے وقت جب بندہ کہتا ہے کہ میں اﷲ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں اور نکلنے کے وقت وہ کہتا ہے کہ میں اﷲ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں‘ تواس کے اندر بھی مدد کی طلب پائی جاتی ہے ۔
حقیقت یہ ہے کہ بندے کے لیے مصائب برداشت کرنے اور آزمایشوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اﷲ کا ذکر بہت بڑی تاثیر کا حامل ہے۔ مصیبت کے وقت وہ کہتا ہے: اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ(البقرہ۲:۱۵۶) ’’ہم اﷲ ہی کے ہیں اور اﷲ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے‘‘ تو ا س کے نفس کو سکون اور دل کو اطمینان نصیب ہوجاتا ہے۔ اس کی عزیمت قوی اور اس کی ہمت بلند ہو جاتی ہے۔
اس میں شک نہیں کہ اﷲ کا ذکر مشکل کو آسانی‘ تنگی کو فراخی اور مشقت کو خفیف کر دیتا ہے۔ اﷲ کا ذکر شدت کے بعد خلاصی‘ تنگی کے بعد فراخی‘ رنج و غم کے بعداس سے رہائی ہے۔ وہ ذاکر کو قوت مہیا کرتا ہے۔ ذکر کے ساتھ وہ وہ کچھ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے جو اس کے بغیر نہیںکرسکتا۔ (الوابل الصیب‘ص ۱۶۳)
جب حضرت فاطمہؓ بنت محمد ؐنے اپنے والد گرامی جناب رسولؐ اﷲ سے گھر کے کام میں معاونت کے لیے خادم مانگا تو آنحضورؐنے انھیں اور ان کے شوہر حضرت علیؓ سے فرمایا:’’کیا تمھیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمھارے لیے خادم سے بہتر ہے؟ جب تم بستر پر لیٹو تو اﷲ کی تسبیح ۳۳ مرتبہ‘ تحمید ۳۳ مرتبہ اور تکبیر ۳۴ مرتبہ کرو۔ یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے‘‘(متفق علیہ)۔
اﷲسبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُھُمْ بِذِکْرِاﷲِ ط اَلاَ بِذِکْرِ اﷲِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (الرعد۱۳:۲۸) ’’جنھوں نے نبیؐ کی دعوت کو مان لیا‘ان کے دلوں کو اﷲ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہنا اﷲ کی یاد ہی وہ چیزہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے‘‘۔ یہ اﷲ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے اطلاع ہے کہ وہ اپنے دلوں کو اﷲ کے ذکر سے مطمئن کریں۔ وہ دلوں کے قلق و اضطراب کو زائل کر دے گا اور انھیں راحتیں اور لذتیں مہیا کرے گا۔ مزیدیہ کہ وہ اﷲ کے ذکر کے سوا کسی چیز سے مطمئن ہوتے بھی نہیں۔ کیوں کہ دلوں کے لیے ان کے خالق کی محبت ‘اس کے انس اور اس کی معرفت سے بڑھ کر کوئی چیز لذیذ نہیں۔ (تفسیر السعدی‘ج ۴‘ ص ۱۰۸)
طمانیت ‘ دل کا کسی چیز کے ساتھ سکون حاصل کرنا اوراضطراب و قلق کا خاتمہ ہے۔ (تہذیب المدارج‘ ص ۵۰۳)۔ ذاکر کا سکونِ قلب خوش حالی و بدحالی ‘تنگی و فراخی ہر حال میں دائمی ہے۔
اگر ذکر سے یہاں مراد قرآن کریم ہے توقرآن وہ ہے جس سے اہل ایمان کے دلوں کو طمانیت حاصل ہوتی ہے۔دل ایمان اور یقین کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے اور ایمان و یقین کے حصول کا کوئی راستہ قرآن کریم کے علاوہ نہیں ہے۔ دل کا سکون اور اس کی طمانیت یقین سے ہے‘ جب کہ اس کا اضطراب اور قلق شک سے ہے۔ پس جس نے قرآن سے تعلق پیدا کر لیا تو اس سے اسے عقل کا اطمینان ‘نفس کی سکینت میسر آئی اور اس کے دل نے ایمان و یقین کے ساتھ سکون پا لیا۔
اﷲ تعالیٰ کا ذکر‘ ذاکرین کے افعال اور ان کے معمولات میں برکت پیدا کرتا ہے۔ ذکر منعم کی نعمت اور رازق کی عطا پر دل و دماغ میں اس کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ذکر منعم کے شکر اور اس کی حمد پرمشتمل ہے۔جس نے اﷲ کی نعمت کا اقرار کیا اور اس پر اس کا شکر ادا کیا تو اﷲ تعالیٰ نے وہ نعمت ا س کے لیے محفوظ فرما دی بلکہ اس میں اضافہ فرمایا جیسا کہ اﷲ عزوجل کا ارشاد ہے: لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَاَزِیْدَنَّکُمْ وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِیْ لَشَدِیْدٌ (ابراھیم۱۴:۷) ’’ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے‘‘۔
امام مسلم کی صحیح روایت کردہ حدیث پر غور کرو کہ حضورؐ نے فرمایا:’’ اﷲ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ جب کھانا کھاتا ہے توا س پر اﷲ کی حمد بیان کرتا ہے اور جب کوئی مشروب پیتا ہے تو اس پر اﷲ کی حمد بیان کرتا ہے‘ اور یہ سب کچھ کھانا اور پینا اسے کھلانے ‘ پلانے‘ عطا کرنے والے کی یاد دلاتا ہے۔‘‘ پس وہ منعم کی عظمت کو اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہوئے اور اس کی نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے جو کہ اس نے انسانوں کے لیے آسان فرما دی ہے‘ اس کی حمد و شکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھتا ہے۔
پانی ہی کو لیجیے جو ایک نعمت ہے ۔ اگر انسان کو ا س سے محروم کر دیا جائے تواس کی کتاب زندگی کا آخری صفحہ آجائے اور وہ دنیا کو چھوڑ جائے۔ پانی کا ایک پیالہ شدید پیاس کی حالت میں پوری دنیا کے برابر ہے‘ توپھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہ تو اﷲ کی حمد بیان کرتے ہیں اور نہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں! کیا اس کی تذکیر و تنبیہ ہماری آنکھیں نہیں کھولتی؟ اَلاَ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَھُوَ الَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ (الملک۶۷:۱۴) ’’کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے ؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے‘‘۔ کیا ہم اس کی تحذیر سے نہیں ڈرتے؟ اَفَرَاَیْتُمُ الْمَآئَ الَّذِیْ تَشْرَبُوْنَ o ئَ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْہُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَo لَوْ نَشَآئُ جَعَلْنَاہُ اُجَاجًا فَلَوْ لاَ تَشْکُرُوْنَ(الواقعہ۵۶:۶۸-۷۰) ’’کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا‘ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تواسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں‘ پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟‘‘
ذکر سے برکت حاصل ہوتی ہے‘ جب کہ اس کو مٹانے والی چیز کو روک دیا جائے اور ابلیس کے تسلط اور کھانے پینے میں شرکت سے تحفظ حاصل کرلیاجائے۔حدیث میں ہے:’’ شیطان آدمی کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھانے پینے میں حصہ دار بن جاتا ہے‘جب کہ اسے وہاں سے ہٹانے والا کوئی ذکر نہ ہو‘ روکنے والا کوئی مضبوط قلعہ نہ ہو اور اس کو رد کرنے والی کوئی دعا نہ ہو‘‘۔
بیشتر لوگ اس ذکر مسنون سے بے خبرہیں جو آدمی کو اپنی اہلیہ کے ساتھ مباشرت کے موقع پر کرنا چاہیے۔ غلبہ خواہش کے وقت اسے بھول جاتے ہیں‘ حالانکہ وہ بڑا اہم ذکر ہے۔ اﷲ نے جو اولاد ان کے مقدر میں لکھی ہو‘ اس کے حفظ و امان میں اس ذکر کی تاثیر ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے: لَوْ اَنَّ اَحَدَکُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ یَاْتِیَ اَھْلَہٗ قَالَ بِسْمِ اﷲِ اَللّٰھُمَّ جَنِّبْنَا الشَّیْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّہٗ یُقَدَّرُ بَیْنَھُمَا وَلَدٌ لَمْ یَضُرَّہٗ شَیْطَانٌ اَبَدًا (متفق علیہ) ’’جب تم میں سے کوئی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اﷲ کہے اور یہ کہے ’’اے اﷲ! تو شیطان کے شرسے ہمیں بچا اور جو اولاد ہمیں عطا کرے اسے بھی بچا تو اگر ان کے بچہ مقدر ہوگا تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا‘‘۔ اس حدیث میں مذکور اس حفاظت کے معانی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان اس پر اﷲ کے نام کی برکت کی وجہ سے کبھی غالب نہ آئے گا۔ اس میں وہ سارے بندے پیش نظر ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے: اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْھِمْ سُلْطَانٌ اِلاَّ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِیْنَ(الحجر۱۵:۴۲) ’’بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا۔ تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں‘‘۔
اجر و ثواب کے ان عظیم فوائد اور آثار پر غور کرو‘ نیز حفظ و سلامتی‘ زندگی اور علم ‘ برکت اور نعمت‘ عبودیت اور استعانت اور جو اس سے بھی عظیم تر ہے اس پر غور کرو۔
کیا تم اپنے نفس کے لیے بخل کرنے اور اسے ان بھلائیوں اور برکتوں سے محروم رکھنے پر راضی ہو؟ کیا تم اجر سے بے نیا زہو کر ذکر کو ترک کر دو گے‘ جب کہ وہ اجرکا بڑا ذریعہ اور سبب ہے؟
تم کیسے اپنے نفس کو شیطان کی تیر اندازی اور اپنے دل کو اس کے غلبے کے لیے کھلاچھوڑ دو گے‘ جب کہ تم ذکر کرنے والوں میں سے نہ ہوئے؟ اور تم اپنے دل کے روگ اور اس کی موت کا احساس نہ کرو گے‘ جب تم منکر پر نکیر نہ کرو گے اور اﷲ کی حرمات کی حفاظت کے حریص نہ بنو گے؟
تم کیسے اپنے ضعفِ فہم اور قلت ِعلم کی طرف توجہکرو گے‘ جب کہ تم غافل رہو گے؟اور تم کیسے اپنے خالق ‘ اپنے مالک ‘ اپنے رازق اور نعمتوں کے عطا کرنے والے کے ذکر سے غافل بنوگے؟ بلاشبہہ ان میں سے کوئی چیز بھی تمھیں پسند نہیں بلکہ تم ان سب سے پناہ مانگتے ہو۔ لہٰذا ذکر کی طرف بڑھو‘ اس کے خواہش مند بنو اور اس میں سے مسنون اذکار حفظ کر لو‘ ان کے ساتھ اپنے دل کو متحرک کرو اور اپنی عقل کو ان میں مشغول رکھو‘ اور اپنی زبان کو ان کے ساتھ تر رکھو تاکہ تم ذاکرین میں شمار کیے جاؤ اور علیین میں اٹھائے جاؤ۔
ذکر کی اس تاثیر اور اجر کے ساتھ کچھ ایسی خصوصیات بھی ہیں جو ان کو اختیار کرنے میں مددگار ہیں۔
ذکرسہل ہے ‘مشکل نہیں۔ وہ کسی بدنی عمل کا محتاج نہیں اور نہ ذہنی کاوش ہی کا۔ وہ استحضار قلب اور تعاون نفس کے ساتھ زبان سے ادایگی ہے‘ جب کہ دوسری عبادات میں بڑی محنت ہوتی ہے۔ رمضان کے روزوں میں بھوک و پیاس کی مشقت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ میں بذل و انفاق کی نفسیاتی مشقت ہوتی ہے۔ حج میں سفر اور مناسک کی ادایگی میں بدنی مشقت ہوتی ہے۔ مگر ذکر سب سے زیادہ آسان عبادت ہے اور پھر وہ ان میں سے برتر و افضل بھی ہے‘ جب کہ وہ زبان کی حرکت ‘اعضا و جوارح کی حرکات میں سے سب سے ہلکی اور آسان ہے۔(الوابل الصیب‘ ص ۹۷)
مزید برآں ذکر کی کوئی شرائط نہیں ہیں‘ مثلاً نماز کے لیے وضو اور وقت کا ہونا ناگزیر ہے‘ اور حج کے لیے بیت اﷲ کا قصد ضروری ہے‘ اورزکوٰۃ سال میں صرف ایک بار ہے‘ اور روزوں کے لیے رمضان کا چاند نظر آنا ضروری ہے لیکن ذکر میں اس طرح کی کوئی قید نہیں۔ وہ جملہ عبادات میں سے سب سے زیادہ آسان ہے جس میں کوئی محنت و مشقت نہیں۔عبید بن عمیر نے اس بارے میں کہا ہے:’’اگر یہ رات تم پر بھاری ہے کہ تم اس کی مشقت جھیلو‘ اور اگر تم نے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا ہے‘ اور اگر تم دشمن خدا سے لڑنے سے اجتناب کرتے ہو توکثرت سے اﷲ عزوجل کا ذکر کرو۔‘‘
ذکربلا قید دن اور رات کے تمام اوقات پر مشتمل ہے۔ فَاصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِھَا ج وَمِنْ اٰنَآئِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ اَطْرَافَ النَّھَارِ لَعَلَّکَ تَرْضٰی (طٰہٰ۲۰:۱۳۰) ’’پس اے نبیؐ، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو‘ اور اپنے رب کی حمد وثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو‘ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروںپر بھی‘ شاید کہ تم راضی ہوجاؤ‘‘۔ا س کی ادایگی ہر جگہ اور ہر حال میں بیٹھے‘ کھڑے اور لیٹے کی جاسکتی ہے۔ اﷲ تعالیٰ کا فرمان ہے: ’’جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں‘‘(آل عمران۳:۱۹۱) ۔ اس طرح کا کوئی اور عمل نہیں ہے جس میں اوقات واحوال کی عمومیت پائی جاتی ہو۔ (الوابل الصیب‘ص ۱۰۸)
اس مرحلے پر ہم رسولؐ اﷲ کے معمول مبارک سے متعارف ہوتے ہیں کہ حضور ؐ ہر حال میں اﷲ کا ذکر کرتے تھے۔ اور ذکر میں تنوع وہ خصوصیت ہے جو بہت سارے اذکار مسنون کے ضمن میں نمایاں ہے۔دعاے استفتاح میں رسولؐ اﷲسے متنوع صورتیں وارد ہیں اور صبح و شام کے بہت سے اذکار ہیں جن میں سے بعض دوسروں سے بے نیا زکردیتے ہیں۔
ذکر جس میں قلب زبان کے ساتھ ہوتا ہے‘ نفس پر اس کی عظیم اور براہ راست تاثیر ہوتی ہے‘ اس لحاظ سے کہ وہ زبان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے ۔جس پر کوئی مصیبت آپڑی اور اس نے کہا: انا للّٰہ وانا الیہ راجعون اور لا حول و لا قوۃ الا باﷲ تواس نے شرح صدر اور اطمینان قلب محسوس کیا اور اﷲ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی تقدیر پر اپنی رضا کا اظہار کیا۔ اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے: ’’تم مجھے یاد رکھو میں تمھیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو‘ کفران نعمت نہ کرو ۔ اے لوگو‘ جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو‘‘(البقرہ۲:۱۵۲-۱۵۳) ۔اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ہر مصیبت میں جاے پناہ اور ہر تکلیف میں موجب راحت ہے۔
ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ ابن القیم ؒ نے کہا ہے:’’ذکر کی تین قسمیں ہیں: وہ ذکر جس میں دل زبان کا رفیق ہو‘ وہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور دل کے ساتھ ذکر اس کا دوسرا درجہ ہے۔ اور صرف زبان سے ذکر اس کا تیسرا درجہ ہے۔‘‘(تہذیب المدارج‘ ص ۴۶۷)
ابن حجر ؒنے کہا ہے: ’’ ذکر بعض اوقات زبان سے ہوتا ہے اور اس پر ذاکر کو اجر دیا جاتا ہے اور اس کے معانی کا استحضار شرط نہیں ہے۔ لیکن وہ اس سے مشروط ہے کہ اس کا مقصود اس کے معنی کے علاوہ کچھ اور نہ ہواور اگر الفاظ کے ساتھ دل کو ملا لیا جائے تو وہ کامل ترہے۔ اگر زبان وقلب کے ساتھ معنی کو جمع کر لیا جائے اور وہ اﷲ تعالیٰ کی عظمت پر مشتمل ہو اور اس کے نقائص سے مبرا ہو تو اس کے کمال میں اضافہ ہو جائے گا‘اوراگر یہ ذکر نماز اور جہا دجیسے دیگر فرائض میں واقع ہو تواس کا کمال اور بڑھ جائے گا۔ اگر اس میں توجہبھی درست ہو اور نیت بھی خالصتاً اﷲ تعالیٰ کے لیے ہو توکمال آخری حد کو پہنچ جائے گا‘‘(الفتح ‘ج ۱۱‘ ص ۲۰۹)۔
فخرالدین رازیؒ نے کہا ہے: ’’ زبان کے ذکر سے مراد وہ الفاظ ہیں جو اﷲ کی تسبیح‘ تحمید‘ تکبیر اور تمجید پر دلالت کرتے ہوں ۔ دل کے ساتھ ذکر‘ اﷲ تعالیٰ کی ذات و صفات کے شواہد میں غور و فکر کرنا ہے۔ اﷲ کی تخلیق کے آثار میں غور و فکر‘ نیز اوامر و نواہی کے دلائل میں سوچ بچار‘ حتیٰ کہ بندہ ان کی حکمت سے آگاہ ہو جائے ۔ اعضاے جسمانی کے ساتھ ذکر دراصل طاعات میں شدتِ انہماک ہے‘‘۔ (الفتح ‘ ج۱۱‘ ص ۲۰۹)
ابن القیم ؒنے کہا ہے:’’ذکر کی تین قسمیں ہیں:ثنا‘ دعا اور رعایت۔ ذکرِ ثنا یوں ہے : سبحان اﷲ والحمد للّٰہ ولا اِلٰہَ اِلاَّ اﷲ واﷲ اکبر۔ ذکرِ دعا: رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَاسکتۃ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ(الاعراف ۷:۲۳)’’اے رب ‘ ہم نے اپنے اوپر ستم کیا اور اگر تُو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقینا ہم گمراہ ہو جائیں گے‘‘۔ یاحی یاقیوم برحمتک استغیث۔ا ور جہاں تک ذکرِ رعایت کا تعلق ہے تو وہ ذاکر کے اس قول کے مثل ہے: اللھم معی‘ اللّٰہ ناظر علی ‘ اﷲ شاھدی‘ اور اس طرح کا ذکر جس سے اﷲ کے ساتھ حضوری کی تقویت استعمال کی جاتی ہے ۔ اور اس میں دل کی اصلاح کی رعایت ہو‘ اﷲ تعالیٰ کے ساتھ ادب کی حفاظت‘ اور غفلت اور شیطان اور نفس کی برائی سے اجتناب ہو۔ (تہذیب المدارج‘ ص ۴۶۸)
]اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے فرمایا: ’’اے نبیؐ، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو۔ دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں‘‘۔ (الاعراف ۷:۲۰۵)
یاد کرنے سے مراد نماز بھی ہے اور دوسری قسم کی یاد بھی‘ خواہ وہ زبان سے ہو یا خیال سے۔ صبح و شام سے مراد یہی دونوں وقت بھی ہیں اور ان اوقات میں اللہ کی یاد سے مقصود نماز ہے‘ اور صبح و شام کا لفظ ’’دائماً‘‘ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے مقصود ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہنا ہے… اس کی غرض یہ بیان کی گئی ہے کہ تمھارا حال کہیں غافلوں کا سا نہ ہوجائے۔ دنیا میں جو کچھ گمراہی پھیلی ہے اور انسان کے اخلاق و اعمال میں جو فساد بھی رونما ہوا ہے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ خدا اُس کا رب ہے اور وہ خدا کا بندہ ہے اور دنیا میں اُس کو آزمایش کے لیے بھیجا گیا ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد اسے اپنے رب کو حساب دینا ہوگا۔ پس جو شخص راہِ راست پر چلنا اور دنیا کو اُس پر چلانا چاہتا ہو اُس کو سخت اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ بھول کہیں خود اُس کو لاحق نہ ہو جائے۔ (تفہیم القرآن‘ ج۲‘ ص ۱۱۴-۱۱۵)[
]ایک دوسرے مقام پر فرمایا: ’’یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اُس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جائو جو اُن کے لیے اُتاری گئی ہے‘‘۔ (النحل ۱۶:۴۴)
تشریح و توضیح صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی‘ اور اپنی رہنمائی میں ایک پوری مسلم سوسائٹی کی تشکیل کرکے بھی‘ اور ’’ذکرِالٰہی‘‘ کے منشا کے مطابق اُس کے نظام کو چلا کر بھی۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بیان کر دی ہے جس کا تقاضا یہ تھا کہ لازماً ایک انسان ہی کو پیغمبر بناکر بھیجا جائے۔ ’’ذِکر‘‘ فرشتوں کے ذریعہ سے بھی بھیجا جا سکتا تھا۔ براہِ راست چھاپ کر ایک ایک انسان تک بھی پہنچایا جا سکتا تھا۔ مگر محض ذکر بھیج دینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت و ربوبیت اس کی تنزیل کی متقاضی تھی۔ اُس مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ اس ’’ذکر‘‘ کو ایک قابل ترین انسان لے کر آئے۔ وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کرکے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ جن کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے اس کا مطلب سمجھائے۔ جنھیں کچھ شک ہو ان کا شک رفع کرے۔ جنھیں کوئی اعتراض ہو ان کے اعتراض کا جواب دے۔ جو نہ مانیں اور مخالفت اور مزاحمت کریں اُن کے مقابلے میں وہ اُس طرح کا رویہ برت کر دکھائے جواِس ’’ذکر‘‘ کے حاملین کی شان کے شایاں ہے۔ جو مان لیں انھیں زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کے متعلق ہدایات دے‘ ان کے سامنے خود اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کرے‘ اور ان کو انفرادی و اجتماعی تربیت دے کر ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا پورا اجتماعی نظام ’’ذکر‘‘ کے منشا کی شرح ہو۔ (ایضاً‘ ص ۵۴۳)[
تم نے دیکھ لیا ہے کہ ذکر میں کتنی بھلائیاں ہیں۔ وہ کتنا سہل و آسان ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ اوقات کے حوالے سے اس میں کتنی وسعت ہے؟
عظیم نعمتیں ہیں جو اﷲ نے ہماری طرف بھیجی ہیں‘تو کیا ہم ان سے غافل رہیں اور محرومین میں سے ہو جائیں؟ ہماری زندگی میں غفلت ‘ اچانک وارد ہو نے والا خطرہ ہے۔ دل بہلاوے اور اکتاہٹیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ جھوٹ اور گھٹیا کلام ‘ ناجائز دولت‘گستاخ شاعری‘ غیبت کی اشاعت ‘چغلی کی کثرت‘ باہمی گالی گلوچ اور بڑی برائیوں کے ساتھ زبان درازی کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے اور اس سب کچھ نے قلب کے نور کو بجھا دیا ہے اور اس کی قساوت کو بڑھا دیا ہے۔بلائیں بڑھ گئی ہیں اور مصیبتیں شدید ہو گئی ہیں‘ جب کہ اﷲ کے سوا انھیں کو ئی دور کرنے والا نہیں۔
غفلت بلا شبہہ دنیا میں بیماری ہے ‘اور آخرت میں ندامت و بدبختی۔ رسولؐ اﷲ نے فرمایا: ’’جو لوگ بیٹھے اور اس نشست میں اﷲ کا ذکر نہیں کیا تو یہ نشست ان کے لیے حسرت اور خسران کا باعث ہوگی۔ اﷲ چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا‘‘ (ترمذی) ۔ افسوس اور حسرت ہے غفلت شعاروں پر!..
ذکر کی مجالس فرشتوں کی مجالس ہیں اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں‘اور جس کی جس کے ساتھ نسبت ہے وہ اسی کی مثل ہے(الوابل الصیب‘ص ۱۵۸)۔ تم دونوں میں سے کس فریق کے ساتھ ہونا چاہتے ہو؟
آخرمیں شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا قول ہے :’’ذکر دل کے لیے ایسا ہی ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی۔ مچھلی جب پانی سے جدا ہوتی ہے تواس کا کیا حال ہو جاتا ہے ؟ (الوابل الصیب‘ ص ۹۳)۔ یہ وہ معروف سوال ہے جس کا جواب ہے:’’ احتیاط‘غفلت سے احتیاط‘ اور اﷲ ہی اﷲ کا ذکر ‘‘۔
بعید نہیں کہ اﷲ ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے اور ذکر کی بدولت ہمارے اجر بڑھا دے ‘اس کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے اور اس کے باعث ہمارے رنج و غم مٹا دے اور اس کے ساتھ ہماری روحوں کو راحت حاصل ہو!
اے اﷲ! تُو اپنے ذکر ‘ اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت میںہماری مدد فرما۔
(المجتمع ‘ شمارہ ۱۴۸۳-۱۴۸۵)
(کتابچہ دستیاب ہے۔ قیمت: ۶ روپے۔ منشورات‘ منصورہ‘ ملتان روڈ‘ لاہور)
محبت کا لفظ خود اپنے اندر بڑی مٹھاس‘ کشش‘ کیف ‘ لذّت اور مزہ رکھتا ہے۔ کسی کے بھی تعلق کے ساتھ یہ لفظ بولا جائے تو دل میں زندگی کی ایک رو دوڑ جاتی ہے۔ ہم سب ہی محبت کے مزے سے آشنا ہوتے ہیں۔ یہ کوئی انوکھی اور اجنبی چیز نہیں ہے۔ انسانوں کے تعلق سے بھی ‘ محسوسات کے تعلق سے بھی‘ مال و دولت کے تعلق سے بھی‘ اپنی عزت اور آن کے تعلق سے بھی‘ اور خود اپنے نفس سے محبت کے تعلق سے بھی ہم سب خوب جانتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے اور محبت کا مزہ اگر دل کو لگ جائے اور دل میں اتر جائے تو یہ کیا کرشمہ دکھاتی ہے۔ عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ وہ مقام اور درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ایمان کی نشانی‘ ایمان کی شرط اور ایمان کی روح ہے۔ ایمان کا راستہ ہی عشق و محبت کا راستہ ہے۔ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْآ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ ط (البقرہ ۲:۱۶۵)’’ایمان رکھنے والے اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں‘‘۔جو بھی ایمان لائیں گے وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں گے۔ اس کے دین پر عمل کریں گے‘ اُس کے دین کو قائم کریں گے۔ اپنی محبت کو پہلے بیان فرمایا ہے کہ جو اس کی راہ پر آجائے‘ اس کی راہ پر چل پڑے‘ اپنے آپ کو اس کے دین کے لیے لگا دے تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے پیار کرتا ہے۔ دیکھیے یہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ یُّحِبُّھُمْ وَ یُحِبُّوْنَہٗٓ (المائدہ ۵:۵۴) ’’اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں‘‘۔
یہ محبت تو ایمان کی روح اور ایمان کی جان ہے۔ اِس کے بغیر تو ایمان چند الفاظ کا مجموعہ ہے جو زبان سے ادا ہو جائے‘ ایک لباس ہے جس کو آدمی وضع قطع اور چال ڈھال کے مختلف طریقوں سے اپنے اوپر اوڑھ لے۔ لیکن اصل ایمان تو وہ ہے جو دل کو بھی لذّت بخشے اور جس کے پیچھے چلنے میں مزہ بھی آئے۔ اسی لیے نبی کریمؐ نے یہ بھی فرمایا: کہ جن چیزوں سے ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے اُن میںسے ایک یہ ہے کہ ‘ اِن یکون اللّٰہ والرسول احب الیہ ممن سوآئٌ علیھم‘ اللہ اور اس کے رسولؐ ان دو کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو جائیں ۔جب یہ کیفیت ہوتی ہے تبھی ایمان دل میں اترتا ہے‘ ایمان کا مزہ ملتا ہے اور ایمان میں لذّت آتی ہے۔
ایمان کے مطالبے آدمی دل کے تقاضے سے پورے کرتا ہے۔ محبت کی راہ میں کسی کو دھکا نہیں دینا پڑتا ہے کہ جائو اس کے کوچے میں جائو‘ جو محبوب ہے اس کی گلی میں جائو‘اس کے دروازے پر جائو‘ اس کو یاد کرو‘ اس کا نام لکھو۔ یہ سب سبق کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محبت خود ہی استادوں میں سب سے بڑی استاد ہے ‘ سکھانے والوں میں سب سے بڑی سکھانے والی اور قوتوں میں سب سے بڑی قوت ہے۔ یہ انسانوں کے دل فتح کر لیتی ہے‘ جمادات اور نباتات کے دل فتح کر لیتی ہے۔ کسی پودے کو آپ پیار دے کر دیکھئے‘ پانی دیجئے‘ خبرگیری کیجیے وہ لہلہا اٹھتا ہے‘رنگ برنگ کے پھول آپ کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ جس کو بھی آپ محبت دیں گے وہ مفتوح ہو جائے گا۔ اس کا دل بھی فتح ہو جائے گا اور وہ آپ کا غلام بھی بن جائے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور اللہ کے واسطے سے اور بہت ساروں کی محبت‘ یعنی اس کے رسولؐ کی ‘ اُس کی کتاب کی ‘اُس کے دین کی ‘ اُس کی امت کی اور اس کی راہ میں ساتھ چلنے والوں کی ۔ یہی محبت کی زندگی ہے۔ اِس کی کمی اُن سارے مسائل کی جڑ ہے جو ہمیں درپیش ہیں۔ جتنی یہ محبت پیدا ہوتی جائے گی‘ دل میں اترتی جائے گی اور جتنی رچتی بستی جائے گی اتنا ہی مسائل کا جنگل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اور بہنو‘ سب سے بڑھ کر تو اسی محبت کی فکر کرنی چاہیے۔
یہ محبت مصنوعی ذرائع سے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس طرح کی طبعی چیز بھی نہیں ہے جس طرح باپ کو بیٹے سے ہو جاتی ہے‘ ایک مرد کو عورت سے ہو جاتی ہے یا آدمی کو کسی حسین چیز سے ہو جاتی ہے۔ لیکن حُسن‘ جمال اور کمال اگر سب سے بڑھ کر کسی کے پاس ہے تو وہ حبیب حبیب ِعالمؐ ہیں۔ اُسی کے حُسن کا ایک جلوہ ہے جو کائنات میں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ جدھر بھی دیکھیں گے حُسن بکھرا ہوا ہے‘ پہاڑوں اور درختوں اور پھولوں اور پرندوں میں‘ ہر جگہ اُس کا حسن جلوہ گر ہے۔ یہی حسن ازلی‘ ابدی اور اعلیٰ ہے۔
حسن سے ہی احسان نکلا ہے۔ احسان کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر ذی نفس کا ہر سانس جو اندر جاتا ہے وہ بھی اُس کا احسان ہے اور جو باہر آتا ہے وہ بھی اس کا احسان ہے۔ہر لقمہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے منہ میں رکھ رہا ہے یہ اسی کی توفیق و عنایت ہے۔ انسان خود نہیں رکھتا۔پانی کا ہر گھونٹ جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے اٹھا کر پیا ہے وہی پلاتا ہے۔ وَالَّذِیْ ھُوَ یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِo (الشعراء ۲۶:۷۹) ’’وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے‘‘ ۔ آدمی دوا کھا کر سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہو گیا‘ ڈاکٹر نے بڑی اچھی دوا دی لیکن حقیقت یہ ہے کہ وَاِذَا مَرِضْتُ فَھُوَ یَشْفِیْنِo (الشعراء ۲۶:۸۰)’’جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا بخشتا ہے‘‘۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کے بغیر مل سکتی ہے۔ اگر مل سکتی تو دینے والا خود خدا بن جاتا اور جو خدا سے بے نیاز ہو کر دے سکتا وہ تو خود خدا ہوتا۔ کائنات میں دو خدا تو نہیں ہیں۔ ایک ہی خدا ہے۔ دینے والا بھی ایک ہی خدا ہے‘ کوئی اور نہیں ہے اور ہو نہیں سکتا۔
محبت میں یہ تقاضا نہیں ہے کہ صرف اُسی سے محبت ہو‘ بلکہ یہ تقاضا ہے کہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت ہو۔ اس نے اور بھی محبتیں رکھی ہیں‘ اور بھی چیزوں کو محبوب بنایا ہے: مال کی محبت‘ عزیز و اقربا کی محبت‘ دنیامیں اپنے لیے عزو جاہ کی محبت‘ یہ سب اُسی نے رکھی ہیں۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوٰتِ مِنَ النِّسَآئِ وَالْبَنِیْنَ وَالْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنْْطَرَۃِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّۃِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوََّمَۃِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِط (آلِ عمران ۳:۱۴) ’’لوگوں کے لیے مرغوبات نفس--- عورتیں‘ اولاد‘ سونے چاندی کے ڈھیر‘ چیدہ گھوڑے‘ مویشی اور زرعی زمینیں ---بڑی خوش آیند بنا دی گئی ہیں‘‘۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی محبت رکھ دی گئی۔ لیکن فرمایا کہ سب سے بڑھ کر محبت تو اُسی کے لیے ہونی چاہیے۔ جب اس کی محبت کا تقاضا آجائے تو وہ سب پر غالب ہونا چاہیے۔ اس میں پھر کوئی اشتباہ کی گنجایش نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں تو نہیں‘ لیکن سابقہ صحِف سماوی میں اللہ تعالیٰ جب اپنی محبوب امت سے بات کرتا ہے تو جو استعارے اور تشبیہات استعمال کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے میری محبوب امت! تو بدکار عورت کی طرح جگہ جگہ جا کر آشنائیاں کیوں کرتی ہے؟یہود و نصاریٰ سے اللہ تعالیٰ جب خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بدکار عورت کی طرح جگہ جگہ آشنائیاں کیوں کرتے پھرتے ہو؟ در در پر جا کر سر کیوں جھکاتے ہو؟ میرے ہو جائو تو میں تمھارا ہوں۔ جب میں تیرا ہوں تو دنیا میں تجھے اور کس کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اگر ہم اس کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو کتنا ہی ہم سر مار لیں‘کوشش کر لیں‘ اُسی کے بن جانے اور اُسی کی محبت میں غرق ہوئے بغیر یہ راہ طے نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو اس بات کا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے کہ اگر تم نہیں تو پھر دوسری قوم لائوں گا اور سب سے بڑھ کر اُن کی پہلی صفت یہی ہو گی کہ وہ محبت کی زندگی گزاریں گے‘ میں اُن سے محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ باقی صفات کا ذکر تو بعد میں آتا ہے سب سے پہلے یہ ہے ‘ اس کے بعد ہی وہ کام کر سکیں گے جو اُن کے سپرد کیا گیا ہے۔
محبت کوئی اجنبی چیز تو نہیں‘ جانی پہچانی چیز ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ محبت کیا ہوتی ہے توکوئی اس طرح بتا نہیں سکتا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ لیکن کس کو ان میں سے ہرچیز کا تجربہ نہیں ہے۔ محبت ہوتی ہے تو اُسی کی طرف دھیان لگا رہتا ہے‘ اسی کا خیال رہتا ہے‘ اُسی کا نام زبان پہ رہتا ہے۔ اُس سے ملاقات کے لیے جو موقع مل جائے غنیمت ہوتا ہے۔ اگر پانچ وقت مل جائے تو اس سے بڑھ کر محبت کرنے والے کی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ خود بلائے ‘ دروازہ کھول دے‘ یہ تو اس کا بہت بڑا قُرب دینے اور قریب کرنے کا اعلان ہے۔ جب اُس سے روبرو ملاقات کی گھڑی آئے تو اُس سے ملاقات کا شوق اسی محبت کی علامت اور نشانی ہے۔ پھر جو کام کریں اس طرح کریں کہ اُس کو خوش کر دیں۔ انسان دُھن میں لگا ہو توکسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ خود ہی دُھن میں لگا رہتا ہے۔ دھیان اسی میں لگا رہتا ہے اور ایسے ایسے کام بھی کرتا ہے جو محبوب نے فرض اور لازم نہیں کیے۔ جو فرض کیے وہ تو بجا لاتا ہے مگر جو فرض نہیں کیے اُن کے پیچھے بھی لگا رہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر تو قربت کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ۔ کہاں سے‘ کس طرح‘ کون سا ایسا موقع مل جائے جس سے اُس کو خوش کر دوں اور اس کے قریب ہوتا چلا جائوں۔
یہ سب محبت کی وہ علامتیں ہیں جو سب جانتے ہیں۔ دل میں ایک آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ کے اندر سب تعلقات بھسم ہو جاتے ہیں۔ایک ہی تعلق طاری رہتا ہے اور دل کے اوپر چھاجاتا ہے۔ یہ سب نشانیاں آپ جانتے ہیں۔ اس کی میزان میں رکھ کے اپنے دل کو تول سکتے ہیں۔ اس کی ملاقات ‘ اُس کا ذکر‘ اُس کی یاد‘ اُس کی رضا‘ اُس کی خوشنودی کی کوشش زندگی کے اندر کتنی ہے‘ خود اپنے اندر پیدا کریں ‘ جو ساتھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں‘ دو ہوں ‘چار ہوں یا جتنے بھی‘ ان کے اندر پیدا کریں ‘ آپ کا اور آپ کے کام کا نقشہ بدل جائے گا۔ وہی کام جو آپ ٹہل ٹہل کر کرتے ہیں‘ وہ دوڑ دوڑ کر کریں گے۔وہی زبانیں جو دعوت کے لیے نہیں کھلتیں ‘ وہ کھلنے لگیں گی‘ اس لیے کہ پھر میں خود زبان بن جاتا ہوں۔ وہی پائوں جو اب نہیں اُٹھتے‘ وہ اٹھنے لگیں گے‘ اس لیے کہ وہ ہاتھ میں خود بن جاتا ہوں۔ وہی ہاتھ جو کام نہیں کرتے‘ وہ کام کرنے لگیں گے اس لیے کہ وہ پائوں میں خود بن جاتا ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جب آدمی دوڑ دوڑ کے اس کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک مختصر سی دعا حدیث میں آتی ہے کہ:
رَبِّ اجْعَلْنِیْ لَکَ ذَکَّارًا لَکَ شَکَّارًا لَکَ رَھَّابًا لَکَ مِطْوَاعًا لَکَ مُطیْعًا اِلَیْکَ مُخْبِتًا اِلَیْکَ اَوَّاھًا مُّنِیْبًا (ترمذی‘ عن ابن عباسؓ)
اے میرے اللہ‘ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے بہت یاد کروں‘ تیرا بہت شکر کروں‘ تجھ سے بہت ڈرا کروں‘ تیری بہت فرمانبرداری کیا کروں‘ تیرا بہت مطیع رہوں‘ تیرے آگے جھکا رہوں‘ اور آہ آہ کرتا ہوا تیری ہی طرف لوٹ آیا کروں۔
یہ سب محبت کی تصویریں ہیں:خوب ہروقت مجھے یاد کرو۔ ہر وقت میرا شکر کرتے رہو۔ خوف بھی ہو‘ محبت بھی۔ محبت اور خوف کا ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے‘ پتا نہیں کب یہ محبت چھن جائے۔ اس کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو محبوب کو ناگوار گزرے۔یہ کوڑے کا خوف نہیں ہوتا بلکہ یہ خوف اس کا ہوتا ہے کہ نہ جانے کب کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے میرا محبوب‘ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ دوڑ دوڑ کر تیرے کام کروں۔ جو فرض نہیں ہیں وہ بھی کروں۔ لَکَ مُطیعًا تیرا بہت مطیع رہوںاور لَکَ مُخْبِتًا اور تیری طرف جھکا رہوں اور ہائے ہائے واہ واہ کرکے تیرے در پہ لوٹ آیا کروں۔
حبیب کے حبیبؐ نے فرمایا کہ اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ اس کے انعامات تم پر بے پایاں ہیں اور مجھ سے اللہ کے لیے کرو (ترمذی)۔ جو اللہ کا حبیب ہے ‘ اللہ نے اس کو اپنے کام کے لیے بھیجا ہے۔ اُس کے ذریعے اُس نے ہم پر اپنی ساری نعمتیں تمام کر دیں۔ قرآن مجید‘ اپنا دین ‘ اپنی ہدایت‘ اپنی جنت کاراستہ اور جہنم سے بچنے کا راستہ ‘ سب کچھ اُنہی کے ذریعے ملا ہے۔ ان سے محبت کا تو یہ عالم تھا کہ لوگ نگاہ بھر کر دیکھ نہیں پاتے تھے۔ مجلس میں سناٹا رہتا تھا۔ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا تھا۔ تھوکتے تھے تو چاہنے والے وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ بھی محبت کی علامتیں تھیں۔ ان میں سے کوئی چیز فرض نہیں تھی۔ کسی چیز کا دین میں مطالبہ نہیں تھا۔ ایک آدمی آیا اور اس حال میں آپؐ سے ملا کہ آپؐ کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ عمر بھر باپ اور بیٹے نے اپنے گریبان کے بٹن بند نہیں کیے۔ دین کا کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ ایسا کرنا ضروری ہے۔ ایک اور آدمی آیا اس نے دیکھا کہ آپؐ کی چپل کے تسموں پر بال ہیں۔ اُس نے ہمیشہ وہی چپل پہنے۔ ایک اور آدمی آیا اس نے دیکھا کہ آپؐ سالن میں کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے ہاں کبھی کوئی سالن نہیں پکا جس میں کدو نہ ڈلا ہو اور اس میں کدو کے ٹکڑے نہ تلاش کیے ہوں۔ اُن میں سے کوئی چیز بھی فرض نہیں تھی۔ اور جو چیزیں فرض کیں‘ جن کا مطالبہ کیا---مکے کی گلیاں ‘ عکاظ کے میلے‘ طائف کی وادی‘ بدر و حنین کے میدان--- بھلا جو قمیض کے بٹن بھی بند نہ کرتے ہوں‘ کدو کے ٹکڑے بھی نہ چھوڑتے ہوں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اِن میں پیچھے رہ سکتے ہیں؟ پھر انھوں نے اسپین سے لے کر چین تک سب کو بدر و حنین کا میدان بنا دیا۔ جو کام قومیں ہزاروں برس میں کرتی ہیں‘ وہ کام انھوں نے سوبرس میں کر دیا۔ یہ اِسی محبت کا نتیجہ ہے۔ یہی محبت تو اُن کا سارا سرمایہ تھی۔ ہر دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپؐ کے دل کا ایک ٹکڑا آگیا۔ ہر شخص چلتا پھرتا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بن گیا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے آگے قوموں کی قومیں ‘شہروںکے شہر او ر ملک کے ملک سپرانداز ہو گئے اور بچھتے چلے گئے۔ اس لیے کہ محبت فاتحِ عالم ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت اور اس کے رسولؐ کی محبت یقینا سارے عالم کو فتح کر لیتی ہے۔ آپ ؐ کے پاس اس کے سوا کوئی اور نسخہ نہیں تھا۔ نہ وعظ تھے‘ نہ لٹریچر تھا‘ نہ کتابیں تھیں‘ کچھ نہیں تھا‘ بس محبت کی تفسیر تھے‘ زندہ چلتی پھرتی تصویر تھے۔
ایک آدمی آیا۔ اُس نے پوچھا قیامت کا دن کب آئے گا؟ فرمایا پوچھ تو رہے ہو‘ کچھ تیاری بھی کی ہے؟ کہا نہیں۔ نماز روزے‘ یہ تو بہت مشکل ہیں۔ صرف اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا جس سے محبت کرتے ہو اُسی کے ساتھ رہوگے۔ حضرت انسؓ بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے صحابہؓ کی زندگی میں اس سے زیادہ خوشی کا کوئی دن نہیں دیکھا کہ جب یہ خوشخبری سُنی کہ نمازیں بھی کم ہیں‘ روزے بھی کم‘ کوئی وسیع سرمایہ ساتھ نہیں ہے‘ بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ بشارت ملی کہ پھر تو قربت بھی ہے‘ ساتھ بھی ہے اور پاس بیٹھنا بھی ہو گا اور ملنا جلنا بھی ہو گا۔
کسی نے کہا کہ آدمی محبت تو کرتا ہے مگر پہنچ نہیں سکتا۔ پہنچ نہ سکناتو بہت بلیغ بات ہے۔ ۱۴ سو برس کے زمانے کا فاصلہ ہے۔ مکان کا بھی فاصلہ ہے۔ بہت دور ہے جا نہیں سکتے۔ عمل کا بھی فاصلہ ہے کہ ہمارے عمل کی اُن کے عمل کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ فرمایا کہ محبت تو ایسا نسخہ ہے کہ ساری دوریوں اور فاصلوں کے باوجود آدمی اُسی کے ساتھ جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپؐ کے پیچھے چلنا اللہ کی محبت کی کسوٹی ہے۔یہ محبت کا سیدھا راستہ ہے۔ قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمُ اللّٰہُ (آلِ عمران۳: ۳۱)۔ ’’اے نبیؐ ، لوگوں سے کہہ دو کہ ’’اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو‘ اللہ تم سے محبت کرے گا‘‘۔اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلو اور میرے بن جائو‘ میرے نقشِ قدم پر چلو‘ جن راستو ں سے میں گزرا ہوں‘ اُن سب سے گزرو۔ اگر میں کہوں کہ مکہ کی گلیوں سے گزرو‘ عکاظ کے میلوں سے گزرو‘ طائف کی وادی سے گزرو اور بدر و حنین کے میدان سے بھی گزرو‘ تو ان سب مقامات سے بلاجھجک گزرواس لیے کہ یہی محبت کا تقاضا ہے۔
اتّباع کے معنی اطاعت کے نہیں ہیں۔ اطاعت کا لفظ الگ ہے۔اطاعت کے معنی تو کہنا ماننے اور حکم ماننے کے ہیں‘ اور اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں۔ پیچھے پیچھے تو ہر آدمی چلا جائے گا‘ محبوب جدھر جائے گا اُس کے پیچھے جائے گا۔ جہاں وہ چلا ہو گا اس کے پیچھے چلے گا۔ جو نقشِ قدم اُس نے چھوڑے ہوں گے اُنہی کو وہ پیار کرے گا انہی کے اوپر وہ اپنے قدم بھی رکھے گا۔
یہ محبت بھی آسانی سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ایک واقعہ آپ نے بھی پڑھا ہو گا‘ میں نے بھی پڑھا ہے۔ پڑھ کے دل لرز جاتا ہے اور بڑی محبت بھی پیدا ہو تی ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ زخموں سے چور اور جان بہ لب تھے۔ محبت میں یہاں تک پہنچ گئے۔ آپؐ کے پاس بھی لائے گئے۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپؐ اپنا پائوں میرے چہرے پر رکھ دیں۔ لوگ تو بڑے دعوے کرتے ہیں محبت کے‘ لیکن حضورؐ کے قدموں کے نیچے آنے کے مقام تک پہنچنے کے لیے اس کیفیت میں ہیں کہ پورا جسم خونم خون‘ زار و نزار‘ جان لبوں پر ہے تو اس کے بعد انھوں نے اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھا یا محبت میں یہ آرزو ہوئی کہ قدمِ مبارک چہرے کے اوپر ہوں۔ یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔
وہ لوگ جو دین کے راستے پر ساتھ چل رہے ہیں ان کے لیے اس میں بہت رہنمائی ہے۔ آپ ؐنے فرمایا کہ اپنے آپ کو باندھ لو‘ اس کے ساتھ جمالو‘ جم جائو‘ ناگواریاں بھی ہوں تو صبر اختیار کرو۔ وَلَا تَعْدُ عَیْنٰکَ عَنْہُمْج (الکھف ۱۸:۲۸) ’’اور اُن سے ہر گز نگاہ نہ پھیرو‘‘نگاہیں ہٹنے نہ پائیں۔ یہی ساتھی سرمایہ ہیں۔کچے بھی ہیں اور پکے بھی۔ گناہ گار بھی ہیں اور نیک بھی ‘پُختہ بھی ہیں اور ناپختہ بھی ہیں۔ جو بھی ہیں وہ سب جو ساتھ چل رہے ہیں‘ ان میں سے ہر شخص قیمتی ہے۔ ہر شخص ایک سرمایہ ہے۔ کالے بھی ہیں اور گورے بھی‘ پڑھے لکھے بھی ہیں اور جاہل بھی۔ اچھے اخلاق والے بھی ہیں اور بد اخلاق بھی۔ آکے چادر کھینچ لیتے ہیں‘ بُرا بھلا کہتے ہیں‘ طعنے دیتے ہیں پھر بھی وہ محبوب رہتے ہیں۔ عذر پیش کرتے ہیں وہ قبول کر لیے جاتے ہیں۔ غلطی کرتے ہیںتو معاف کر دیے جاتے ہیں اورسینے سے لگا لیا جاتا ہے۔کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی دھتکار کے باہر کر دیا گیا ہو۔
یہی تو وہ لوگ ہیں جن سے کام ہونا ہے۔ انھی کی تائید سے تو دین غالب ہوا۔ ھُوَ الَّذِیْٓ اَیَّدَکَ بِنَصْرِہٖ وَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ o (الانفال۸:۶۲) ’’وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمھاری تائید کی‘‘۔ یٰٓاَیُّھَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللّٰہُ وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَo (الانفال ۸:۶۴) ’’اے نبیؐ ، تمھارے لیے اور تمھارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے ‘‘۔
یہ مومنین کی جماعت ہی تو ہے جس کی جدو جہد سے پورا کا پورا دین نافذ ہوگا‘ فتنہ مٹے گا اور دین کا کلمہ غالب ہو گا۔ ان میں سے تو ہر شخص بڑا قیمتی ہے۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کی قدر و قیمت کم کی جائے۔ ہر شخص کا دل اللہ کی یاد کا مسکن ہے۔یہ تو خانۂ کعبہ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ خانۂ کعبہ کیا ہے؟ مٹی کا گھر ہے۔ یہ تو گوشت کا دل ہے جو اللہ نے خود بنایاہے۔ جس میں وہ خود بستا ہے۔ اس کی یاد بستی ہے۔ اس کی محبت بستی ہے۔ اس کا ایمان بستا ہے۔ اس کی ناقدری کی جائے اور اس کو آدمی جھڑک دے‘ اس کو ایذا پہنچائے‘ اس کو تکلیف دے‘ اس کی پروا نہ کرے ‘ اس کی برائی کرتا پھرے‘ اس کوگالی دے‘ اس کا مذاق اڑائے‘ یہ کیسے ہو سکتا ہے! اسی لیے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اُس نے مجھے خوش کیا۔ جس نے مجھے خوش کیا اُس نے اللہ کو خوش کیا۔ جس نے کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھ ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ آپ بتائیے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ محبوب ہوں تو کیا اس کے بعد اب کسی ہدایت کی ضرورت ہے؟ یہ تو خود اپنی جگہ پر کافی ہے۔ جب اللہ پیارا ہے‘ اللہ کے محبوبؐ پیارے ہیں تو پھر اللہ کے کسی بندے کو‘ اپنے کسی ساتھی کو کیسے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی بات زبان پر کیوں آئے‘ ہاتھ سے ایسا کام کیوں ہو‘ روش ایسی کیوں ہو جس سے اُس کو تکلیف ہو۔جن کو ہم نے آگے کھڑا کر دیا ہے وہ بھی اُسی طرح محبوب ہیں‘ اور جو ہمارے پیچھے ہیں وہ بھی اسی طرح محبوب ہیں۔ یہ محبت کا رشتہ ہے۔
اب کوئی آگے چلنے والا یہ حق تو نہیں رکھتا کہ وہ کہہ سکے کہ میں تمھاری جان ‘مال ‘ والدین سب سے زیادہ پیارا ہوں۔ یہ مقام تو صرف اللہ کے رسولؐ کے لیے۔ لیکن اِسی کا کچھ حصّہ کہیں نہ کہیں تو آئے گا جس سے جماعتیں مضبوط ہوں گی اور ایران و روم فتح کرنے کے قابل ہوں گے۔ خشک احتساب جماعتوں کو صحیح تو رکھ سکتا ہے‘ مگر اُن کے اندر سیلاب کی وہ قوت نہیں پیدا کر سکتا کہ دنیا کے اوپر چھا جائے۔ یہ سیلاب کی قوت تو محبت ہی پیدا کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رحما کی مثال دی ہے ‘ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ ط وَالَّذِیْنَ مَعَہٗ ٓ اَشِدَّآئُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَآئُ بَیْنَھُمْ (الفتح ۴۸:۲۹) ’’محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں‘‘۔ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ بیج کونپل بنی‘ درخت بنا اور پھر تناور درخت بن گیا۔ آپس کی محبت اور رحمت پر مبنی اس کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت کے سیمنٹ سے جڑی ہوئی ہیں۔وہی جماعت اس قابل ہے کہ اس کا ننھا منا بیج تناور درخت بن جائے۔ عام انسان‘ہر انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا‘ گوشت پوست کا انسان جس کے اندر اس نے اپنی روح پھونکی ہے (نفختُ فیہ من روحی)۔ ہر انسان جو گناہ گار ہے‘ اس کا گناہ آپ کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو‘ نفرت کا مستحق نہیںہے۔ گناہ گار بھی آتے تھے‘ جانی دشمن بھی آئے‘ چچا کا کلیجہ چبانے والے بھی آئے‘ مکے کے پورے ۱۳سال گالیاں دینے والے‘راہ میںکانٹے بچھانے والے بھی آئے‘ مرد بھی آئے‘عورتیں بھی آئیں‘ بیٹی کے اوپر برچھا مارنے والا جس کے نتیجے میں اُن کا اسقاط حمل ہوگیا وہ بھی آیا‘ سب کو گلے سے لگا لیا اور سب سے کہا کہ آئو آج سے تم میرے بھائی ہو اوروہی پھر قوت بن گئی۔
وہ چند افراد کی قوت نہیں تھی۔ مہاجرین و انصار نے ساری دنیا فتح کی۔وہ تو لیڈر تھے ‘ قائد تھے‘وہ آگے چلنے والے تھے۔ انسانی قوت تو ان سے آئی جن کے دلوں کو اونٹ دے کر اور مالِ غنیمت دے کر جیتا گیا۔
فرمایا کہ بھوکے کے پاس جائو تو اپنے رب کو وہاں پائو گے۔ تم اسے کہاں تلاش کرتے پھرتے ہو؟ پیاسے کے پاس جائو تو مجھے وہاں پائو گے‘ اور بیمار کے پاس جائو تو مجھے وہاں پائو گے۔ تم مجھے کہاں تلاش کرتے ہو؟ مجھے بندوں میں تلاش کرو۔ ان کے پاس جائو گے‘ ان سے محبت کرو گے تو پھر وہ تمھارے ہو جائیں گے اور تم اُن کے ہو جائو گے۔
میرے بھائیو اور دوستو! یہ بنیادی سبق ہے۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ حمد کا کلمہ بھی محبت کا کلمہ ہے۔ شکر اور تعریف محبت کے بغیرنہیں ہوسکتی اور محبت تو شکر کے بیج سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی اسی کلمے سے فرمایا: الحمد للّٰہ۔ اورجب دین تکمیل تک پہنچ گیا تو پھر فرمایا: فسبّح بحمد ربک۔ شکر ہی تو محبت کا بیج ہے۔ اِسی سے محبت کا درخت پھوٹتا ہے‘ اس کی شاخیں نکلتی ہیں‘ پتے آتے ہیں‘ پھول کھلتے ہیں‘ پھل نکلتے ہیں۔ یہ دین کی بنیاد ہے‘ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کی راہ عشق و محبت کی راہ ہے اور اسی سے یہ منزل آسان ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نسخہ میں نہیں جانتا۔
میں پھر اپنی بات دُہرائوں گا کہ تم اگر اس معیار پر پورے نہیںاترو گے تو پھر تمھارے ہاتھوں سے یہ کام نہیں ہو گا۔ پھر اللہ دوسرے لوگ لائے گا۔ فَسَوْفَ یَاْتِی اللّٰہُ بِقَوْمٍ (المائدہ ۵:۵۴) ’’وہ دوسری قوم لے کر آئے گا‘‘۔ اور اس گروہ کی پہلی خصوصیت ہی ہو گی کہ وہ اللہ کی محبت کے نشے میں سرشار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہو گا۔ اس کے بعد سارے کام آسان ہوں گے‘ دین غالب ہو گا‘ پھر زندگی ٹھکانے لگے گی۔ پھر تھوڑے عمل سے بھی بڑے بڑے نتائج پیدا ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اسی محبت کا حصّہ عطا فرمائے۔ (کیسٹ سے تدوین: م - س)
’’ضمیر‘‘ اُس خالق مطلق و علیم و حکیم کی ایسی محیرالعقول اور پُراسرارتخلیق ہے کہ آدمی اس میں جتنا بھی غور کرے‘ گم کدئہ فکروتخیل میں اتنا ہی ششدر و دنگ ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہ حیرت کدہ ہے جس میں قوسِ قزح کے رنگ‘ کہکشانوں کی وسعت‘ سمندروں کی گہرائی اور آسمانوں کی گیرائی‘ فکروخیال کو کائنات اور ماوراے کائنات میں دعوتِ پرواز اور لذتِ نظارہ دیتے ہیں۔
خالق موجودات نے آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ:
فَاِذَا سَوَّیْتُہٗ وَنَفَخْتُ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سٰجِدِیْنَ o (صٓ ۳۸:۷۲) اور پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جائو۔
روح جب جسدِعنصری سے پرواز کر جاتی ہے‘ یعنی جان نکل جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اُس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔
لیکن ’’ضمیر‘‘کیا ہے! اِسے نہ انسان کے قالب میں پھونکا گیا‘ نہ ہم اسے کسی ایسی شے سے تعبیر کرسکتے ہیں‘ جس کے نکل جانے سے انسان کی موت واقع ہو جائے۔ اِس کے باوجود ضمیر کوئی ایسی شے ہے جو ہمہ دم انسان کے باطن میں نیزے کی اَنی کی طرح کچوکے دیتی‘ چھیڑچھاڑ کرتی اور مسلسل اپنی موجودگی کا اعلان کرتی رہتی ہے۔
اقبال کا کہنا ہے ؎
بانگِ اسرافیل اُن کو زندہ کر سکتی نہیں
روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد
روح وہ شے ہے جو خاک کے پنجر میں پھونکی گئی تو وہ جی اُٹھا۔ اِسی سے تارِنفس قائم ہے۔ اگر جسد روح سے تہی‘ یعنی خالی اور محروم ہو گیا تو زندگی بھی ختم ہو گئی۔ لیکن وہ کون سی کیفیت ہے کہ ’’زندگی‘‘ تو قائم ہے مگر ’’روح‘‘ سے تہی ہے۔ لیکن یہ ’’زندگی‘‘ ایسی ’’موت‘‘ سے بدتر ہے جو صورِاسرافیل سے بھی بیدار ہونے کی اہلیت سے عاری ہے۔ گویا ’’زندگی‘‘ اور ’’موت‘‘ بیک وقت ایک جسد میں جمع ہیں۔
ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اِس لیے ثابت ہوا کہ یہ تعبیر کسی ایسے جوہر کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی حقیقت ہی حیات بخش زندگی ہے۔ اِسی کے ہونے سے زندگی،’’زندگی‘‘ کہلاتی ہے۔ اور اِس جوہر کا نام ’’ضمیر‘‘ ہے۔
۱- نفسِ اَمّارہ: وہ نفس جو ہمیشہ خودسری‘ سرکشی اور جرم کی آماجگاہ ہو۔ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَۃٌم بِالسُّوْٓئِ اِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّیْ ط (یوسف ۱۲:۵۳) ’’بے شک نفسِ امارہ تو برائی ہی کی طرف مائل ہوتا ہے‘ الا اُس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے‘‘۔
۲- نفسِ لوّامہ: ’’نفس ملامت گر‘‘ جس کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اُس کی قسم کھائی ہے: وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَۃِ o (القیامہ ۷۵:۲)’’اور نہیں‘ میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی‘‘ (برائی سے دامن بچانے کے لیے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے)۔ نفسِ لوامہ یا نفسِ ملامت گر‘ یہ ہے کہ بندے سے عملِ خیر صادر ہو تو اُس پر اِترانے کے بجائے اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں خلوصِ نیت یا تکمیلِ کار میں خامی نہ رہ گئی ہو۔ اور اگر کوئی لغزشِ پا یا معصیت سرزد ہو جائے تو اُس پر نادم و سرنگوں ہو تاکہ توبہ اور تلافی کی توفیق نصیب ہوسکے۔
۳- نفسِ مطمئنہ: وہ نفس ہے جو نہ خیالاتِ شیطانی سے متزلزل ہوتا ہے ‘ اور نہ نفسانی تحریکات سے منتشر ‘ بلکہ جس کا اپنے اللہ اور اُس کے دین پر ایقانِ کامل اور اُس کی اطاعت و بندگی غیرمتزلزل ہوتی ہے‘ اُس کے لیے بشارت ہے کہ: یٰٓاَیَّتُھَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۃُ o ارْجِعِیْ ٓ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَۃً مَّرْضِیَّۃً o (الفجر ۸۹:۲۷-۲۸) ’’اے نفسِ مطمئن‘ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو (اپنے انجامِ نیک سے) خوش اور (اپنے رب کے نزدیک) پسندیدہ ہے‘‘۔
چنانچہ ’’ضمیر‘‘ وہ احساسِ شعورِ باطنی اور نفسِ لوامہ کے نفسِ مطمئنہ کی طرف عروج کی منزل‘ اور ایک طرح سے دونوں کا حسین امتزاج ہے جو انسان کو اپنے وجود‘ اپنی خودی‘ اور عزتِ نفس کی یاد دلانے کے لیے اپنے ارتعاشِ نبض سے تازیانے کی طرح ضرب لگاتا رہتا ہے۔ وہ شرر ہے‘ جو اُس کے اندر ایمان کی لَو روشن رکھتا اور اُس کی حدت و توانائی کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ اُسے خیر کی طرف متوجہ‘ اور شر سے متنبہ کرتا ہے۔ ضمیر وہ قوت ہے جو صبرواستقلال کی طرف رہنمائی کرتی اور رَیب و گمان اور لغزش و کج روی سے روکتی ہے۔ گویا ’’ضمیر‘‘ حریمِ قلب میں وہ آئینہ ہے جو عکسِ خیال کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے‘ اور اُس کے اسباب و نتائج کے امکانی نشیب و فراز سے صاحب ِ خیال کو آگہی عطا کرتا اور اُن کے مضمرات کی فہمایش کرتا اور اُسے راہِ راست پر گام زن رکھتا ہے۔
اِس لحاظ سے ’’ضمیر‘‘ گویا روح کی ’’روح‘‘، یعنی اُس کی جان اور اُس کی بالیدگی اور شادابی حیات کا باعث ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ’’ضمیر‘‘، نفسِ لوا مہ سے اِرتقا پذیر ہو کر’’نفس مطمئنہ‘‘ کے مقامِ ارفع و اعلیٰ پر فائز ہوجاتا ہے۔ جہاں وہ اپنے رب کے قرب سے خوش‘ اور اُس کا رب‘ اُس کے ایمان و اطاعت سے راضی ہوتا ہے۔ یہ وہ فردوسِ اطمینان ہے جس کی جستجو میں بندے نے خُلدِبریں سے اخراج سے لے کر اَن گنت صدیاں گزاری ہیں۔
جس طرح ضربِ دل‘ جسم کی زندگی کی علامت ہے‘ اُسی طرح ضربِ ضمیر‘ انسان کی روحانی اور ذہنی صحت کا عنوان ہے۔ اقبال نے کہا ہے ع
دلِ مُردہ دل نہیں ہے اِسے زندہ کر دوبارہ
گویا دل کا دھڑکنا‘سانس کا آنا جانا اور انسان کا چلنا پھرنا ہی زندگی کا ثبوت نہیں ہے‘ اِس کے لیے کسی اور شرر کی ضرورت ہے۔ دل کی موت دراصل ضمیر کی مرگ اور احساس کی موت ہے‘ اور یہ اُسی وقت واقع ہو جاتی ہے جب خاکستر کی چنگاری بجھ جائے‘ اللہ کی حاکمیت پر یقین نہ رہے اور ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اُس وقت گویا انسان کا اللہ سے اپنی عبودیت کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے‘ اور نہ صرف دل کی موت واقع ہو جاتی ہے‘ بلکہ اگر احساسِ زیاں بھی جاتا رہے تو ضمیر کی موت بھی ناگزیر امر ہے۔ اور موت کی یہی کیفیت ہے جس سے بقول اقبال بانگِ اسرافیل بھی بیدار نہیں کر سکتی۔
جب ایسا ہوتا ہے تواِلٰہ واحد کی جگہ‘ سیکڑوں مرئی اور غیر مرئی ’’خدا‘‘ اقلیمِ دل پر کسی مافیا کی طرح قابض ہو کر اُس کی کل گھمانے لگتے ہیں۔ آدمی زندہ ہوتے ہوئے بھی ہمہ دم موت سے ڈرنے لگتا ہے۔ ایمان و یقین کے سرچشمے خشک ہونے لگتے ہیں۔ آدرش اور اصول کے قلعے مسمار ہو جاتے ہیں۔ عزم و استقلال اور ہمت و استقامت کی فصیلیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور ’’جان‘‘ بہت عزیز ہوجاتی ہے حالانکہ اِس سے زیادہ ناپایدار اور کوئی شے عالمِ وجود میں موجود نہیں‘ یعنی ابھی ہے‘ ابھی نہیں ہے۔ ’’ہرچند کہیں کہ ہے‘ نہیں ہے!‘‘
کُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فَانٍo وَّیَبْقٰی وَجْہُ رَبِّکَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ o (الرحمٰن ۵۵:۲۶-۲۷) ہر چیزجو اس زمین پر ہے فنا ہوجانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔
گویا سلطنتیں‘ عمارات و عجائبات‘ جہاز‘کارخانے ‘ تکنیکی مہارت‘ سائنسی ایجادات‘ میزائلیں‘ ایٹمی اثاثے‘ قلعے‘ جاہ و حشمت‘ عظمت و سطوت‘ شوکت و تمکنت‘ انسان کی بالادستی بلکہ ’’خدائی‘‘ کا تزک و احتشام‘ حتیٰ کہ چاند ستارے‘ سورج‘ کہکشائیں اور کائنات کی ہر شے فنا پذیر ہے--- اور صرف اللہ کی ذات--- عظمت و اِکرام والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔
خلافت ِ ارضی کے مقام سے اس ذہنی تنزل کا تلازم یہ ہے کہ انسان ’’جان‘‘ کے ’’فریبِ تحفظ‘‘ میں ’’زمینی حقائق‘‘ کے نام پر حمیت و غیرت اور ننگ و ناموس سے بھی دست بردار ہو جاتا ہے۔ ایمان و عبودیت‘ عہد و اقرار اور حلف و قَسم کے ساتھ یہ سب اور صدیوں کی تمدنی‘ تہذیبی اور تاریخی اقدار، ’’روایاتِ پارینہ‘ بنیاد پرستی اور رجعت پسندی‘‘ کی علامت بن کر گردن زدنی ٹھہر جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ انسان جبلی طور پر ہر شے سے کٹ کر نہیں رہ سکتا‘ کسی نہ کسی قسم کا تعلق بہرحال ضروری ہے‘ اِس لیے اور نہیں تو مٹی کے در و دیوار‘ اسباب بود وباش اور سازوسامانِ آسایش ہی محورِ زندگی بن جاتے ہیں۔
یہی جبلت پتھر اور دھات کے زمانے میں تو کیا‘ آج بھی کمزور دل اور وہم و گمان کے شکار انسان کو اپنے ہاتھوں پتھر اور مٹی سے بنائے ہوئے خدائوں (بتوں) کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ کبھی چاند اور سورج جیسے مظاہرِفطرت کی‘ جو اُسے اپنے سے طاقت ور نظر آتے ہیں‘ پرستش پر مائل کردیتی ہے۔ اور دورِ حاضر کی اصطلاح میں‘ احساسِ کمتری بن کر‘ چڑھتے سورج کی طرح جابر و قاہر قوموں کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔
یہ درست ہے کہ ’’جان‘‘جانے کے بعد بھی انسانی زندگی کے مادی آثار دیدۂ عبرت نگاہ کی سبق آموزی کے لیے کچھ مدت تک باقی رہتے ہیں‘ لیکن تابہ کے۔ ایک دن یہ بھی ملیامیٹ ہو جائیں گے۔ یہ سارا مال و اسباب اور سازوسامان نہ تو بالآخر اِس دنیا میں اُن فریب خوردگانِ جان عزیز کے کام آئے گا‘ جنھوں نے ’’اپنا سب کچھ بچا لینے‘‘ کے وہم و گمان میں اس چند روزہ حیاتِ مستعار میں قلب و ضمیر‘ ایمان و یقین اور غیرت و حمیت کی سوداکاری کی تھی اور نہ وہ اُسے اپنے ساتھ ہی لے جا سکیں گے‘ جس طرح ع
سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے
اِسی حقیقت کی روشنی میں حکیم الامت علامہ اقبال نے اپنی خداداد حکمت و دانش اور بصیرت کی بنا پر ملت کو یہ فہمایش مناسب سمجھی ؎
یہ مال و دولتِ دنیا‘ یہ رشتہ و پیوند
بتانِ وہم و گماں! لا الٰہ الا اللہ
اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلافت ِ ارضی کے اعزاز سے سرفراز کیا تو اُس کی مستقل ہدایت و رہنمائی کے انتظام کے ساتھ‘ راستے کے نشیب و فراز سے بھی آگاہی بخشی۔ اُسے ازل سے بہ ہر نفس ابلیس کے حسد و عداوت‘ مکروفریب اور ترغیب و تحریص کے امتحان کا سامنا ہے اور یہ چیلنج مختلف زمانوں میں نئے نئے انداز سے اُسے درپیش رہتا ہے۔
ایک دَور میں ساری دنیا کے سر پر اشتراکیت کا بھوت سوار تھا۔ اور اس میں شک نہیں کہ وہ مسلم اقوام اور ملت ِ اسلامیہ کے لیے بھی ایک فتنۂ عظیم تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑا اور خطرناک سفید استعمار و استحصال کا وہ فتنہ ہے جس سے ہم گذشتہ چند صدیوں سے دوچار ہیں۔ اس استعمار کا مفاد جب تک تھا‘ اُس نے اشتراکیت کے خلاف ملت ِ اسلامیہ کو استعمال کیا‘ اور ہم اپنی سادگی‘ حماقت یا عارضی شخصی مفادات کی بنا پر اُس کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے۔ لیکن مغربی اقوام جانتی تھیں کہ اُن کو اصل خطرہ اشتراکیت کے فلسفۂ شکم پروری، ’’روٹی‘ کپڑا اور مکان‘‘ سے نہیں بلکہ مسلمان کی اُس قوتِ ایمان سے ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی‘ اور جس کے لیے مادی وسائل زندگی بسر کرنے کا ذریعہ تو ہیں‘ لیکن مقصد ِ زیست نہیں۔ مغربی استحصالی قوتیں ہی کیا اُن کے گرو ’’جارج ابلیس‘‘ پر بھی یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح تھی۔ چنانچہ اُس نے اپنے مریدوں‘ مشیروں اور کولیشن (colaition) پارٹنروںکو بشمول اشتراکی قیادت کے‘ بہت پہلے متنبہ کر دیا تھا:
ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اُس اُمت سے ہے
جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو
جانتا ہے‘ جس پہ روشن باطنِ ایام ہے
مزدکیت فتنۂ فردا نہیں‘ اسلام ہے!
سفید استعمار نے جب دیکھا کہ دنیا کی ایک چوتھائی آبادی کے حامل ملک چین کو زیر کرنا مشکل امر ہے‘ تو انھیں افیم کی لت ڈال دی‘ تاکہ اُن کی غیرت و حمیت اور ضمیر ایک طویل خوابِ خرگوش کی مدہوشی میں اپنی حقیقت فراموش کر دے۔ تاہم اب تک برعظیم کے مسلمانوں پر متحدہ قومیت اور تصورِ وطن سمیت کسی افیم کا حربہ کارگر نہ ہو سکا تھا۔
اب کہ ’’گراں خواب چینی‘‘سنبھل کر نہ صرف ہوشیار بلکہ دنیا کی ایک عظیم طاقت بن چکے ہیں‘ اور ’’مزدکیت‘‘ کا بت ٹوٹ چکا ہے‘ کیا ہم نے ’’فتنۂ فردا‘‘ سے ترقی کر کے ’’فتنۂ امروز‘‘ کی حیثیت اختیار کر لی ہے؟ کہ زمانہ لوحِ جہاں سے ۵۸ مسلم ممالک کا وجود حرفِ مکرر کی طرح مٹا دینے کے درپے ہے؟
ہم کہ تیغوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے تھے‘ ستاروں پر کمندیں ڈالتے تھے اور آسماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے تھے کہ ہم باطل سے دبنے والے نہیں ہیں! ہمارے فکروخیال میں کیا تبدیلی آگئی ہے کہ ہم اپنی ’’ترکیبِ خاص‘‘ میں قومِ رسول ہاشمیؐ نہیں رہے! بلکہ ’’سب سے پہلے پاکستان‘‘ کا نعرہ لگا کر امریکہ کی خدائی کے ساتھ اُن تازہ خدائوں میں سب سے بڑے خدا ’’وطن‘‘ کی زلف گرہ گیر کی غلامی بھی قبول کر بیٹھے ہیں۔
’’مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا‘‘ کا فلسفہ غلط تھا؟ یا ہماری کشت ِ خیال بنجرہوگئی ہے؟ آج ’’ترقی یافتہ‘‘ دنیا کے ’’محورِخیر‘‘ کو جس عظیم ترین ’’محورِ شر‘‘ کا سامنا ہے‘ وہ نعوذباللہ اسلام اور مسلمان ہیں؟ افغانستان‘ فلسطین‘ شام‘ کشمیر‘ پاکستان‘ ایران‘سوڈان‘ شیشان‘ بوسنیا ہرزک‘ عراق‘ صومالیہ‘ لیبیا‘ الجزائر‘ تیونس‘ انڈونیشیا بلکہ سعودی عرب تک سب مسلمان ہدف ہیں‘ کوئی آج تو کوئی فردا میں۔
جنوبی سوڈان اور مشرقی تیمور میں ’’دہشت گردی‘‘ نہیں ہو رہی بلکہ (عیسائی) قبائل جنگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور اگر تیسرا سفید فام ملک آسٹریلیا اپنی فوجیں لے کر چڑھ دوڑتا ہے تو یہ بھی عین عملِ خیر اور امنِ عالم کے مطابق ہے‘ لیکن اگر اہل کشمیر‘ اہل شیشان‘ اہل فلسطین اور اہل کوسووا عین اپنے گھروں میں اپنی آزادی کے لیے‘اور وہ بھی اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کے مطابق‘ اپنے نونہال قربان کر رہے ہیں‘ تو یہ دہشت گردی ہے۔
پاکستان میں چند دھماکے دنیا بھر کے ’’دہشت گرد‘‘ اسامہ بن لادن کے سوا کسی اور کی کارستانی نہیں ہو سکتے‘ اور اس کے لیے ۱۴ کروڑ کے اِس ملک کو یرغمال بنا لینا ضروری ہے‘ لیکن گجرات (بھارت) میں ۳ ہزار مسلمانوں کا قتلِ عام چند الفاظ ملامت کا مستحق بھی نہیں ہے۔ اگر اسپین اور آئرلینڈ اِسی خلفشار میں مبتلا ہیں‘ تو یہ اُن کا اندرونی معاملہ خیال کیا جاتا ہے‘ لیکن پاکستان میں کوئی اُونچی آواز سے احتجاج بھی کرتا ہے‘ تو کہا جاتا ہے کہ یقینا بنیاد پرست سرگرمِ عمل ہیں۔
مسلمان جو کچھ بھی کریں اُس کو دہشت گردی‘ بنیاد پرستی‘ تنگ نظری‘ عورتوں کے حقوق کی پامالی‘ سودخوری سے نفرت‘حرام کاری سے گریز‘ لواطت پر ملامت‘ اپنے دین پر استقامت‘ محمدؐ سے محبت‘ شریعت کے اتباع حتیٰ کہ ستر ڈھانپنے کی خواہش‘ غرضیکہ کوئی نام بھی دے لیں‘ یہ سب ’’اُن‘‘ کی نگاہ میں ’’محورِ شر‘‘ ہیں جن کا مٹا دیا جانا ہی اُس ’’محورِ خیر‘‘ کی زندگی کی ضمانت ہے۔
انھوں (آگ کی بھٹیوں میں اہل ایمان کو ڈالنے والوں) نے اُن میں بجز اِس کے اور کیا عیب پایا تھا کہ وہ فقط ایک الٰہ واحد پر ایمان رکھتے تھے‘ (اور کسی دوسری طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہ تھے) جو وہ انھیں آگ میں جھونکتے اور قتل کر رہے تھے‘ (اُس) الٰہ واحد پر جو زبردست (اور) سب سے زیادہ سزاوار حمد (وعبودیت) ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں سلطنت (و اختیار اور سارا نظام) اُسی کا ہے‘ (ہر دوسرا نظام خواہ اُسے ’’یک عالمی نظام‘‘ کہیں یا کچھ اور‘ باطل اور ناقابلِ قبول ہے)۔ انھوں نے مومنین و مومنات پر بہت ظلم کیا ہے‘ اور توبہ کرکے باز نہیں آئے۔ اُن کے لیے (اللہ کے ہاں) جہنم کا اور آگ میں جلتے رہنے کا عذاب ہے اور اللہ (تو) ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ (البروج ۸۵:۵-۱۰)
اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اس میں اپنے ہی ’’برادرانِ اسلام‘‘ان دشمنانِ دین و ایمان کے آلۂ کار ہیں ؎
من از بیگانگاں ہرگز نہ نالم
کہ بامن ہرچہ کرد‘ آں آشنا کرد
کے مصداق کمین گاہ سے اپنوں ہی کے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امریکہ‘ فرانس یا اٹلی کو کیا الزام دیں کہ وہ مسلمان بچیوں کے سر پر رومالِ حجاب پہننے پر معترض ہیں‘ ترکی اور انڈونیشیا جیسے سو فی صد مسلم ممالک کیا کسی سے پیچھے ہیں! اور تو اور اِس مملکتِ خداداد پاکستان میں‘ جس کا وجود ہی ’’پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الٰہ الا اللہ‘‘ اور قرآن و سنت کے عہدِنفاذ کا مرہونِ منت ہے‘ اب اُس کی سرزمین ’’پاک‘‘میں بھی مکتب و مدرسہ کے ساتھ ’’دینی‘‘ کا لاحقہ تک دہشت گردی کی علامت ٹھہرا‘ یعنی جب بھی اکبرخدا کا نام لے گا‘ رقیب فوراً اس کی رپورٹ تھانے میں درج کرائیں گے‘ جہاں امریکی ایف بی آئی منکرنکیر کے طور پر اُس سے حساب کتاب کرے گی۔
حق و باطل کی تاریخی ستیزہ کاری میں یہ تصادم قابلِ فہم ہے۔ لیکن جو بات عالمِ اسلام سے بالعموم اور نظری پاکستان کے مقتدر طبقے سے بالخصوص پوچھنے کی ہے‘ وہ یہ ہے کہ ع
اے کشتۂ ستم! تری غیرت کو کیا ہوا!
پرانے زمانے میں خال خال لوگ حرص و طمع کا شکار ہو کر انفرادی سطح پر فروختنی اور قومی و ملّی غداری کے مرتکب ہو جاتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج فوج در فوج‘ صف بہ صف ہم اس دلدل میں گردن تک دھنسے ہوئے ہیں‘ اور سمجھتے ہیں کہ ’’ہم بچ گئے‘‘۔ کشمیر ہماری شہ رگ تھی‘ لیکن ہم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی سے دست برداری اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ دہشت گردی ہے۔ ہمارے ایٹمی ’’اثاثے‘‘ جنھیں ’’بچانے کے لیے‘‘ ہم نے مسلمانوں کے قتلِ عام اور اُمت مسلمہ پر امریکی آتش و آہن کی بارش کا طوفان برپا کرنے میں ہراول کا کردار ادا کیا‘ ہمارے گلے پڑ گئے۔ ہماری حاکمیت ِ اعلیٰ امریکہ کے پائوں میں ناک رگڑ رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ’’ہم بچ گئے‘‘۔
اے میرے وطن پاک کے وہ لوگو جو اِس ملک کی آزادی‘ حریت فکرونظر اور اپنے ایمان کی سرفرازی کے لیے خاک و خون کے سمندر میں سے گزرے! ہمارا کیا بچ گیا ہے؟--- اور ہم نے کیا کھویا ہے؟--- کیا ہمارا نفسِ لوامہ تھک ہار کر سو گیا ہے؟--- کیا ضمیر مردہ ہو گیا ہے؟--- کیا زندگی روح سے ایسے تہی ہو چکی ہے کہ اب بانگِ اسرافیل بھی اُسے زندہ نہیں کرسکتی؟ --- کیا نبضِ ضمیر میں کچھ ارتعاش‘ کچھ کسک باقی نہیں رہی؟
ہزاروں سال پہلے بھی فرعون نے یہی کہا تھا جو آج کہہ رہا ہے مَآ اُرِیْکُمْ اِلاَّ مَآ اَرٰی وَمَآ اَھْدِیْکُمْ اِلاَّسَبِیْلَ الرَّشَادِ o (المومن ۴۰:۲۹) ’’میں تمھیں بھی اسی نظر سے دکھائوں گا جس سے خود دیکھتا ہوں‘ میں تمھیں درست سمت ہی لے کر جائوں گا‘‘۔ میں نے اعلانِ جنگ کر دیا ہے تو اب سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا ورنہ سب دہشت گرد قرار دے دیے جائیں گے۔ میرے اعلانِ جنگ کے بعد دنیا بھر میں کروڑوں افراد کا "No War" (جنگ نہیں) کا نعرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انسانیت کی معلوم تاریخ میں اتنے بڑے عالمی مظاہروں کی مثال نہیں ملتی لیکن جمہوری اقدار کا نام نہاد محافظ امریکہ ۱۱ستمبر۲۰۰۱ء سے بھی اہم اس واقعے کو معمولی حیثیت دینے پر بھی آمادہ نہیں۔
طرفہ تماشا یہ ہے کہ عراق پر حملہ اور پورے خطے پر قبضہ جمہوریت کی ترویج کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ ۱۲ دسمبر ۲۰۰۲ء کو واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک میں امریکی وزیرخارجہ کولن پاول نے ایک ’’تاریخی‘‘ دستاویز پیش کی جس کا عنوان تھا: ’’امریکی شرق اوسطی شراکت براے جمہوریت و ترقی‘‘۔ اس منصوبے کو اگرچہ شراکت کا نام دیا گیا ہے اور ہدف جمہوریت و ترقی قرار دیا گیا ہے لیکن عملاً یہ پورے خطے کو امریکی استعمار کے تحت لانے کا منصوبہ ہے۔
کولن پاول کے بقول عالم عرب پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کا مرکز بن چکا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں: ’’عرب ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ۸۰ کے عشرے سے دنیا بھر میں دہشت گردی کا اصل سرچشمہ بن گئے ہیں۔ ۸۲ فی صد دہشت گردوں کا تعلق عرب ممالک سے ہے (شاید باقی ۱۸ فی صد دہشت گرد وہ ہوں گے جن کے ہاتھوں کشمیر‘ فلسطین‘ چیچنیا‘ بوسنیا‘کوسووا‘ فلپائن‘ برما‘ جنوبی سوڈان اور اریٹریا کے لاکھوں افراد کا خون ہو رہا ہے)۔ ان ۸۲ فی صد دہشت گردوں کی اکثریت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے‘‘۔ کچھ متوسط تعلیم کے حامل ہیں اور معمولی تعداد میں اَن پڑھ بھی ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ ان ممالک کے تعلیمی نصاب‘ تعلیمی اداروں کی بدانتظامی اور درست تعلیمی پالیسیوں کے فقدان نے ان دہشت گردوں سے درپیش خطرات کو دوچند کر دیا ہے‘‘۔
ا- اقتصادی عمل میں جمود‘ جمہوری اقدار کا فقدان‘ کرپشن‘ رشوت۔
۲- آبادی میں غیرمنظم اضافہ جو مزید اقتصادی بدحالی کا سبب بنا۔
۳- بے روزگاری۔
۴- فاسد نظام تعلیم۔
اپنے تئیں مرض اور اسباب بیان کرنے کے بعد علاج یہ تجویز ہوتا ہے کہ مختلف عرب ممالک میں امریکی تعلیمی ادارے کھولے جائیں جن میں تعلیم کے ساتھ ساتھ مغربی اقدار بھی سکھائی جائیں۔ تعلیمی ماہرین اور اساتذہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو تربیت دی جائے۔ امریکی نصاب تعلیم عام کیا جائے اور اس پورے عمل میں طلبہ و اساتذہ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک کرنے کے لیے فیسیں کم رکھی جائیں۔ ان مدارس اور امریکی اداروں میں تعلیم پانے والوں کو بڑی بڑی تنخواہوں پر ملازمتیں مہیا کی جائیں۔ انھیں معاشرے میں بڑھاچڑھا کر پیش کیا جائے اور اہم سیاسی و حکومتی مناصب تک پہنچنے میں ان کی مدد کی جائے۔ یہ لوگ امریکہ کے ساتھ جذباتی لگائو کے حامل اور مستقبل میں امریکی پالیسیوں کی حمایت کرنے والے اصل کل پرزے ہوں گے۔
علاج کا دوسرا اہم عنصر ان ممالک کے زیادہ سے زیادہ افراد کو سیاسی‘ اقتصادی‘ معاشرتی اور تعلیمی تربیتی کورس کروانا ہے جس کے لیے ہمارے پاس طے شدہ پروگرام موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی کتب کا ترجمہ کر کے ان ممالک کے اہم اداروں‘ سرکاری محکموں‘ پارلیمنٹ‘ تعلیمی اداروں‘ اہم لائبریریوں اور افراد تک پہنچائی جائیں۔ ان میں سے اہم کتب کو ان ممالک کے نصابِ تعلیم کا لازمی جزو بنا دیا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ تراجم کا یہ کام امریکی وزارتِ خارجہ کی زیرنگرانی ہو۔
تیسری جانب ان ممالک میں جمہوری اقدار کو فروغ دیتے ہوئے پارلیمنٹ کی تشکیل یقینی بنائی جائے۔ اس ضمن میں امریکی کانگریس سے خصوصی رہنمائی حاصل کی جائے۔
علاج کا چوتھا اہم عنصر عرب خواتین کی اپنے ملک کی سیاسی اور اقتصادی زندگی میں بھرپور شرکت ہے۔ پارلیمنٹ میں خواتین کی نمایاں نمایندگی ہو اور خواتین کی بہبود کے لیے موثر کمیشن اور کمیٹیاں تشکیل دی جائیں۔
اس پورے پروگرام کے لیے ابتدائی طور پر ۲۹ ارب ڈالر کا بجٹ رکھا گیا ہے لیکن یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ ضمنی اور تفصیلی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے مزید مالی امداد کی ضرورت ہوگی۔ وزیرخارجہ نے یہ وضاحت بھی کی کہ امریکہ جن ممالک کو بھی مالی امداد دیتا ہے آیندہ ان کی امداد اس پروگرام پر عمل درآمد کے تناسب سے مربوط کر دی جائے گی۔
اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے نظام الاوقات طے کیا جائے گا اور اس امر کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس پر عمل درآمد ۲۰۰۳ء میں شروع ہو کر ۲۰۰۶ء میں مکمل ہو جائے۔ امریکی وزیرخارجہ نے اس پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے خطے کے ممالک کو چار گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔
۱- وہ ممالک جنھیں یہ اصلاحات خود نافذ کرناہیں ان میں سعودی عرب اور مصر جیسے اہم ممالک شامل ہیں۔ انھیں یہ یقین دہانی کروائی جائے گی کہ امریکہ ان کی حکومتیں تبدیل نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان اصلاحات کو مکمل طور پر نافذ کیا جائے۔ امریکہ اس ضمن میں ان کی کڑی نگرانی کرے گی۔ اگر ان ممالک کو پروگرام کی کسی جزئیات پر کوئی اعتراض ہو تو انھیں خود اس کا ایسا متبادل پیش کرنا ہوگا جو امریکی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو۔
۲- وہ ممالک جہاں یہ اصلاحات عسکری قوت کے ذریعے نافذ کرنا ہیں‘ ان میں عراق‘ شام‘ لیبیا‘ ایران جیسے ممالک شامل ہیں۔ عراق پر حملہ خواہ القاعدہ سے تعلق کے الزام کی بنیاد پر ہو یا وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اسلحے کے الزام میں‘ سب ایک کھلا جھوٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عراق کو نئے امریکی استعمار کا نقطۂ آغاز بنانا مقصود ہے۔ یہ منصوبہ بھی کوئی راز نہیںرہا کہ تین سے پانچ سال تک کے لیے عراق پر قبضہ کرنا مقصود ہے تاکہ ایک تیر سے کئی شکار کیے جاسکیں۔
امریکی وزیرخارجہ کے مطابق عراق کے بعد لیبیا کی باری ہے‘ کیونکہ اس کے ساتھ مفاہمت کی کوئی ادنیٰ اُمید باقی نہیں رہی۔ ’’خطے کے ممالک کو ابھی سے اس ضمن میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور اس ضمن میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیبیا کے خلاف یہ کارروائی ۲۰۰۳ء کے اواخر یا ۲۰۰۴ء کے اوائل میں ہو سکتی ہے‘ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ متبادل قیادت کی تیاری عمل میں آجائے‘‘۔
کولن پاول منصوبے کے مطابق اگرچہ شام بھی اسی گروپ میں شامل ہے لیکن اس کے خلاف عسکری قوت کا استعمال کچھ مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ پہلے اسے مختلف سیاسی ‘اقتصادی‘ علاقائی اور اندرونی دبائو کے ذریعے اصلاحات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ البتہ ایران کے متعلق مزید تفصیل منصوبے میں شامل نہیں ہے۔
۳- وہ ممالک کہ جنھوں نے عملاً اصلاحات کا عمل شروع کر دیا ہے۔ انھیں ہمارا پورا تعاون حاصل رہے گا۔ ان میں بحرین‘ کویت‘مراکش اور تیونس وغیرہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک کو دیگر ممالک کے لیے بہتر مثال بنانا ہوگا اور ان کے مؤثر افراد کو تربیتی کورس کرواتے ہوئے مختلف سیاسی‘ غیر سیاسی اور این جی اوز کے نیٹ ورک میں فعال بنانا ہوگا۔ ان ممالک میں مقامی و بلدیاتی حکومتوں کے نظام کو مستحکم کرتے ہوئے حکومتی مرکزیت کو کم سے کم کرنا ہوگا۔
۴- وہ ممالک کہ جو امریکہ کے حلیف ہیں اور اس کے ساتھ عملی شراکت کا آغاز کرچکے ہیں ان میں قطر‘ اُردن اور یمن جیسے ممالک شامل ہیں۔ ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ ’’مناسب اوقات میں جو بھی امریکی پروگرام دیے جائیں انھیں نافذ کرنا ہوگا۔ ان اصلاحات کے نفاذ کی ذمہ داری براہِ راست امریکی ذمہ داران پر ہوگی۔ ان حکومتوں کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اندرونی معاملات یا قومی خودمختاری جیسی اصطلاحوں کی آڑ میں امریکی مطالبات سے راہِ فرار اختیار کریں کیونکہ ان حکومتوں سے امریکی تعاون کا اصل مقصد وہاں مثالی حکومتی نظام تشکیل دینا ہے تاکہ تمام رکاوٹوں اور مشکلات سے بآسانی نمٹا جاسکے‘‘۔ اس منصوبے کے مکمل متن کا عربی ترجمہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیں: www.elosboa.com
اس امریکی نقشۂ کار میں پاکستان کا مقام کیا ہو سکتا ہے‘ قارئین خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔
بیانات‘ رپورٹوں اور تجزیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس میں امریکی ارادوں اور صہیونی خواہشات چھلکتی دکھائی دیتی ہیں۔ ۱۹۹۱ء کی امریکی عراقی جنگ کے بعد بڑے بش نے کہا تھا کہ ’’اب عراق کی راکھ پر ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی جائے گی‘‘۔ تب اعلان کیا گیا کہ اسرائیلی فلسطینی تنازعہ حل ہونے کے بعد دنیا ایک نیا مشرق وسطیٰ دیکھے گی۔ ۱۹۹۳ء میں دو سال کے خفیہ مذاکرات کے بعد اوسلو معاہدہ سامنے آیا۔ ۲۰۰۰ء تک ہر ممکنہ طریقے سے اس معاہدے اور اس کی کوکھ سے جنم لینے والے کئی معاہدوںکو نافذ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تاآنکہ فلسطین میں تحریک انتفاضہ کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا جو تمام صہیونی امریکی ہتھکنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے ابھی تک جاری ہے۔ صہیونی ریاست تمام تر امریکی و مغربی امداد کے باوجود اقتصادی لحاظ سے ۵۰سال پیچھے چلی گئی ہے۔ اعداد و شمار گواہی دے رہے ہیں کہ صہیونی ریاست میں ایسا اقتصادی بحران ۱۹۵۳ء کے بعد پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے۔
اب ایک نئے زاویے سے ’’نئے مشرق وسطیٰ‘‘کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ دہشت گردی‘ ۱۱ستمبرسے تعلق‘ تباہ کن اسلحہ‘ اسلحہ انسپکٹروں سے عدم تعاون‘ اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کا نافذ نہ کرنا‘ جمہوری اقدار کی نفی… سب تجارتی اشتہارات ہیں۔ اصل مقصد افغانستان کے بعد ایک نیا نشانِ عبرت وجود میں لانا ہے‘ جس کی لاٹھی لہرا کر پوری دنیا کو باور کروانا ہے کہ ’’أنا ربکم الاعلٰی‘‘۔
عراق میں سعودی عرب کے بعد دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ ہے۔ صدربش کے سابق اقتصادی مشیر لارنس لینڈسائی نے واضح طور پر کہا تھا کہ ’’عراق کے خلاف فوجی کارروائی کا اصل ہدف تیل ہے‘‘۔عراق اس وقت پابندی کے باوجود بھی ’’تیل بمقابل غذا‘‘ فارمولے کے مطابق ۲۴ لاکھ بیرل تیل یومیہ نکالتا ہے جو تیل کی عالمی پیداوار کا ۳.۳ فی صد ہے‘ جب کہ زیرزمین ذخیرے کی مقدار ۵.۱۱۲ ارب بیرل ہے‘ جو دنیا کے مجموعی ذخیروں کی ۱۵فی صد ہے اور الاسکا سمیت امریکہ کے تمام ذخائر سے چار گنا زیادہ ہے۔ عراقی تیل نکالنے پر فی بیرل ایک سے ڈیڑھ ڈالر خرچ ہوتے ہیں‘ جب کہ شمالی امریکہ میں یہ لاگت ۲۱ ڈالر اور جنوبی امریکہ میں ۸۱ڈالر فی بیرل آتی ہے۔ عراقی تیل اپنے معیار کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تر ہے۔
اب اگر خاکم بدہن عراق پر امریکی قبضہ ہو جاتا ہے اور ڈیڑھ لاکھ امریکی و برطانوی فوجی وہاں تین سے پانچ سال تک کے عرصے کے لیے براجمان ہوجاتے ہیں (جیسا کہ اعلان کیا جا رہا ہے) تو اسے ’’پولوسٹپ‘‘ قراردیاجا رہاہے‘ یعنی ایسی بنیادی اور کاری ضرب کہ جس سے مضبوط مرکز زیر ہو جائے اور پھر تمام کمزور مراکز خود بخود شکست سے دوچار ہوتے چلے جائیں۔
اس جنگ میں کتنے وسائل جھونکے جائیں گے؟ مختلف اقتصادی ماہرین مختلف اندازے بتا رہے ہیں۔ ۵ دسمبر ۲۰۰۲ء کے نیویارک ریویو آف باکس میں کہا گیا کہ ’’اگر جنگ مختصر ہوئی تو اس پر ۵۰ ارب ڈالر خرچ ہوں گے جس کے بعد ۷۰ ارب ڈالر مزید درکار ہوں گے تاکہ جنگ کے نتائج پوری طرح حاصل کیے جاسکیں اور اگر جنگ طویل ہوئی تو اخراجات ۱۴۰ ارب ڈالر تک بڑھ سکتے ہیں جس کے بعد ڈیڑھ کھرب ڈالر مزید درکار ہوں گے۔ لیکن اگر امریکہ عراق اور خلیج کے تیل پر قبضہ مستحکم کر لیتا ہے تو ان اخراجات کی حیثیت‘ ان سے حاصل ہونے والے فوائد کے مقابل کچھ بھی نہیں۔
تیل کی قیمت میں صرف ایک ڈالر کی کمی آ جائے تو ایک سال میں امریکہ کے اخراجات چار ارب ڈالر کم ہو جاتے ہیں۔ ۱۹۹۸ء میں ایک بیرل کی قیمت ۳.۱۲ ڈالر تھی جو ۱۹۹۹ء میں ۸.۱۷ ڈالر اور ۲۰۰۰ء میں ۶.۲۷ ڈالر فی بیرل ہوگیا تو تمام امریکی حسابات تلپٹ ہوکر رہ گئے۔ ۱۹۷۴ء سے ۱۹۸۳ء کے دوران امریکہ کو صرف پٹرول کی تجارت میں تقریباً ۲۷ ارب ڈالر سالانہ بچت ہوتی تھی جو اب ۴۶ ارب ڈالر سالانہ خسارے میں بدل چکی ہے۔
یہ اعداد و شمار تو صرف جنگ کے امریکی اخراجات‘ عالمی تجارت اور خطے کے ممالک پر اس کے کیا بد اثرات مترتب ہوں گے اس کی کسی کو کوئی پروا نہیں۔ رہی لاکھوں انسانی جانیں‘تو ان کی کیا حیثیت‘ وہ کوئی نیلے خون والے امریکی تو نہیں کہ ان کی بھی فکر کی جائے۔
امریکہ تو اپنے ان اقتصادی‘ سیاسی‘عسکری‘ ثقافتی اور صہیونی مفادات کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار‘ بلکہ باولا ہوا جا رہا ہے لیکن مسلم ممالک جو اس جارحیت کا اصل شکار ہیں انھیں دشمن ہی سے نہیں اپنے آپ سے بھی غافل کیا جا رہا ہے۔ جنوری اور فروری جنگی تیاریوں کے حوالے سے حساس ترین تھے اور پاکستان ہی میں بسنت کا جنون نہیں مراکش‘ لبنان‘اُردن‘ قطر‘ امارات اور مسقط عمان سمیت متعدد ممالک میں میلے‘ جشن اور ہاؤہو کا طوفان عروج پر تھا اور اب بھی کسی نہ کسی حوالے سے جاری ہے۔ بسنت میں جب یہاں امریکی مشروب ساز اداروں کی طرف سے اشتہاری اور ہلاکتی مہم عروج پر تھی‘ عین انھی دنوں امریکہ میں یہ مہم چل رہی تھی کہ فورویل گاڑیاں بند کی جائیں کیونکہ ان میں پٹرول کی کھپت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم پٹرول زیادہ کھپائیں تو دہشت گرد ممالک کو پیسہ زیادہ ملتا ہے ‘ جس سے وہ ہمارے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں‘‘۔ سعودی عرب کو اس مہم کا زیادہ نشانہ بنایا گیا۔
ایک طرف دشمن کی تیاری اور منصوبہ بندی کا یہ عالم ہے‘ دوسری طرف اُمت مسلمہ نے صف بندی بھی نہیں کی ہے۔ ہمیں اس ربانی فیصلے میں تو ادنیٰ شک و شبہ نہیں ہے کہ: وَاللّٰہُ مُتِمُّ نُوْرِہٖ وَلَوْ کَرِہَ الْکٰفِرُوْنَ o(الصف ۶۱:۸)’’کافر کتنا ہی ناپسند کریں‘ اللہ اپنا نور مکمل کرکے رہے گا‘‘۔ لیکن اے قوم! اے سربراہانِ قوم!! غلبہ اور جیت تو ایمان و علم و عمل سے حاصل ہوتا ہے‘ کائنات کے رب پر ایمان اور کائنات میں ہر طرف بکھرے علوم تک رسائی اور پھر اجتماعی جدوجہد۔
ہر انسان امن، محبت، سکون اور اس طرح کی دیگر نفسیاتی و جذباتی ضروریات کی تسکین کا حاجت مند ہے۔ لیکن مرد بعض ضروریات کی تسکین کے طریق کار میں عورت سے مختلف ہوتا ہے اور اس اختلاف سے ناواقفیت میاں بیوی کو بعض مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے۔
میاں اور بیوی کی جذباتی ضروریات جن کی تسکین ضروری ہے بڑی حد تک انسان کے طرزِعمل کو متاثر کرتی ہیں۔ انسان کا طرز عمل انھی کے زیر اثرہوتا ہے سوائے اس صورت کے کہ مرد کی جذباتی ضروریات مکمل طور پر عورت کی ضروریات سے مختلف ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کی اکثریت ایک دوسرے کی جذباتی ضروریات کے اختلافات کو نہیں سمجھتی۔ اس عدم واقفیت کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کوسمجھنے سے قاصر رہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس فہم کا مثالی اسلوب کیا ہو، نیز وہ مطلوب تعاون کس طرح پیش کریں اور مشکلات سے کیسے بچیں۔ان میں سے ایک اہم مشکل غلط فہمی ہے۔
زوجین میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دوسرے کی ضروریات کی خاطر بہت کچھ پیش کیا ہے اور بڑا ایثار کیا ہے لیکن اس سے کوئی سود مند نتیجہ برآمد نہیں ہوا بلکہ جو کچھ پیش کیا گیا وہ سارے کا سارا ضائع ہوگیا اور حسن سلوک کا اعتراف نہیں کیا گیا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ زوجین نیک نیتی کے ساتھ محبت، مہربانی، شفقت اور معاونت کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن غلط اسلوب متوقع حسنِ سلوک کو بیگانگی میں تبدیل کردیتا ہے۔ جو چیز معاملات کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے وہ یہ کہ طرفین میں سے کوئی یہ خیال کر لے کہ یہ پریشانیاں (دوسرے فریق کی) عمداً پیدا کردہ ہیں۔جیسے کہ مرد کوئی کام بیوی کی خوشنودی اور بھلائی کے لیے کرے لیکن وہ بیوی کو اس انداز سے پیش کرے ‘ گویا کہ وہ کسی دوسرے مرد کو پیش کر رہا ہے ‘ نہ جس طرح کہ عورت کو پیش کیا جانا چاہیے ۔ اسی طرح سے عورت اپنے شوہر کو اس انداز سے پیش کرے جیسا کہ اس کی ضرورت مند کوئی عورت ہو، نہ کہ مرد۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک کو دوسرے فریق کی ضروریات اس طرح نظر آئیں جیسے کہ وہ اس کی اپنی ہوں۔ وہ ضروریات حسب ذیل ہیں:
۱- اعتماد: میاں‘ بیوی کے ساتھ معاملات میں شرکت اور تعاون کرتا ہے‘ اس کی حفاظت و پاسبانی کے لیے مستعد رہتا ہے‘ اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتاہے وہ بیوی اور خاندان کی خوشنودی اورخوش حالی کے لیے خرچ کرتا ہے‘ نیز یہ کہ وہ ہمیشہ اپنے خاندان کی بہتری کے لیے کوشاں رہتا ہے۔لہٰذا اسے محسوس ہونا چاہیے کہ اسے اپنی بیوی کا اعتماد حاصل ہے اور وہ اس کی قدر دا ن ہے ۔
۲- قبولیت: بیوی کی طرف سے میاں کو کسی اصلاح و تبدیلی کی شرط کے بغیر قبول کر نا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامل فرد ہے‘ جب کہ کمال توصرف اﷲ وحدہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، لیکن وہ قبولیت ‘ اس بات کی دلیل ہوگی کہ بیوی شوہرسے مطمئن ہے‘ اور وہ باور کرتی ہے کہ شوہر اپنی غلطیوں کی اصلاح کا اہل ہے اور بیوی کی دائمی نصیحتوں کا حاجت مند نہیں ہے ۔ اس صورت میں بیوی کے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی کہ شوہر اس کی بات پر دھیان دے اور اس کی رائے کو قبول کرلے۔
۳- تحسین و قدردانی: شوہر بیوی کی طرف سے تحسین و قدردانی محسوس کرے۔ جب بھی وہ خاندان کے لیے زبانی یا عملی طور پر کوئی چیز پیش کرے تو بیوی کی طرف سے احسان مندی‘ شکر گزاری اور حسن سلوک کے اعتراف کا اظہار ہونا چاہیے‘ اور اسے شوہر کی شخصیت اوراس کی رائے کو قدر و منزلت کی نظرسے دیکھنا چاہیے۔
۴- پسندیدہ نگاہ : شوہر کی عملی زندگی میں کامیابی کی بنیاد‘ اس کے خاندان میں اندرونی امن و سکون‘ اس کی بیوی کی طرف سے اس کی شخصیت ‘ اور اس کی داد و دہش کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھنا شوہر کی اپنی ثابت قدمی اور پختہ ارادے پر منحصر ہے ۔ یہ سب کچھ مل کر شوہر کی زندگی میں اہم اور بنیادی مقاصدکی تسکین کا باعث بنتا ہے۔
۵- تائید: یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہر شوہر ایسا مردِ میدان بننے کا خواہش مند ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی تمناؤں کا مصداق ہو۔ یہ مقام حاصل کرنے کی وہ سرتوڑ کوشش کرتا ہے ، اور بہترین حوصلہ افزائی جوشوہرکو اس دوران میں حاصل ہوسکتی ہے وہ اس کی بیوی کی تائیدہے۔ البتہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی کی تائید کا مطلب شوہر کے ہر کام میں دائمی موافقت نہیں اور نہ یہ موافقت ہی خود اس کام کے لیے ہوتی ہے بلکہ یہ موافقت اور تائید ان اسباب اور نیک ارادوں پر بھی ہو سکتی ہے جو شوہر اس کام کے بارے میں بروے کار لاتا ہے۔
۶- حوصلہ افزائی: بیوی کی طرف سے شوہر کی حوصلہ افزائی اور بلند خواہشات کے حصول کے لیے اس کی ثابت قدمی پراس کے عزم و ارادے کو تقویت دینے سے شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی پورے طور پر اس کی مزاج شناس ہے‘ نیز شوہر کی کامیابی کے لیے بیوی کا خواہش مند ہونا ایک ایسا امرہے جوبیوی اور اس کے خاندان کی کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔
۱- توجہ اور دل چسپی: بیوی اپنے میاں کی طرف سے توجہ کے اظہار اور دل چسپی کی ضرورت مند ہوتی ہے ۔ اسے آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ میاں کی نظر میں ایک ممتاز شخصیت ہے اور شوہر کی زندگی میں اسے ایک قابل ذکر مقام حاصل ہے۔
۲- ہمدردی : بیوی محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی نسوانی حالت سے باخبرہے اور اس کے احساسات کے ساتھ تعامل میں اپنے اوپر گزرنے والی نفسیاتی کیفیات کو سمجھتا ہے‘ اور یہ کہ وہ اس کا ہمدرد ہے۔
۳- احترام: بیوی کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت شوہر کی طرف سے بیوی کے اس احساس کو پختہ کرنا ہے کہ وہ بذات خود ایک قابل احترام اور آزاد شخصیت ہے ‘ اور دلیل کے طور پر وہ اس کی بات کو دل چسپی سے سنتا ہے اور اس کی رائے اور خیالات کواہمیت دیتاہے۔
۴- ترجیح: جب شوہربیوی کی ضروریات کو ترجیحاً پورا کردیتا ہے اور پوری مستعدی کے ساتھ اس کی تائید اور اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے ‘ تو بیوی اپنے تئیں اپنی حاجات کو پا لیتی ہے اور اپنے لیے اپنے شوہرکے جذبہ ( محبت ) کو محسوس کرتی ہے ۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ شوہر کی منظور نظر ہے حتیٰ کہ شوہر اسے اپنی ذات پر بھی ترجیح دیتا ہے تو وہ اس سے متاثر اور خوش ہو کر پورے اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کو اپنے شوہر اور خاندان کے لیے وقف کر تی اوراپنے احساسات کو ان پر نچھاور کر دیتی ہے۔
۵- اظہار احساسات کی آزادی : شوہر کی طرف سے بیوی کواسے تمسخر کا نشانہ بنائے بغیر اظہارخفگی کا استحقاق اور اسے اپنے احساسات کی تعبیر کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔
۶- مستقل یقین دہانی: اکثر شوہریہ سمجھتے ہیں کہ شوہر کی اپنی بیوی کے ساتھ طویل رفاقت اور بیوی کے حسن سلوک کا مطلب لازماً یہ ہے کہ وہ اس کے اخلاص اور ایثار کے باعث اسے ایک مثالی شخص باور کرتی ہے جو اس کے احساسات اور وفاداری کا ثبوت ہے‘ نیزیہ کہ وہ اس کے جذبات کی سچائی کی دلیل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیوی مستقل یقین دہانی چاہتی ہے کہ وہ شوہر کے جملہ احساسات کی مالکہ ہے، اس کی توجہ اور دل چسپی کا محور و مرکز ہے اور شوہر کے ہاں مرورزمانہ کے ساتھ اس کی قدر ومنزلت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ‘ بلکہ بڑھی ہے۔ یہ جواب ہے جو بیوی اپنے شوہر سے سننا چاہتی ہے۔ جب وہ ایک عمر کے بعد اس کے احساسات کی سچائی کے متعلق سوال کرنا چاہے توشوہر کی طرف سے سردمہری کی کیفیت اسے صدمے سے ہم کنار کر دیتی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک ان جملہ کیفیات کا ضرورت مند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میاں توجہ ، دل چسپی ، احترام، ترجیح وغیرہ کا حاجت مند نہیں ہوتا اور نہ یہ کہ بیوی اعتماد وتائید وغیرہ نفسیاتی حاجات سے بے نیاز ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میاں اپنی مخصوص چھ حاجات حاصل کرلے، وہ دوسری قسم کی حاجات ہرگز نہیں حاصل کر سکتا اور یہی صورت بیوی کے بارے میں ہے کہ جب تک وہ اپنی بنیادی حاجات کو حاصل نہیں کر لیتی‘ دوسری قسم کی حاجات حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ طرفین میں سے ہر ایک جب اپنی اپنی ضروریات حاصل کر لے گا تب ہی وہ دوسری جانب سے بڑے پیمانے کی تحسین و موافقت حاصل کرنے کے قابل ہو گا۔
اﷲ عزوجل نے میاں بیوی کی نفسیاتی حاجات میں اس اختلاف کو اسی وقت پیدا فرمادیا جب اس نے آدم و حوا‘مذکر و مؤنث کو پیدا فرمایا اور تخلیق کے اس اختلاف کی بنیاد پر دیگر اختلافات مرتب ہوئے اور یہی دونوں کی جسمانی ساخت اورنشوونما کی بنیاد ہے۔ اﷲ تعالیٰ نے انھیں تذکیر و تانیث اور متعین ذمہ داریاں ودیعت فرمائیں۔
نفسیات، تربیت، عادات وروایات کے اس بنیادی اختلاف نے ضروریات میں اختلاف پیدا کر دیا۔ ہمارا اس سے اتفاق نہیں کہ اختلاف زندگی کے بگاڑ کا باعث ہے ‘ بلکہ وہ تو اس کا خدمت گار ہے کیوں کہ طرفین ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور ان کے مابین نفسیاتی موافقت تکمیل پا جاتی ہے۔
ان ضروریات کے کچھ مخصوص عوامل ہیں جن کی تکمیل کا طریقہ ، فطری طریقہء کار سے مختلف ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس نے ماں کی مامتا‘ بیوی کی زندگی اور عورت کی کامیابی کے معاملے کو بگاڑ کر رکھ دیا ۔ نتیجتاً توازن بگڑ گیا ہے۔
قبل ازیں ماں اپنی بیٹی کی تربیت اس حیثیت سے کرتی تھی کہ پہلے اس نے بیوی بننا ہے، اس کے بعد ماں۔ مراحل کی یہ وہ ترتیب ہے جس کا اسے نفسیاتی طور پر اہل بنایا گیا ہے۔ مراحل کے توازن کا بگاڑ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب ہے۔ لہٰذا ہم نہ صرف نفسیاتی حاجات کے مطالعہ کے ضرورت مند ہیں بلکہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم باہمی کش مکش کے مراحل‘جو میاں بیوی کے درمیان بُعد پیدا کرتے ہیں‘ سے عہدہ برآ ہونے کے لیے بہت زیادہ نفسیاتی تعلیمات حاصل کریں۔
ازدواجی زندگی سے متعلق فریقین کا تصور الگ الگ ہوتا ہے لیکن بنیاد ی طور پر ضروریات میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا جیسا کہ حاجت پوری کرنے کے درجے میں بھی کوئی ضابطہ نہیں ہوتا۔ البتہ بعض حالات میں بیوی ا عتماد‘ توجہ یا تائید وغیرہ کی زیادہ مقدار کی حاجت مندہوسکتی ہے۔
۱- زوجین کے حقوق یا ان میں سے کسی ایک کی حاجات کا نظر انداز کر دینا ۔ اگر ان کی تکمیل کا براہ راست اور فوری طورپر اہتمام نہ کیا جائے تو وہ دردانگیز احساسات اکٹھے ہوتے اور ایک لمبے عرصے تک تہ بہ تہ جمع ہو تے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ کسی غیر مناسب وقت پر پھٹ پڑتے ہیں۔ لہٰذا فریقین کا فرض ہے کہ وہ بلاتاخیر معاملات کو نمٹالیں۔
۲- طرفین میں سے کوئی ایک اپنی بہت سی خواہشات کو ایثارو قربانی کے نام پر ترک کر دے تاکہ وہ ایثار کیش شمار کیا جائے‘ جب کہ وہ ان خواہشات کو پورا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ہاں ‘ اگر ان میں سے کسی ایک پر ایثار کرنا ناگزیر ہو تو ضرور کیا جائے اور زوجین اپنا نصب العین بنا لیں کہ وہ جو کچھ بھی اپنے خاندان کے لیے کریں ‘ وہ ایک ہی نہر میں ڈالا جائے جو ان کے خاندان کی سعادت مندی اور خوشحالی کی نہر ہے۔
اگر میاں یا بیوی کی طرف سے مذکورہ چھ ضروریات میں سے کوئی ضرورت سے زیادہ بطور عطیہ پوری کی جائے توا ن کے مابین تائید ،حوصلہ افزائی اور نصائح کی کثرت کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے گا جیسا کہ ماں کا بیٹے کے ساتھ۔ نتیجتاً معاملہ دو طرح تقسیم ہو جائے گا ‘ یا تو میاں اس بار ے میں کوفت و پریشانی میں مبتلا رہے گا اور یا ہتھیار ڈال دے گا اور اس دوران میں بیوی کو شکایت رہے گی کہ خاندان میں ہر شے کے بارے میں وہی مسئول اول بن کر رہ گئی ہے۔
۳- زوجین کو یہ حقیقت معلوم ہو جانی چاہیے کہ مرد اپنے فیصلے میں تائید کا طلب گار ہوتاہے‘ جب کہ عورت اپنے فیصلے میں شرکت کی خواست گار ہوتی ہے۔ مردکی فطرت آزادی اور خوداعتمادی پر مشتمل ہوتی ہے‘ جب کہ عورت شرکت کی طرف مائل ہوتی ہے اور شرکت بھی اس کی ، جسے وہ پسند کرتی ہو۔
۴- سوے ظن اور بدگمانی ازدواجی زندگی کی رفتار میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن حکیم اور سنت مطہرہ میں ہمیں لوگوں سے بدگمان ہونے سے منع فرمایا گیا ہے اور میاں کی بیوی سے یا بیوی کی میاں سے بدگمانی بدرجہ اولیٰ اجتناب کی متقاضی ہے۔ لازم ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں اور شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ حسن ظن کا رویہ اختیار کریں ‘ اور کمال تو صرف اﷲ وحدہ لاشریک ہی کے لیے ہے۔ لیکن زوجین کے مابین حقیقی اشتراک و ہم آہنگی تو وہ ہے جو زندگی کے باہم متصادم نقطہ ہاے نظرمیں آئے۔ (انٹرویو: ایمان الشوبکی‘ ترجمہ: خدابخش کلیار‘ ہفت روزہ المجتمع ۲۵مئی ۲۰۰۲ء )
انٹرنیٹ کے ذریعے سے ممبر اپنا اکائونٹ کھولتا ہے اور ۶ ہزار روپے کمپنی کو جمع کروا کر ممبرشپ حاصل کرتا ہے۔ وہ ممبر پھر مزید دو افراد کو ممبرشپ دلواتا ہے جو مزید چھ چھ ہزار روپے کمپنی کو جمع کرواتے ہیں۔ اسی طرح ہر فرد مزید دو افراد کو ممبر بنانے کا مکلف ہوتا ہے۔ جب نو افراد ممبر بن جاتے ہیں تو پہلے ممبر کو ۳ ہزار ۳ سو روپے کا چیک مل جاتا ہے۔ گویا ہر فرد ۵۴ ہزار روپے کمپنی کو جمع کروا کر ۳ ہزار ۳ سو روپے حاصل کرتا ہے۔ علاوہ ازیں کمپنی ہر ممبر کو ایک سال کے پیکج کے لیے جس کی لاگت ۳۰ ہزار سے ۴۰ ہزار ہوتی ہے loyalty کارڈ (۵ سے ۵۰ فی صدرعایت) فراہم کرتی ہے۔ اس اسکیم سے بہت سے لوگ وابستہ ہو رہے ہیں۔ کیا یہ اسکیم سود پر مبنی ہے؟
جواب: جہاں تک معاشیات اور اسلامی معاشیات کے طالب علم کی حیثیت سے میرا مطالعہ ہے‘ میں بزناس اور اس نوعیت کے دوسرے کاروباری سلسلوں کو نہایت شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔
اسلامی معاشیات کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ سرمایہ‘محنت اور قدرتی وسائل کا استعمال اس طرح کیا جائے کہ پیداواری صلاحیت اور اثاثوں کی تخلیق (asset creation) رونما ہو۔ اسی سے اضافۂ قدر (value added) کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پیداواری صلاحیت (productivity) بڑھتی ہے‘ اشیا اور خدمات کی رسد بڑھتی ہے اور انسانوں اور معاشرے کی ضروریات پوری ہونے کا سامان کرتی ہے۔ یہی عمل ہے جسے پیدایش دولت (wealth creation)کہا جاتا ہے اور یہی وہ عمل ہے جو انسانوں کے لیے خیر اور فلاح کا باعث ہوتا ہے۔ اس نظام میں زر (money) کا کردار یہ ہے کہ وہ دو انسانی یا مادی (human or physical) وسائل کے درمیان تبادلے کا ذریعہ اور اس طرح حقیقی معاشی سرگرمی کو آگے بڑھانے کا وسیلہ بنتا ہے۔ اس طرح زر ایک زرِمبادلہ (medium of exchange) ہے‘ ایک معیارِ قدر ہے اور حال اور مستقبل کے معاشی لین دین کے لیے مرکزی حوالہ (reference point) ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشیات میں زر خود ایک شے (commodity) نہیں ہے اور زر کی خرید و فروخت بحیثیت زر ممنوع ہے۔ زر صرف ایک ذریعہ ہے‘ خود اس سے مزید زر پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بنیادی تصور ہے اور میرے علم کی حد تک ہر مذہب اور ہر اس تہذیب نے جس کی اخلاقی بنیادیں ہوں اس بنیاد کو تسلیم کیا ہے۔ ارسطو تک نے یہ بات کہی تھی کہ زر‘ زر پیدا نہیں کرتا ("money does not beget money") ۔
یہی وجہ ہے کہ سود (ربٰو) اسلام میں ہر شکل میں ممنوع ہے۔ اس کی اخلاقی‘ تہذیبی اور معاشی بنیاد یہ ہے کہ اگر زر مادی اثاثوں (physical assets) یا خدمات (services) کے فروغ کا ذریعہ بنتا ہے‘تو اس کے ذریعے سے جو نمو اور اضافہ (value creation) وجود میں آتا ہے ‘ اور جسے منافع کہا جاتا ہے وہ ایک جائز اضافہ ہے اور یہی وہ اضافہ ہے جو انسانی زندگی کو ضروریات کی تکمیل اور خوش حالی سے ہم کنار کرتا ہے۔ تجارت اور اس سے حاصل ہونے والے نفع کو جائز اور مطلوب قرار دینے اور ربٰو سے حاصل ہونے والے اضافے کو خسارہ اور ظلم قرار دینے کی یہی بنیاد ہے۔ ہر وہ کاروبار جس کے نتیجے میں اثاثوں کی تخلیق ہو‘ خواہ اشیاے صرف کی شکل میں ہو یا اشیاے پیداوار یا خدمات کی ‘ مفید اور جائز ہے۔ اور صرف روپیہ کے لین دین سے اثاثوں کی تخلیق کے بغیر اضافہ ربٰوکی تعریف میں آتا ہے۔
جس کاروبار کا آپ نے ذکر کیا ہے اور جو تفصیل اس کی آپ نے بیان کی ہے اِس اصول کی روشنی میں اس کا ہدف بظاہر اثاثوں کی تخلیق نہیں بلکہ کسی کا پیسہ لے کر کسی دوسرے کو پیسہ دینا ہے۔ اس طرح اضافے اور آمدنی کو حقیقی پیداواری عمل کے بجائے محض روپیہ کے ہیرپھیر کی صورت میں استعمال کرنا اخلاقی اور معاشی دونوں اعتبار سے ان مقاصد کو پورا نہیں کرتا جو شریعت کا منشا ہے۔ جہاں تک loyalty کارڈ کا معاملہ ہے وہ ایک غیر متعلق چیز ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محض چاشنی کے لیے اسے اس اسکیم پر لگا دیا گیا ہے۔ اس طرح کا کارڈ آج مغربی دنیا میں عام چیز ہے اور اسے اس قسم کے سرمایے کے لین دین سے منسلک کرنا کوئی منطقی بات نہیں۔اس قسم کے کارڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی سٹور سے خریدے اور ادارے سے تعلق کی بنیاد پر اور اپنی خریداری میں استمرار (continuity)کی وجہ سے اسے کٹوتی دی جائے۔ بظاہر اس پوری اسکیم میں یہ کارڈ ایک الگ چیز ہے اور پیسہ بٹور کر پیسہ دینا ایک دوسری چیز ہے۔
اگر صورت حال کے بارے میں میرا تجزیہ صحیح ہے تو اس طرح کے اکائونٹ سے جو منافع حاصل ہوگا‘ اسے اسلامی معاشیات (اور خود جدید معاشیات) کی رُو سے منافع میں حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے کہ سرمایے میں اضافہ کسی پیداواری عمل سے مربوط نہیں ہے۔ میری نگاہ میں یہ زر ہی کے لین دین کی ایک نسبتاً ’تہذیب یافتہ‘ (sophisticated) اور پیچ در پیچ (round about) کوشش ہے جو معاشی اعتبار سے مخدوش اور اخلاقی اعتبار سے ناقابلِ دفاع ہے۔ اس سے ایک قسم کی حبابی معیشت (bubble economy) تو پیدا ہو سکتی ہے لیکن مادی اثاثوں کی وہ تخلیق رونما نہیں ہوتی جو اسلام اور خود معاشیات کا اصل ہدف ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے اور خالص شرعی پہلو کے لیے مناسب ہے کہ آپ صاحب ِنظر اور ثقہ علما سے رجوع کریں۔(پروفیسر خورشید احمد)
س: موجودہ بنک کاری نظام سودی ہے اور صہیونیت کے شکنجے میں پوری طرح جڑا ہوا ہے۔ اسلامی بنک کاری بھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ عام آدمی اپنی مختلف مجبوریوں‘ ضرورتوں اور تحفظ کے پیش نظر بنک میں پیسہ رکھنے پر مجبور ہے اور اسے اپنی رقم کے عوض سود لینا پڑتا ہے۔
میری تجویز ہے کہ جب تک کوئی متبادل میسر نہیں آتا اس سود کو حاصل کر کے خود استعمال کرنے کے بجائے غریب اور نادار افراد کی ضروریات پر خرچ کیا جائے‘ اور مفلوک الحال لوگوں کی حالت بدلنے پر صرف کیا جائے۔ کیا یہ تجویز شرعی نقطۂ نظر سے جائز ہے؟
ج : اس وقت بنکنگ کا جو صہیونی نظام ہے اس کے شکنجے سے نکلنے کی تدبیر وہ قیادت کرسکتی ہے جو ایمان اور علم و عمل سے سرشار اور امریکی عالمی استعمار کی ذہنی غلامی سے آزاد ہو۔ اس وقت تک اس نظام کے ظلم سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جائے؟ اس کے لیے متعدد تجاویز میں سے ایک تجویز وہ ہے جو آپ نے پیش کی ہے۔
مجھے آپ کی اس تجویز سے کہ سودی منافع بنک سے حاصل کر لیا جائے اور خود استعمال کرنے کے بجائے اپنے مفلوک الحال بھائیوں کو دے دیا جائے‘ سے اتفاق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود لینا ظلم ہے اور سود دینا ظلم میں تعاون ہے۔بنک سود لیتا ہے‘ مقروض اشخاص اور ادارے اسے سود دیتے ہیں اور اس طرح وہ ظلم میں بنک سے تعاون کرتے ہیں۔ بنک ظلماً جو سودی رقمیں لیتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ خود رکھ لیتا ہے اور اس کا تھوڑا سا حصہ کھاتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ بنک مقروض اداروں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے اور کھاتہ داروں کے ساتھ بھی۔ مزید یہ کہ وہ کھاتہ داروں کو اس ظلم میں اپنے ساتھ شریک بھی کرتا ہے۔
کھاتہ داروں کے لیے اس ظلم سے نکلنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بنک سے سودی منافع وصول کر لیں اور ان لوگوں تک پہنچا دیں جن سے سود لیا گیا ہے۔ اصل حق دار وہی ہیں لیکن ان کا معلوم کرنا اور ان تک رقم پہنچانا ناقابل عمل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فقرا اور مساکین تک یہ رقم پہنچا دی جائے۔ یہی وہ صورت ہے جو آپ نے تجویز کی ہے۔ یہ قابل عمل ہے اور احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ گم شدہ رقم اور سامان کا حکم احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اصل مالک کو تلاش کیا جائے اور رقم اور سامان اس تک پہنچایا جائے۔ اگر سال دو سال تک اعلان اور تشہیر کے باوجود اصل مالک نہ ملے تو اس رقم کو فقرا اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کا ثواب اصل مالک کی طرف گم شدہ رقم اور سامان کو فقرا میں تقسیم کرنے والے کو ملے گا کہ اس نے رقم بے جا صرف کرنے کے بجائے حق دار پر صرف کی ہے۔ سودی منافع بھی گم شدہ رقم اور سامان کے حکم میں ہے کہ اصل مالکوں تک اس کا پہنچانا ناقابل عمل ہے۔ لہٰذا اسے بنک سے وصول کر لیا جائے اور فقرا اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ فقرا ان رقوم کے حق دار ہیں جن کے مالک معلوم نہ ہو سکتے ہوں۔ آپ سودی منافع وصول کر کے اپنے رشتہ داروں یا معاشرے کے مفلوک الحال افراد تک پہنچا سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی اور دینی تحریکیں اس حل سے متفق ہیں۔ البتہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ خود اس رقم کو استعمال نہ کریں تاکہ اس کا ناجائز ہونا ذہن میں مستحضر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رزق حلال عطافرمائے۔ آمین! (مولانا عبدالمالک)
تقسیمِ ہند کے بعد بھارت کے مسلمان ایک ایسی انوکھی صورتِ حال سے دوچار ہوئے جو انھیں تاریخ میں اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ ۱۵اگست ۱۹۴۷ء کو بظاہر ’’جمہوریت کی نئی صبح‘‘ طلوع ہوئی تھی اور آزادی و مساوات کی بشارت دی گئی مگر حقیقت میں ہندو اکثریت کے غصّہ و انتقام کے ایک نئے دَور کا آغاز ہوچکا تھا۔
نئے حالات کے پیش نظر اور گوناگوں مسائل سے عہدہ برآ ہونے کے لیے گذشتہ ۵۰برسوں میں بھارت کے مسلمانوں اور مسلم جماعتوں اور تنظیموں نے طرح طرح کی حکمت عملیاں اختیار کیں۔ اس ضمن میں زیرنظر کتاب میں حسب ذیل مسلم تنظیموں کی کاوشوں اور کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے: جمعیت العلماے ہند‘ امارتِ شرعیہ بہار و اڑیسا‘ تبلیغی جماعت‘ جمعیت اہل حدیث‘ جماعت اسلامی‘ مسلم لیگ‘ کل ہند تعمیرملّت‘ مجلس اتحادالمسلمین‘ مسلم مجلس مشاورت‘ مسلم مجلس‘ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ‘ اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا‘ انسٹی ٹیوٹ آف آبجکیٹواسٹڈیز‘ آل انڈیا ملّی کونسل۔
یہ کتاب ایک طرح سے مذکورہ بالا تنظیموں کا تعارف ہے‘ (مختصر تاریخ‘ طریق کار اور حکمت عملی کا تجزیہ)۔ مصنف نے صدر یار جنگ‘ سلیمان ندوی‘ مناظراحسن گیلانی‘ مولانا مدنی‘ مولانا لاہوری‘ ابوالکلام اور مولانا تھانوی کے نام لے کر‘ یہ سوال اٹھایا ہے کہ اتنے بڑے ذہن و دماغ کے انسان رکھنے والی اُمت آخر کیوں اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکی؟ ڈاکٹر سید عبدالباری کے نزدیک اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیشتر علما نے مغرب کے اقتدار اور جبروت کے اسباب پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا اور اس کی ترقی کے اسباب کا تجزیہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور صرف انگریز دشمنی کو اپنا مذہب و مسلک بنا لیا۔ مزیدبرآں مغرب کے اُن فلسفوں کا توڑ کرنے کے لیے انھوں نے کوئی بڑا تحقیقی ادارہ قائم نہیں کیا جو پوری دنیا میں اتھل پتھل مچائے ہوئے تھے اور بعض عالی مرتبت علما ذہنی طور پر اشتراکیت سے مرعوب تھے اور مدارس کا ماحول عام طور پر دیگر مسالک کی تغلیط و تردید کا ہی رہا (ص ۵۰-۵۱)۔
مصنف نے جماعتوں اور تنظیموں کے انفرادی کردار‘ خدمات اور ان کے کارناموں کے ساتھ ان کی خامیوں‘ ناکامیوں اور کمزور پہلوئوں کی بھی نشان دہی کی ہے۔ مگر مصنف کی تنقید بہت معتدل اور محتاط ہے۔ تبصروں اور تجزیوں میں انھوں نے بہت کچھ سنبھل سنبھلا کر‘ اور پھونک پھونک کر قدم اٹھایا ہے‘ اور بالعموم اختلافی پہلوئوں کے ذکر سے گریز کیا ہے۔ مثلاً تبلیغی جماعت کا (مولانا محمد الیاس اور مولانا محمد یوسف کے دَور تک) فقط تعارف کرا دیا ہے مگر اب کیا صورتِ حال ہے؟ اس پر‘ ماسوا دو تین جملوں کے (ص ۱۴۳) کچھ کلام کرنے سے گریز کیا ہے--- جماعت اسلامی کی کمزوریوں کی طرف ہمدردانہ اشارے بھی کیے ہیں (ص ۱۹۹-۲۰۰)۔
ڈاکٹر سید عبدالباری ایک تجربہ کار معلّم اور اُردو کے معروف ادیب و شاعر اور نقاد ہیں۔ انھیں یہ علمی منصوبہ ‘ دہلی کے انسٹی ٹیوٹ آف آبجکیٹو اسٹڈیز کی طرف سے سونپا گیا تھا۔ ان کا کام بہت اہم مگر اتنا ہی نازک تھا۔ کتاب میں (’’اگرچہ‘‘…’’پھر بھی‘‘ کے اسلوب کے ذریعے) ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھنے کی سعی نظر آتی ہے۔ مجموعی طور پر ان کے ہاں اُمیدافزا پہلو غالب ہے۔ اس طویل تجزیے کا اختتام بھی ان سطور پر ہوتا ہے کہ ۵۰ سال کی طویل سیاہ رات کے بعد آفتابِ تازہ کا طلوع زیادہ دُور نہیں اور راقم کو اس صبحِ روشن کے قدموں کی آہٹ صاف طور پر سنائی پڑ رہی ہے۔ (رفیع الدین ہاشمی)
یہ ایک ایسے معلّم اور مصنف کی آپ بیتی ہے جو ریاست دیر جیسے دُورافتادہ اور پس ماندہ علاقے میں پیدا ہوا۔ ریاست میں ایک بھی اسکول نہ تھا۔ لوگ چھپ چھپ کر یا باہر جاکر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ نواب دیر اپنی رعیت کو تعلیم دینے کے خلاف تھا۔ کسی کو اسکول کھولنے کی اجازت نہ تھی مگر ان کے اپنے بیٹے بیرونِ ملک جاکر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ریاست میں کتوں کے لیے تو شفاخانہ موجود تھا مگر انسانوں کے لیے کوئی ہسپتال نہیں تھا (ص ۳‘۴)۔
مصنف نے غربت اور تنگ دستی کے عالم میں تکلیفیں برداشت کر کے اور محنت و مشقت کی زندگی گزارتے ہوئے‘ نہایت عزم و ہمت اور حوصلے کے ساتھ ریاست سے باہر جاکر تعلیم حاصل کی۔ کیمبرج یونی ورسٹی سے ایم‘لٹ اور پشاور یونی ورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ پشاور یونی ورسٹی میں لیکچرر ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے ڈین کے عہدے تک پہنچ کر سبکدوش ہوئے۔
مصنف کی اس بات پر تو رشک ہی کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بلامبالغہ کوئی ایسی نعمت نہیں جو اللہ نے مجھے نہیں دی اور کوئی ایسی آرزو نہیں کی جو اللہ نے پوری نہیںکی (ص ۳۰۷)۔ لیکن آپ بیتی پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ نہایت غریب گھرانے اور انتہائی پس ماندہ علاقے کے ایک شخص نے جو کچھ بھی ترقی کی ‘اس کے پسِ پردہ توفیقِ الٰہی کے ساتھ مصنف کی نیک نیتی‘ خلوص‘ عزم و ہمت اور دوسروں سے ہمدردانہ رویہ‘ اپنے فرائض کی دیانت دارانہ بجاآوری‘ وقت کی سختی سے پابندی‘ سخت کوشی‘ سحرخیزی اور رزق حلال جیسے عادات و معمولات اور عوامل و عناصر کارفرما رہے۔ کہتے ہیں کہ میں اسکول کے زمانے میں کبھی کبھی سارا سارا دن بھوکا رہتا تھا لیکن واپسی پر (دوسرے ہم جماعتوں کی طرح) بلااجازت کسی کھیت سے گنا نہیں توڑا (ص ۲۹)۔ ہمیشہ پہلا پیریڈ لیا اور صبح جاگنے کے لیے کبھی الارم کلاک کا استعمال نہیں کیا (ص ۱۵۳)۔
مصنف کے بیرونِ ملک اسفار کے تجربات دل چسپ ہیں ‘مثلاً: اوّل‘ کیمبرج کے ایک پروفیسرنے قادیانی سمجھ کر ان کی خوب حوصلہ افزائی کی لیکن جب پتا چلا کہ ’’میں قادیانی نہیں تو اس نے مجھ میں دل چسپی لینی چھوڑ دی‘‘ (ص ۷۳)۔ ہم کیمبرج کے پروفیسروں کی مہارتِ علمی اور رہنمائی سے بہت مرعوب ہیں مگر مصنف کا تجربہ مختلف ہے۔ ان کے نگرانِ مقالہ نے ان کی صحیح رہنمائی نہ کی اور نہ کوئی خاص مدد کی۔ البتہ مصنف نے پروفیسر آربری کی تعریف کی ہے کہ ان کا طرزِعمل سارے کا سارا ایک مسلمان کا تھا‘ بس کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ دوم: مصنف نے اپنے کچھ دیگر تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہودی پوری انسانیت کو بداخلاق بنانے پر تلے ہوئے ہیں اور انھوں نے مسلمان ملکوں میں جاسوسی کے جال بچھا رکھے ہیں۔
آخری حصے میں ایک پورا باب تنظیم اساتذہ پاکستان پر ہے۔ قاضی صاحب نے تنظیم کی اہمیت و خدمات کے ساتھ اپنے اُوپر اس کے احسانات کا اعتراف کیا ہے لیکن تنظیم اور افرادِ تنظیم کی کمزوریوں‘ خامیوں اور اصلاح طلب پہلوئوں کا بھی بڑے کھلے اور واشگاف انداز میں ذکر کردیا ہے۔ یہ ایک طرح کا مکتوبِ مفتوح ہے۔
قاضی صاحب کا اسلوب رواں دواں اور آسان ہے۔ اگرچہ فنی اور ادبی اعتبار سے تو یہ خودنوشت کوئی بلندپایہ آپ بیتی قرار نہیں دی جا سکتی‘ لیکن مصنف نے جس خلوص‘ کھلے دل و دماغ‘ صاف گوئی اور بے لاگ انداز میں اسے لکھا ہے اس لحاظ سے یہ ایک دل چسپ‘ معلومات افزا‘ سبق آموز اور قابلِ مطالعہ آپ بیتی ہے۔
اگر اس کی تدوین کی جاتی اور تکرار یا غیر ضروری حصوں کو نکال دیا جاتا اور زبان و بیان میں بھی کچھ اصلاح کر دی جاتی تو یہ کہیں زیادہ خوب صورت اور عمدہ خود نوشت کا درجہ حاصل کرلیتی (ضخامت بھی کم ہو جاتی)‘ تاہم موجودہ صورت میں بھی اس میں ایک اچھی آپ بیتی کی بعض خوبیاں موجود ہیں‘ مثلاً مصنف کا خود احتسابی کا رویہ‘ اپنی غلطیوں اور شخصی کمزوریوں کا اعتراف‘ صاف گوئی اور اپنے شدید مخالفین سے براہِ راست مکالمے کا اہتمام اور ان کی خوبیوں کا اعتراف وغیرہ۔ (ر- ہ )
ڈاکٹر محمد رفیع الدین (۱۹۰۴ئ-۱۹۶۹ئ) ایک ممتاز فلسفی‘ اقبال شناس اور جدید علوم کے اسکالر تھے۔ ان کی عالمانہ تصنیف قرآن اور علمِ جدید بقول ڈاکٹر غلام مصطفی خان: ’’جدید نظریات کو اسلام کی کسوٹی پر پرکھنے اور اسلام کے نظریۂ لاشعور‘ نظریۂ جبلت‘ نظریۂ فوقیت اور نظریۂ معاش اور اسلام کے نظریۂ قومیت کی تشریح کے سلسلے میں--- سب سے نمایاںاور منفرد نوعیت کی کتاب ہے‘‘۔ محمد موسٰی بھٹو نے بکثرت ذیلی سرخیوں کے اضافے کے ساتھ اصل کتاب کی تلخیص پیش کی ہے۔ شروع میںایک طویل مضمون میں بھٹو صاحب نے مصنف مرحوم کی فکر کے اہم پہلوئوں کا خلاصہ اور ان کی بعض کتابوں سے اقتباسات دیے ہیں۔ یہ سب مباحث فکری اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ مصنف کی علمیت مسلّمہ اور عالمانہ نقدوتبصرہ اورگرفت بہت عمدہ اور برمحل ہے۔
اصل کتاب کے آخری سو صفحات (مارکسزم کی بحث) کی تلخیص شامل نہیں کی گئی کیونکہ کتاب کی ضخامت زیادہ ہو چلی تھی۔ تدوین شدہ موجودہ صورت میں آسانی سے پتا نہیں چلتا کہ مرتب کا مطالعاتی جائزہ کہاں ختم ہو رہا ہے اور اصل کتاب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فہرست بھی رہنمائی نہیں کرتی۔ کاش اس نہایت مفید کتاب کو تدوین و تلخیص اور معیارِ اشاعت کے لحاظ سے بھی شایانِ شان طریقے سے پیش کیا جاتا۔ (ر-ہ)
مولاناعامر عثمانی مرحوم نے بڑی پتے کی بات کہی ہے: ’’ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام گروہ‘ تمام باضابطہ جماعتیں اپنے اپنے گروہی خیالات و نظریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے‘ اس طوفان ہلاکت کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہوں‘ جو ہم سب کو بہا لے جانے کے لیے گرجتا‘اُمڈتا چلا آرہا ہے‘ چلا نہیں آ رہا‘ ]بلکہ[کبھی کا آچکا ہے‘‘۔ (ص ۱۷۶-۱۷۷)
اس اپیل کے ساتھ وہ لکھتے ہیں: ’’تبلیغی جماعت کے اعمالِ خیرپر ہم کبھی معترض نہیں ہوئے‘ بلکہ موقع بہ موقع انھیں سراہا ہے‘‘ (ص ۲۷۰)۔ واقعہ یہ ہے کہ تبلیغی افراد ایثار و اخلاص اور تصوف کے ملے جلے جذبے سے سرشار گھروں سے نکلتے ہیں مگر اساطیری حوالوں اور ضعیف روایتوں کی آمیزش سے ان کے ’’راہبانہ ذہن‘‘ (ص ۱۶۶) تیار کیے جاتے ہیں‘ انھیں ہمدردانہ دعوتِ فکر سے درست کرنے کی سعی کرنا‘ ہر عالم‘ فاضل اور دین کے بہی خواہ پر واجب ہے۔ یہ امر بھی مشاہدے میں آتا ہے کہ ’’جہاں تبلیغی نصاب پڑھا جانے لگا‘ وہاں ایسا التزام کیا جانے لگا کہ کچھ اور پڑھنے کو عملاً ]ممنوع[ کر دیا گیا۔ اسی کا نام ہے غیرواجب کو واجب بنا لینا‘‘ (ص ۲۸۳)۔
تبلیغی جماعت کے اس صدقہ جاریہ میں ایسی افراط و تفریط کا در آنا ایمان‘ جستجو اور حریت کے پیمانوں کو ضعف پہنچانے کا باعث بنتا ہے جس پر نہ صرف جماعت کے بزرگوں کو بلکہ دوسرے راست فکر اہل علم حضرات کو بھی خلوصِ نیت کے ساتھ رہنمائی کرنا چاہیے‘ عامرعثمانی مرحوم نے یہی خدمت انجام دی ہے۔
جیساکہ تبصرے کے آغاز میں ہم نے عامر عثمانی مرحوم کا قول نقل کیا ہے کہ اُمت کی مختلف جماعتوں کو اتفاق و ایمان کے ساتھ تعاون کی شاہراہ پر گامزن ہونا چاہیے۔ اسی جذبے کے تحت عامرعثمانی نے مختلف اوقات میں تبلیغی جماعت کے لٹریچر اور ان کے متعدد بزرگوں کی جانب سے‘ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی مرحوم پر ہونے والی تنقید کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا ہے کہ خود: ’’تبلیغی جماعت کے چھے اصولوں میں کسی جماعت کو مطعون کرنا‘ برا بھلا کہنا شامل نہیں ہے‘‘ (ص ۹۷)۔ لیکن مسلموں اور غیرمسلموں کی تمام تحریکوں کو نظرانداز کرتے ہوئے تبلیغی جماعت کے اکابرکے ہاں جماعت اسلامی ] اور مولانا مودودی[ کے خلاف ایک طرح کی ’’ذہنی جارحیت‘‘ نظر آتی ہے‘‘(ص ۱۴۹)۔ حالانکہ ایسے رویے کی بنیاد مولانا محمد الیاس مرحوم نے نہیں رکھی تھی۔
یہ کتاب مولانا شبیراحمدعثمانی ؒکے بھتیجے اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل مولانا عامرعثمانی مرحوم کے شذرات پرمشتمل ہے‘ جو انھوں نے خداترسی‘ علمی شان‘ اور جرأت ایمانی کے ساتھ تحریر کیے ہیں۔ سید علی مطہرنقوی نے انھیں مرتب کر کے ایک اہم خدمت انجام دی ہے۔ یہ کتاب بالخصوص تبلیغی جماعت کے اکابر واصاغر اور ان کی جدوجہد میں دل چسپی رکھنے والوں کے لیے قابلِ مطالعہ ہے۔ (سلیم منصورخالد)
سفرنامہ واحد صنفِ ادب ہے جس میں داستان کا تحیّربھی ہے اور افسانے کی چاشنی بھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قارئین کی دل چسپی اور پسندیدگی کے پیش نظر گذشتہ ربع صدی میں سفرنامے بکثرت منظرعام پر آئے اور سند قبولیت حاصل کی ہے لیکن نگرنگر گھومنے والے سیاحوں میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنھوں نے دنیا کے تین چوتھائی حصے میں سمندروں کے سفر کیے ہوں اور مشاہدات کو منظرعام پر لائے ہوں۔ (حجاج کے بحری اسفار ایک الگ موضوع ہے)۔
اس حوالے سے زیرنظر سفرنامہ بعض کمزوریوں کے باوجود قابلِ توجہ اور خاصا دل چسپ ہے۔ مصنف پاک بحریہ کے ایک سابق ٹیلی گرافسٹ ہیں۔ انھوں نے بعد میں نیوی مرچنٹ میں بطور ریڈیو افسرطویل عرصے تک مختلف جہازوں پر فرائض سرانجام دیے۔مصنف کو دنیابھرکے سمندروں میں سفر کرنے اور تمام اہم ملکوں کی بندرگاہوں پر جانے اور وہاں قیام کرنے کے مواقع ملے۔ کئی بار دیارِ غیر میں اُس کے آپریشن ہوئے اور طرح طرح کے مصائب کا سامنا بھی رہا اور دل کھول کر لطف بھی اٹھایا۔ مصنف نے تجربات و مشاہدات کو سیدھے سادے انداز میں پیش کیا ہے۔
متلاطم سمندروں میں جہازوں کے عملے (crew) کو کن کن مصیبتوں سے واسطہ پڑتا ہے اور ان مصائب سے ان کی صحت اور مزاج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ڈوبتے جہازوںکی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ کلبوں میں تفریح طبع کے کیا سامان میسر آتے ہیں۔ پھر وطن سے دُور پاکستانیوں کے کیا رویّے ہوتے ہیں؟ اسی طرح کے بہت سے پہلو سامنے لائے گئے ہیں۔
مصنف نے اس کتاب کے مرکزی کردار علی کی نجی زندگی کے مختلف پہلوئوں پر روشنی ڈالی ہے۔ محدود ماحول میں رہنے والے کسی فرد کی نجی زندگی عمومی دل چسپی کا باعث نہیں ہوتی۔ مگر یہاں ایک مخلص‘ فراخ دل اور جذباتی انسان کی آپ بیتی میں دل چسپی کے ساتھ عبرت کے کئی پہلو بھی نظر آتے ہیں۔
علمی و ادبی بڑے مراکز سے دُور ایک قصبے کے باسی مصنف کی یہ پہلی کاوش ہے۔ اس لیے پختہ قلم کاری کا عدمِ وجود تعجب خیز نہیں۔ واقعات کی زمانی ترتیب میں جھول ہے۔املا‘ رموزاوقاف‘ فقروں کی بندش اور تحریر کے دیگر کئی پہلونظرثانی کے مستحق اور توجہ طلب ہیں۔ ایک بھرپورنظرثانی کے بعد یہ کتاب ایک منفرد مقام حاصل کرسکتی ہے۔ (عبداللّٰہ شاہ ہاشمی)
پردے کی بحث میں محترمہ رخسانہ جبیں کے مدلل مقالے ’’آیاتِ حجاب و ستر اورموڈریٹ اسلام‘‘ اور ’’رسائل و مسائل‘‘ (فروری ۲۰۰۳ئ) میں پروفیسرخورشید احمد صاحب کے متوازن جواب نے دلیل‘ یکسوائی اور عدل پر مبنی نقطۂ نظر اختیار کرنے کی راہ سجھائی‘ تاہم مضمون کو ’’عالم نسواں‘‘ کے حصے سے منسوب کرنا مناسب دکھائی نہیں دیتا۔ سماجی علوم کی مردانہ‘ زنانہ تقسیم کو ایک غیرفطری اور غیرمحتاط رویہ کہا جاسکتا ہے۔ مقالات کو اپنے موضوع کے اعتبار سے سماجیات‘ معاشیات‘ سیاسیات‘ نفسیات وغیرہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ’’پردے‘‘ کو عالم نسواں کا مسئلہ قرار دینا درست نہ ہوگا۔ یہ صرف عورتوں کا نہیں بلکہ معاشرے اور تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔
ازراہِ کرم ترجمان القرآن میں قرآنی آیت / آیات لکھتے وقت اختصار اور جگہ کی کمی کو دل میںجگہ نہ دیں۔ پوری آیت یا آیات لکھا کریں۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔
علامہ یوسف القرضاوی کی تحریر ’’انسانی کلوننگ‘‘ (فروری ۲۰۰۳ئ) اپنے موضوع پر ایک جامع اور مفید مضمون ہے۔ خدشہ ہے کہ فرائیڈ کے پیروکار ’’کلوننگ‘‘ کے نتیجے میں بننے والے انسانوںکو اخلاق اور احترامِ انسانیت کا جنازہ نکالنے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس کی فکر کی جانی چاہیے۔
ترجمان القرآن کی تمام تحریروں میں اصلاحی‘ اخلاقی اور دینی رنگ غالب ہوتا ہے۔جس کی وجہ سے ہر ماہ پرچے کا انتظار رہتا ہے۔ خدا کرکے اپنی مقصدیت اور روایات کے ساتھ یہ اِسی طرح روشنی بکھیرتا رہے۔ ’’دل کی زندگی: اعمال کا مدار‘‘ (جنوری ۲۰۰۳ئ) میں حدیث کی تشریح جس طرح سلیس زبان مگر عالمانہ انداز میں کی گئی ہے تعریف کی محتاج نہیں ۔ ’’موڈریٹ اسلام کی تلاش‘‘ (جنوری ۲۰۰۳ئ) سے اندازہ ہوا کہ مغرب کی چال بازیاں کتنی منظم ہیں اور ہم کتنے بے خبر! ’’تحریک اسلامی سینیگال‘‘ (جنوری ۲۰۰۳ئ) پڑھ کر اندازہ ہوا کہ تعلیم کا میدان کتنا اہم ہے مگر ہم اس کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جو اس کا تقاضا ہے۔
’’موڈریٹ اسلام کی تلاش‘‘ (جنوری ۲۰۰۳ئ) میں اغیار کی سازش سے بروقت متنبہ کیا گیا ہے۔ ایف بی آئی کے نام پر معزز شہریوں کو تنگ کر کے چنگیزی دَور کی یاد تازہ ہوگئی۔ اللہ جانے آیندہ یہ کیا کیا گل کھلائے گی۔ شذرات کے ذریعے بروقت گرفت ہوئی۔
’’اشارات‘‘ کے ساتھ شذرات کا اضافہ خوش آیند ہے۔ یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اس سے حکومت کے اقدامات سے آگہی بھی ہوگی اور گرفت اور تنقید بھی۔
ترجمان کی طرزِ ادا مزید سہل بنانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ایف اے تک کے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو۔ اب وہ پہلا سا دور تو نہیں۔ علم کی سطح کافی نیچے چلی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مدیر کا حق تغیروتبدل (معنوی نہیں لفظی) تو اپنی جگہ مسلمہ ہے۔
اشارات (فروری ۲۰۰۳ئ) میں strategy کا ترجمہ تزویر اور اس سے تزویری کیا گیا ہے۔ عربی اور اُردو میں عام طور پر انگریزی لفظ ہی کو الاستراتیجیۃ اور اسٹرے ٹیجی میں بدل جاتا ہے۔ تزویر لفظ زُور سے مشتق ہے۔ قول زور اور زور و بہتان اُردو میں بھی مستعمل ہے۔ تزویر میں بھی یہی معانی پنہاں ہیں۔ تزویر تو خاص طور پر جعل سازی اور دھوکا دہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ’’العملۃ المزوّرۃ‘‘ نقلی سکے کو کہا جاتا ہے۔ انتخابات و معاملات میں دھاندلی کے لیے بھی لفظ تزویر عام استعمال ہوتا ہے۔ اسٹرے ٹیجی اور تزویر میں کوئی بھی قدر مشترک دکھائی نہیں دیتی۔ اس تحریر میں تو structural کا ترجمہ بھی تزویری کر دیا گیا ہے۔ structural اور strategical میں فرق تو ظاہر وباہر ہے۔پھر ان دونوں الفاظ اور تزویر میں بہت نمایاں فرق ہے۔ اگر عربی ترجمہ ہوتا توstructural کے لیے ہیکلی استعمال ہوسکتا تھا۔ اُردو میں ہیئت سے مشتق کیا جاسکتا ہے۔اسی طرح pluralism کا ترجمہ تکثر کیا گیا۔ میری رائے میں تکثرکے بجائے تعدّد زیادہ بہتر ہوتا۔ تکثر میں بڑھوتری اور تکاثر کا مفہوم پایا جاتا ہے۔
اس دعوت کا اثر جہاں جہاں بھی پہنچا ہے‘ اس نے مُردہ ضمیروں کو زندہ اور سوتے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا ہے۔ اس کی اوّلین تاثیر یہ ہوتی ہے کہ نفس اپنا محاسبہ آپ کرنے لگے ہیں۔ حلال اور حرام‘ پاک اور ناپاک‘ حق اور ناحق کی تمیز‘ پہلے کی محدود مذہبیت کی بہ نسبت اب بہت زیادہ وسیع پیمانے پر زندگی کے تمام مسائل میں شروع ہو گئی ہے۔ پہلے جو کچھ دین داری کے باوجود کر ڈالا جاتا تھا وہ اب گوارا نہیں ہوتا بلکہ اس کی یاد بھی شرمندہ کرنے لگی ہے۔ پہلے جن لوگوں کے لیے کسی معاملے کا یہ پہلو سب سے کم قابل توجہ تھاکہ یہ خدا کی نگاہ میں کیسا ہے ان کے لیے اب یہی سوال سب سے زیادہ مقدم ہو گیا ہے۔ پہلے جو دینی حس اتنی کُند ہوچکی تھی کہ بڑی بڑی چیزیں بھی نہ کھٹکتی تھیں اب وہ اتنی تیز ہوگئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کھٹکنے لگی ہیں۔ خدا کے سامنے ذمہ داری و جواب دہی کا عقیدہ اب احساس بنتا جا رہا ہے اور بہت سی زندگیوں میں اس احساس سے نمایاں تبدیلی ہو رہی ہے۔ لوگ اب اس نقطۂ نظر سے سوچنے لگے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ سعی و عمل وہ کر رہے ہیں وہ آیا خدا کی میزان میں کسی قدر و وزن کی حامل ہو سکتی ہے یا محض ھَبَأً مَنْثُورًا بن جانے والی ہے۔ پھر بحمداللہ اس دعوت نے جہاں بھی نفوذ کیا ہے بے مقصد زندگیوں کو بامقصد بنایا ہے اور صرف ان کے مقصدِزندگی ہی کو نہیں بلکہ مقصد تک پہنچنے کی راہ کو بھی ان کی نگاہوں کے سامنے بالکل واضح کر دیا ہے۔ خیالات کی پراگندگی دُور ہو رہی ہے۔ فضول اور دورازکار دلچسپیوں سے دل خود ہٹ رہے ہیں۔ زندگی کے حقیقی اور اہم تر مسائل مرکز توجہ بن رہے ہیں۔ فکرونظر ایک منظم صورت اختیار کر رہی ہے اور ایک شاہ راہِ مستقیم پر حرکت کرنے لگی ہے۔ غرض بحیثیت مجموعی وہ ابتدائی خصوصیات اچھی خاصی قابلِ اطمینان رفتار کے ساتھ نشوونما پا رہی ہیں جو اسلام کے بلند ترین نصب العین کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے اولاً و لازماً مطلوب ہیں۔ (’’اشارات‘‘، ابوالاعلیٰ مودودیؒ، ترجمان القرآن‘ جلد۲۲‘ عدد۳-۴‘ ربیع الاول و ربیع الآخر‘ ۱۳۶۲ھ‘ اپریل ۱۹۴۳ئ‘ ص ۶۸-۶۹)