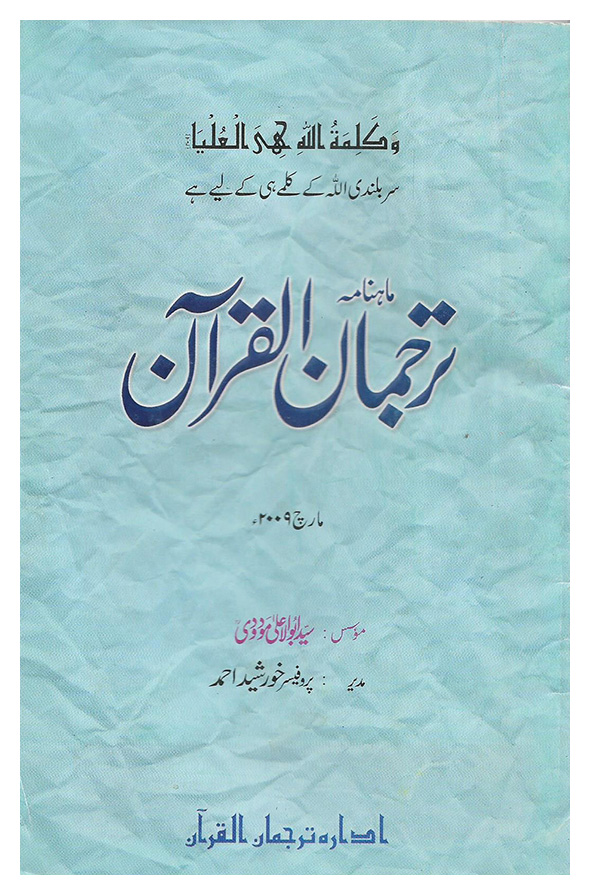
سلیم منصور خالد
|
مارچ ۲۰۰۹
|
مطالعہ کتاب




بے نظیر بھٹو کی زندگی کا آخری سیاسی کارنامہ ’قومی مفاہمتی آرڈی ننس‘ (NRO- National Reconciliation Ordinance) تھا اور آخری کتاب Reconciliation۔ [کتاب کا پورا نام: مفاہمت: اسلام، جمہوریت اور مغرب ہے۔] وہ ۲۷دسمبر ۲۰۰۷ء کی شام جلسۂ عام میں رونما ایک الم ناک حملے میں جاں بحق ہوئیں۔ اگلے روز ۲۸دسمبر کو مارک اے سیگل نے اس کتاب کا دیباچہ لکھا، جب کہ ساتویں روز ۳ جنوری ۲۰۰۸ء کو ان کے شوہر آصف علی زرداری، بیٹے بلاول اور بیٹیوں بختاور اور آصفہ نے کتاب کا اختتامیہ قلم بند کیا۔ ۳۲۸صفحات پر مشتمل یہ کتاب سائمن اینڈ شسٹر نے لندن، نیویارک اور ٹورنٹو سے ۲۰۰۸ء کے اوائل میں شائع کی ہے۔
عجیب اتفاق ہے کہ اس کتاب کا عنوان ہے: ’مفاہمت‘ مگر کتاب کے مندرجات میں کہیں کسی ایک سطر میں بھی مذکورہ ’مفاہمتی آرڈی ننس‘ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، حالانکہ اسی آرڈی ننس کی بنیاد پر نہ صرف ان کی جلاوطنی ختم ہوئی بلکہ ان پر اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر قائم کرپشن کے مقدمات ختم ہوئے اور سیاست میں ان کی واپسی ممکن ہوئی اور اس کے نتیجے میں پیپلزپارٹی کو نئی زندگی اور زرداری صاحب کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صدارت ملی۔ ’مفاہمت‘ (deal) کے بارے میں یہ پُراسرار خاموشی بہت معنی خیز ہے۔
اس کتاب میں جو چیز زیربحث ہے وہ مغرب بلکہ امریکا اور مسلمان ہیں، مسلمان بھی وہ، جنھیں کٹہرے میں کھڑے ملزم بلکہ مجرم بن کر پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کے مباحث کی تکرار، اس میں موجود پیغام کے رنگ اور اس کے اسلوبِ نگارش کو دیکھ کر بسااوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کتاب کا بیش تر حصہ بے نظیر بھٹو کا لکھا ہوا نہیں ہے، تاہم پیپلزپارٹی کے جنرل سیکرٹری جہانگیر بدر نے اس کتاب کو بے نظیر بھٹو کی: ’’وراثت کی آخری کڑی اور نعرئہ حق کی ایسی صدا قرار دیا ہے، جس کی بازگشت آنے والے زمانوں میں بھی گونجتی رہے گی‘‘۔ پاکستان کی ایک اہم سیاسی پارٹی کی رہنما سے منسوب اس کتاب کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں بیان کردہ وژن کو سمجھا جائے، اور جسے وصیت یا وراثت کہا گیا ہے، اس میں پائے جانے والے پیغام کے مضمرات کا احاطہ کیا جائے۔
کتاب میں متعدد مقامات ایسے ہیں کہ ان تحریروں کے اثرات مستقبل پر اثرانداز ہوں گے، اس لیے ضروری ہے کہ حق کی گواہی دی جائے۔ انسانی جان کا قتل جتنا بڑا جرم ہے، کم و بیش اتنا ہی بڑا جرم تاریخ کا قتل ہے۔ علمِ تاریخ، انسانی تجربے، اجتماعی زندگی کے حادثے، اور کارنامے کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا محضرنامہ ہوتا ہے۔ کیا ’مفاہمت‘ کے نام پر ’نفرت‘ کا درس دینا کوئی مناسب عمل ہے؟ اگرچہ کتاب کے دو تہائی مباحث اس امر کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر غور کرکے ان کا بے لاگ تجزیہ کیا جائے۔ مگر زیرنظر صفحات میں اس قدر تفصیل کی گنجایش نہیں، اس لیے ہم اپنے تجزیے کو صرف دو ایک مرکزی موضوعات ہی تک محدود رکھیں گے۔ اس مبحث کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے: ۱-اسلام اور عالمِ اسلام ۲- سید قطب، مولانا مودودی اور جماعت اسلامی۔
یہ درست ہے کہ دینی امور پر بات کرنا کسی فرد کی اجارہ داری نہیں ہے۔ مصنفہ نے اس کتاب میں متعدد جگہ دینی معاملات پر اپنے نتیجہ ٔ فکر کو پیش کیا ہے۔ اپنی بات کہنا ان کا حق ہے، مگر اس میں بہرحال یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ وہ بات درست ہے یا نہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے:
قرآن کی تفسیر میں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ تفسیر کون کر رہا ہے۔ کئی مسلمان، خصوصاً جن کا تعلق مذہبی حکومتوں سے ہے، یقین رکھتے ہیں کہ صرف چند مخصوص لوگوں ہی کو قرآن کی تفسیرکرنے کا حق حاصل ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر کو کسی ایک فرد یا مجلس تک محدود نہیں رکھا گیا۔ قرآن کی تفسیر کرنے کی آزادی ہرمسلمان کو حاصل ہے۔ تمام مسلمانوں کو قرآن کی تفسیر کرنے کا حق دینے کی ضمانت (یعنی حق اجتہاد) حاصل ہے۔ (ص ۶۵)
یہ لطیف نکتہ تو بڑے بڑے روشن خیالوں کو بھی نہ سوجھا تھا کہ قرآن کی تفسیر کرنے کا حق ہرفرد کو ہے۔ علما نے کہیں نہیں کہا کہ تفسیر کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے، بلکہ انھوں نے صرف یہ کہا ہے کہ تفسیر کے لیے علم اور تقویٰ، عربی اور دینی نظائر پر گہری دسترس حاصل ہونی چاہیے، اور جو فرد بھی یہ دسترس حاصل کرلے وہ تفسیر کرسکتا ہے۔علما نے یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ کسی مخصوص نسلی طبقے کو یہ حق حاصل ہے، مگر انھوں نے یہ ضرور کہا کہ قرآن کے مفسر کو دین دار اور خدا ترس بھی ہونا چاہیے۔ مذکورہ پیراگراف میں مصنفہ نے ’اجتہاد‘ کو بھی ہرشہری کا ایسا حق قرار دینے کی کوشش کی ہے، جیساکہ وہ قانون کی تشریح کے لیے علم سے بے بہرہ ہرکس و ناکس کو حق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوسکتیں، آخر یہ آزاد روی صرف دین اسلام کے ساتھ ہی کیوں؟مصنفہ نے برعظیم پاک و ہند میں جن افراد کو علمِ دین کی وضاحت کے لیے نامزد فرمایا ہے، وہ ہیں: ’’مولانا وحیدالدین اور خالد مسعود جیسے زندہ مصلح، جو اپنے جدت پسند علمِ دین کو ریاست کے ظلم وستم یا دھونس کا نشانہ بنائے بغیر پڑھا سکتے ہیں‘‘ (ص ۲۸۴)___ عورتوں کے حقوق پر بحث کرتے ہوئے لکھا گیا ہے:
حقیقت یہ ہے کہ پردے (veil) یا برقعے کا تعلق زیادہ تر قبائلی روایات سے ہے۔ روایت پرست ماضی میں صاحب ِ ثروت خواتین صرف عزیزوں کی شادیوں یا جنازوں میں شریک ہونے کے لیے گھروں سے نکلتی تھیں۔ یہ اُس وقت اِس خطے کا عام چلن تھا، مگر کسی بھی حوالے سے اسلام کی تعلیم نہیں تھا۔ (ص ۴۲)
اگر پردہ کرنا قبائلی روایت کا حصہ ہے تو پھر پردہ نہ کرنا بھی تو کسی قبیلے کی روایت کا حصہ ہوسکتا ہے۔ کیا عہد ِ رسالتؐ و عہدصحابہؓ میں یہ چیزیں محض قبائلی سلسلے کی کڑیاں تھیں یا ان کے لیے قرآن و سنت اور اسلامی روایات کا ایک گراں قدر تسلسل ہمیں رہنمائی دیتا آیا ہے؟ تاہم پردے یا حجاب کی شکلیں مختلف ادوار میں لوگوں کے ذوق اور ضرورت کے مطابق تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ یہ چیز روایت کی اسیری یا دولت کے اظہار کا ذریعہ بھی نہیں تھی۔ مسلمان عورتیں کبھی جنازوں میں نہیں جایا کرتیں۔ اور آخر میں ان کا یہ لکھنا کہ ’’پردہ کسی بھی حوالے سے اسلام کی تعلیم نہیں‘‘۔ ایک بے بنیاد جسارت اور ایک غلط فتویٰ ہے ___ آگے چل کر وہ کہتی ہیں:
عورتوں کے لباس سے متعلق قرآن کی دو بڑی آیات کو حجاب کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور فقہا انھی کو استعمال کر کے عورتوں سے حجاب پہننے کا تقاضا کرتے ہیں--- حالانکہ آیت (الاحزاب:۶۷) خاص رسولؐ کے اہلِ بیت کے لیے ہے۔ (ص ۴۲)
مصنفہ کے نزدیک پردہ صرف بعد کے فقہا کی ذہنی اُپج ہے اور یہ کہ قرآن کا حکم صرف اور صرف رسولِؐ پاک کے اہلِ بیت اور بیویوں کے لیے تھا۔ یہ بصیرت افروز انکشاف، عبرت کے کئی پہلو رکھتا ہے۔ انھوں نے مزید یہ بیان کیا ہے:
جب میں عُنفُوانِ شباب کو پہنچی تو میری والدہ [بیگم نصرت بھٹو صاحبہ] نے مجھ سے برقع (burqa) پہننے کے لیے کہا۔ [یہ سن کر] مجھے اچانک دنیا دھندلائی دھندلائی سی نظر آنے لگی۔ کپڑے کی اِن بندشوں تلے مجھے گرمی اور سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی تھی۔ میرے والد [ذوالفقار علی بھٹو صاحب] نے مجھ پر صرف ایک نگاہ ڈالی اور کہا: ’’میری بیٹی کو پردہ (veil) کرنے کی ضرورت نہیں ہے‘‘۔ میری والدہ نے فیصلہ کیا، اگر یہ پوری طرح لپیٹ لینے والا برقع نہیں پہنے گی تو پھر میں بھی نہیں پہنوں گی۔ اس طرح روایت شکنی کا آغاز ہوا--- اور رسولؐ نے تو کہا ہے کہ بہترین پردہ ’نظر کا پردہ‘ ہے۔ (ص ۴۳)
یہ واقعی انکشاف ہے کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے اپنی بیٹی بے نظیر بھٹو کو برقعہ پہننے کے لیے کہا، مگر بھٹوصاحب نے پردے کی تجویز کو جھٹک دیا اور پھربیگم صاحبہ نے بھی برقع پہننے سے انکار کردیا۔ یوں روایت شکنی کا علَم بلند ہوا۔ اس میں توجہ طلب بات تو یہ ہے کہ بیگم صاحبہ ایک اصفہانی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایران نژاد ماڈرن خاتون تھیں، جو بے نظیر کے سنِ بلوغت سے پہلے بھی کھلے چہرے کے ساتھ، سماجی مجالس میں شرکت کیا کرتی تھیں۔ جب انھوں نے خود برقع پہنا ہی نہیں تو ایسے میں، ان کی جانب سے ردعمل میں آکر برقع چھوڑنے کا اعلان ایک نئی بات ہے۔ اور جو بھٹو صاحب نے کہا یا جس تصور سے بے نظیر لرزاں و ترساں ہوئیں، وہ ان کا ذاتی احساس ہے، اس پر مزید کچھ کہنا لاحاصل ہے، تاہم قرآن، سنت، حدیث اور اسلامی سماجی روایات کو چھوڑ بھی دیں، تب بھی کم از کم ان تین حضرات کے بارے میں کیا کہیں گے جو اپنی وسیع المشربی کے باوجود پردے بلکہ برقعے کے قائل تھے، مراد ہیں: جدیدیت کے حدی خواں سرسیداحمد خاں، روشن خیالی کے ’امام‘ نیاز فتح پوری اور مغرب کے ظاہروباطن کے رازداں علامہ محمداقبال۔ کیا یہ لوگ بھی ’قبائلی طرزِ احساس کے قیدی‘ تھے؟ ___
مسلمانوں میں انتہا پسندی کا کھوج لگاتے ہوئے لکھتی ہیں:
ازمنہ وسطیٰ کے عالم احمد ابن تیمیہ [۱۲۶۲ء-۱۳۲۸ء]نے مسلمانوں اور غیرمسلموں کے درمیان ایک واضح حدِفاصل قائم کی اور کہا: ’’مسلم شہریوں کا یہ فرض ہے کہ ان [غیرمسلموں] کے خلاف بغاوت کریں اور جہاد کریں۔ اس فتوے کو کئی گروہوں نے نقل کیا۔ یوں ان کے نزدیک غیر مسلموں کے خلاف اعلانِ جہاد کرنا جائز ہے۔ (ص ۲۷-۲۸)
پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کو وحشی منگولوں کی بے رحمانہ یلغار روکنے کے لیے تلوار اٹھانا پڑی۔ اسلامی تاریخ کے اس عظیم محسن نے بذاتِ خود اس درندگی کو ایک ایسی سطح پر دیکھا، جس کا مشاہدہ ہمارے مغرب پلٹ اہلِ دانش نہیں کرسکتے۔ ظاہر ہے کہ حالت ِ جنگ اور تلواروں کی بارش میں وہ پھول کی پتیاں تو نچھاور نہیں کرسکتے تھے، بلکہ ایسی صورت حال میں اسلام جو رہنمائی دیتاہے، انھیں اس سے روشنی حاصل کرنا تھی۔ اب یہ مصنفہ یا ان کے مددگار اسکالروں کی تحقیق اور تخیل کی کرشمہ سازی ہے کہ امام ابن تیمیہ کے نزدیک ایک مسلمان کا کام ہروقت، ہر جگہ اورہر حالت میں یہی ہے کہ وہ غیرمسلموں پر جہاد کی تلواریں برساتا رہے۔ آگے چل کر ابن تیمیہ کو ان مجاہدین سے جوڑا گیا جو یہودی، نصرانی اور ہندو استعمار سے آزادی کے لیے مصروفِ جہاد ہیں۔ جو بات امام ابن تیمیہ نے کہی نہیں، اس کے لیے ان کو ذمہ دارکیوں قرار دیا جائے اور ان احوال و ظروف کو نظرانداز کیوں کیا جائے جس میں انھوں نے فتویٰ دیا اور تلوار اٹھانے کی بات کی تھی۔
اکیسویں صدی میں اہلِ مغرب کی تاریخ کروٹ لے رہی ہے، اور وہ سعودی حکمران جو ماضی میں ان کے ہاں ’اعتدال‘ کی علامت قرار دیے جاتے تھے، اب نئی عالمی صف بندی میں ان کے خلاف مغرب کی جانب سے گاہے گولہ باری دیکھنے میں آتی ہے۔ ۱۹۷۳ء میں سعودی فرماں روا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے اسرائیل کی پشت پناہی کرنے پر امریکا کو تیل کی سپلائی روکنے کی بات کی تو امریکی انتظامیہ نے ایک طرف دوستی اور دوسری جانب دشمنی اختیار کرنے کی دو رُخی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے سعودی مملکت کو نفرت کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ اس کے ساتھ دوسرا شکار ’وہابیت‘ ہے۔ گذشتہ ۲۰۰ برس کے دوران مغربی استعماریوں نے ان کی اطاعت نہ کرنے والے مسلمانوں کو ’وہابی‘ کا نام دیا۔ اور ’وہابی‘ لفظ کے ساتھ متعدد بے بنیاد روایات منسوب کر کے مسلمانوں میں عمومی سطح پر نفرت کی آگ بھڑکائی گئی۔ موجودہ سعودی عرب کے علاقے نجد میں شیخ محمد بن عبدالوہاب (۹۲-۱۷۰۳ء) کے رفقا موجود تھے، تاہم بھارت، انڈونیشیا، چیچنیا، افریقہ وغیرہ میں جہاں بھی مسلم سرفروشوں نے گوری اقوام کے استعماری اقتدار کو للکارا تو انھیں وہابی کہہ کر بدنام کیا اور: ’’مارنے سے پہلے دشمن کو بُرا نام دینے‘‘ کی روایت کو آگے بڑھایا۔ مصنفہ نے لکھا ہے:
سُنّی اسلام میں اسلامی سُنّی شریعت کے چار مکاتب ہیں: حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ سُنّی فرقے کے بیج سے ایک اور فرقہ نکل کر اُبھر رہا ہے جنھیں ’وہابی‘ کہا جاتا ہے، جو موجودہ دور میں سعودی عرب میں غالب اکثریت اور قوت رکھتا ہے۔ اس کے بانی محمد بن عبدالوہاب حنبلی مسلک کے پیرو تھے۔ سعودی بادشاہت، خاندانِ سعود پر مشتمل ہے اور وہابیت سلطنت کا سرکاری مذہب ہے۔ وہابیوں نے غیروہابی مسلمانوں کی قبریں مسمار کردیں۔ انھوں نے باجماعت نماز میں شرکت کو لازمی قرار دے دیا۔ وہابی خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ۱۸۰۲ء میں وہابی افواج نے عراق میں کربلا پر قبضہ کرلیا اور اپنے ہتھے چڑھنے والے ہرمعلوم شیعہ مرد، عورت اور بچے کو موت کے گھاٹ اُتار دیا--- وہابیت ایک سخت گیر اور کٹّر مسلک ہے۔ یہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے چند فرقوں کو بھی مرتد قرار دیتا ہے۔ بعض وہابیوں کا کہنا ہے کہ شیعوں کو قتل کرنا ایک مذہبی فریضہ ہے۔ (ص ۵۱)
بلاشبہہ شیخ محمد بن عبدالوہاب کے رفقا نے ایسے مزار مسمار کیے تھے کہ جن پر ضعیف الاعتقادی کے باعث نذرونیاز اور توسّل و التجا کے عمل نے قبرپرستی کے قریب پہنچا دیا تھا مگر اس میں وہابی اور غیروہابی کی تمیز نہ تھی۔ اسی طرح باجماعت نماز کی ادایگی کسی وہابی کا حکم نہیں، بلکہ مردوں کے لیے یہ اللہ کے رسولؐ کا حکم ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھیں۔ ’وہابی سعودیوں‘ کو شیعہ مسلمانوں کا جانی دشمن قرار دینا بھی ایک افسانہ ہے اور کربلا پر ان کی یلغار کا جو نقشہ اس کتاب میں کھینچا گیا ہے وہ بذات خود فرقہ واریت کے شعلوں پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے مغرب کے پالیسی ساز نت نئے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ ہم یہاں پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات پر وقتاً فوقتاً افسوس ناک حملے کرنے والے چھوٹے سے جنگ جُو گروہ کا تعلق اہلِ حدیثوں (’وہابیوں‘) سے نہیں، بلکہ اس گروہ سے ہے کہ جس کے سیاسی گروپ کے ساتھ اکثر پیپلزپارٹی شراکتِ اقتدار کرتی چلی آرہی ہے۔ چونکہ سعودی مملکت اور خاص طور پر سلفیوں کو نشانہ بنانا آج کے مغربی حکمرانوں کو مطلوب ہے، اس لیے خاص طور پر اہلِ مغرب کے اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں کہا گیا ہے کہ وہ ’عیسائیوں اور یہودیوں‘ کے دشمن ہیں۔ یہ اعلان مغربی تھنک ٹینک باربار کررہے ہیں، اور ان کی صداے بازگشت یہاں بھی موجود ہے۔ آگے چل کر لکھا ہے:
ترکی سے پاکستان تک کی مسلم آبادیوں میں مغرب، خصوصاً ریاست ہاے متحدہ امریکا کے لیے تحقیر اور دشمنی کے جذبات روز افزوں ہیں اور عراق کی جنگ [۱۹۹۱ء اور ۲۰۰۳ء تاحال] کو اس کی وجہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ فلسطین کی صورت حال کو ایک اور سبب کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے۔ مغرب کی نام نہاد انحطاط پذیر اقدار کو بھی اکثر ایک حصے کے طور پر شاملِ بحث رکھا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے لیے دوسروں پر الزام دھرنا، اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ [مغرب کے] غیرملکیوں اور نوآبادیاتی حاکموں کی مذمت بڑی آسانی اور بڑی تیزی سے کی جاتی ہے، مگر مسلم دنیا میں اپنے گریبان میں جھانکنے اور اپنی غلطیوں کو پہچاننے کے معاملے میں اتنی ہی کم آمادگی پائی جاتی ہے۔ (ص ۴)
’دانش وری‘ اور ’ٹھنڈے دل و دماغ‘ پر مبنی یہ بیان بھی مسلم دنیا کی مذمت اور امریکی حکومت کے لیے انسانیت سوز اقدامات کی طرف داری کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ اصل بات آخر میں کی گئی ہے کہ مغرب اور نوآبادیاتی حاکموں کی مذمت ’بڑی آسانی اور بڑی تیزی‘سے کی جاتی ہے، مگر ’اپنے گریبان میں نہیں جھانکا جاتا‘۔
حقیقت یہ ہے کہ مسلم دنیا میں اپنی غلطیوں کو پہچاننے ، اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی خرابیوں کو دُور کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ صرف مغرب یا امریکا وغیرہ نہیں، بلکہ امریکا وغیرہ کے وہ دیسی ٹھیکے دار ہیں، جو سیاست اور اقتدار کے سرچشموں پر قابض ہیں، اور جنھیں استعماری حکمرانوں کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ اسی چیز کا شعور رکھتے ہوئے مظلوم مسلمان، اپنے دکھوں کا سبب مغرب کی طاقتوں کو قرار دیتے ہیں اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ جس طرح وہ خود بھی گذشتہ برسوں میں پاکستانی آمر جنرل پرویز مشرف کو خرابی کا سبب قرار دیتی تھیں اور اس کا اہم ذمہ دار مغرب اور امریکا کو قرار دیتے ہوئے ان سے مطالبہ کرتی تھیں کہ وہ مشرف کی پشت پناہی چھوڑ دیں۔ یہ بات عام لوگ کہیں تو غلط، لیکن اگر وہ کہیں تو درست۔ غالباً اسی چیز کو ’خودمختاری‘ کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل یہ بھی لکھا ہے:
دنیا بھر میں ایک ارب مسلمان جنگ ِ عراق پر غم و غصے کے اظہار میں اور اقوامِ متحدہ کی تائید کے بغیر امریکی فوجی مداخلت کے نتیجے میں مسلمانوں کی ہلاکتوں کی مذمت کرنے میں تو یک جا نظر آتے ہیں، مگر اس فرقہ وارانہ خانہ جنگی پر، جو اس سے کہیں زیادہ ہلاکتوں کا موجب بنی ہے، ایسے غم و غصے کا اظہار نہ ہونے کے برابر ہے۔ مسلم قائدین، عوام اور یہاں تک کہ دانش ور بھی شرم ناک طور پر اپنے برادر مسلمانوں کو بیرونی عناصر کے ہاتھوں پہنچنے والے نقصان پر تنقید کرنے میں خاصی سہولت محسوس کرتے ہیں، مگر [اس کے برعکس] جب مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر تشدد کی بات آتی ہے تو [ان پر] موت جیسی خاموشی چھا جاتی ہے۔ (ص ۳)
مسلمانوں کا زوال محض نوآبادیاتی نظام کی ناانصافی یا طاقت کی عالمی تقسیم کی وجہ سے نہیں ہوا۔ مسلم معاشروں کو خود بھی ذمہ دار اور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مسلم ممالک کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ (ص ۳۰۰)
چلیے، ان کم ظرف مسلمانوں کو تو مطلوبہ تنقید کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی، مگر اس کتاب کے اوراق پر یہ کارِعظیم بار بار کیا گیا ہے۔ کہاں عراق اور افغانستان میں مجموعی طور پر ۲۶لاکھ مسلمانوں کا قتل (جس میں پہلے روسی کمیونسٹ فوجوں کے ہاتھوں ۱۳ لاکھ افغانوں کے لیے موت اور پھر ۲۰۰۱ء کے بعد ان دونوں ملکوں میں مزید ۱۳ لاکھ بے گناہ انسانوں کا بہیمانہ قتل اور وہ بھی کسی ثبوت کے بغیر)۔ اس قتل پر احتجاج کرنے میں اس لیے مستقبل کے ’مسلم حکمران‘ لوگ خاصے محتاط ہیں کہ اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھنے کے لیے امریکا بہادر کی خوش نودی میں رخنہ آئے گا۔ مسلم دانش پر ماتم کناں مصنفہ کو یہ بات بھول گئی کہ جو فرقہ وارانہ خانہ جنگی انھیں نظر آرہی ہے، وہ المیہ بھی دراصل اسی امریکی قبضے و یلغار اور مقامی لوگوں کا حق حکمرانی سلب کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے مسلم دانش اس المیے کو الگ حقیقت، جب کہ امریکی فوجی مداخلت اور اس سے پیدا شدہ وحشت و درندگی کو دوسری چیز سمجھتی ہے، تاہم مبالغہ آمیز فرقہ واریت کے افسانوی تذکرے سے بھری پڑی مسلم دنیا اسی کتاب کے اوراق پر نظر آتی ہے، حقائق کی دنیا میں نہیں:
مسلم دنیا کے اندر فرقوں، نظریوں اور اسلام کی تشریحات کے مابین ایک اندرونی خلیج، ایک متشدد محاذ آرائی موجود ہے، اور ہمیشہ موجود رہی ہے۔ اس تباہ کن کشیدگی نے بھائی کو بھائی کے خلاف لاکھڑا کیا ہے۔ آج مسلمانوں کے مابین یہ فرقہ وارانہ تشدد اس مجنونانہ، اور اپنی ہی جڑوں کو کاٹنے والی فرقہ وارانہ خانہ جنگی میں پوری طرح نظر آتا ہے۔ اور مسلم دنیا میں فرقہ واریت ہر موڑ پر نظر آتی ہے۔ (ص ۲)
میرے اس موقف کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہمارے جدید دور کے اہم ترین تصادم اسلام اور مغرب کے درمیان نہیں، بلکہ اسلامی ریاستوں کے اندر اعتدال پسندوں اور جدیدیت کی قوتوں اور انتہا پسند اور جنونی قوتوں کے درمیان داخلی لڑائیوں کی صورت میں رونما ہوئے ہیں۔ (ص ۲۵۶)
مسلم دنیا، نظریوں اور فرقوں کی ایسی کسی عالم گیر اور متشدد محاذ آرائی کی تصویر پیش نہیں کرتی۔ اختلاف ہمیشہ اور ہر معاشرے میں رہا ہے، لیکن یہ گلے کاٹنے کا بحیثیت مجموعی ہولناک منظر یا تو اس کتاب میں نظر آتا ہے یا پھر سیکولر حلقوں کی اس خواہش کا پرتو ہے کہ دین کو اور دین دار طبقے کو بُرا کہنے کے لیے یہ بہانا تراشا جائے کہ دین اسلام تو بس فرقہ وارانہ لڑائیوں کا مذہب ہے۔ جس جنگ یا قتل و غارت کو کتاب میں پوری مسلم دنیا کا سرطان قرار دیا گیا ہے، وہ الم ناک فضا ’مہذب‘ امریکا اور اس کے اتحادیوں اور مسلم دنیا میں اس کے باج گزار حکمرانوں کی حکمت عملیوں کا نتیجہ ہے، اور وہ افسوس ناک صورت حال بھی انھی علاقوں میں ہے جہاں انھوں نے استعماری قبضہ جما رکھا ہے___ وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے:
۱۱ ستمبر ۲۰۰۱ء کے حملوں نے تصورِ خلافت سے تحریک حاصل کرنے والی خوں ریز محاذآرائی کے ہراول دستے، یعنی صلیبی جنگوں کی آمد کا اعلان کیا۔ جب جڑواں ٹاوروں کے جلنے اور منہدم ہونے کی تصویر ٹیلی وژن پر دکھائی گئی تو مسلم دنیا میں اس کا خیرمقدم دو مختلف طریقوں سے کیا گیا: ایک بڑی تعداد کا، اگرچہ بہت بڑی تعداد نہیں، ردِعمل خوف، خفت اور شرمندگی کا تھا، جب [اس پر] یہ واضح ہوا کہ تاریخ میں دہشت گردی کا یہ سب سے بڑا واقعہ اللہ اور جہاد کے نام پر مسلمانوں کے ہاتھوں انجام پایا ہے۔ مگر ایک ردعمل اور بھی تھا اور وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے فلسطین کی گلیوں میں خوشی سے رقص کیا، کچھ نے پاکستان اور بنگلہ دیش میں مٹھائیاں بانٹیں… (ص ۳)
۱۱ستمبر ۲۰۰۱ء کے المیے پر دنیا کے کسی مسلمان ملک یا شہر نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اگر فلسطین کے کسی شہری نے اسرائیلی مظالم کے دکھ سہتے سہتے، اس کے پشتی بان کو پہنچنے والے نقصان پر لمحہ بھر کے لیے کوئی مسرت کا اظہار کردیا، تو اسے ایک ارب اور ۳۰ کروڑ مسلمانوں کے ’ذہنی افلاس‘ کا حوالہ بنانا ظلمِ عظیم ہے۔ اس سانحے کو تو آج تک کسی ذمہ دار مسلمان لیڈر نے ’اللہ اور جہاد‘ کا مظہر قرار نہیں دیا۔ حادثے کے چند گھنٹوں کے اندر اندر امریکی صدربش نے اسامہ اور افغانستان سے اس کا رشتہ جوڑ ڈالا، اور تقریباً ۹ برس گزر جانے کے باوجود آج تک کسی کھلی عدالت میں اس الزام کو جرم کے طور پر ثابت نہیں کیا جاسکا۔ البتہ کروڑوں مسلمانوں پر الزام تراشی اور لاکھوں پر کسی تامّل اور جواز کے بغیر تعزیر جاری کرنے کا کام ضرور کیا گیا۔ بعدازاں مسلم دنیا میں امریکی مظالم کے خلاف جو ردعمل سامنے آیا، اس میں صرف مسلمان ہی نہیں، پوری دنیا کے خوددار، غیرت مند اور بہادر انسان شریک ہیں، جنھوں نے رنگ و نسل اور قوم و مذہب کی تفریق سے بالاتر رہتے ہوئے، افغانستان اور عراق پر امریکا اور اس کے اتحادیوں کی بدترین بم باری اور قتل و غارت گری کی نہ صرف مذمت کی، بلکہ جب بھی ان قاتل فوجوں کو نقصان پہنچا تو انھوں نے سُکھ کا سانس لیا۔ اس لیے امریکی فوجیوں سے ہمدردی اور مسلم اُمہ کی مذمت کا یہ یک طرفہ فتویٰ عدل سے خالی، حقائق سے رُوگردانی اور بے رحمانہ خود مذمتی کی دلیل ہے۔ اسی طرح ’صلیبی جنگوں‘ کی اصطلاح کو صدربش نے استعمال کیا تھا، کسی مسلمان لیڈر نے نہیں۔
کتاب میں مسلک دیوبند کے بارے میں درج یہ اقتباس بھی دل چسپ ہے:
دیوبند مسلک ایک قدامت پسند فرقہ ہے۔ دیوبندی، مسلم اقدار پر مغربی اثر کے حوالے سے متفکر رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ’مغربی‘ بننے کے بجاے ’مسلمانوں کو اپنی پہچان، برقرار رکھنی چاہیے۔ یہ حنفی مسلک کی پیروی کرنے اور غیراسلامی افعال ترک کرنے کے حامی ہیں۔ (ص ۵۱- ۵۲)
حقیقت یہ ہے کہ دیوبندی ہی نہیں، یہاں کا ہر دین دار اپنے آپ کو مغرب کے فکری اور اعتقادی رنگ میں رنگنے کو دین کے تقاضوں کے منافی سمجھتا ہے، غیراسلامی افعال کو ترک کرنے کی تلقین اور تربیت کرتا ہے۔ اس بنیادی بات کو صرف اہلِ دیوبند سے منسوب کرنا، مشاہدے کی خامی، دین سے وابستگی رکھنے والے عام مسلمانوں کے بارے میں معلومات کی کمی اور دینی تعلیمات کے تقاضوں کو سمجھنے میں سوے فہم کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے۔ پھر یہ لکھنا کہ:
دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ دینی اور دنیاوی معاملات کے درمیان کوئی حدِفاصل نہیں، اور یہ کہ اسلام زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے۔ جنوبی ایشیا میں داخلے کے لیے وہابی تحریک ایک عرصے سے دیوبندی مدرسوں میں سرمایہ کاری کرتی چلی آرہی ہے۔ (ص ۵۲)
دین اور دنیا کی تفریق کا قائل مغرب ہے، اسلام نہیں، بقول اقبال: ’جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی‘۔ اسلام کا سارا معاشی وعدالتی اور وراثتی نظام ایسی تفریق و تقسیم کو کسی درجے میں بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے اسلام اہلِ مغرب کی خواہش کے مطابق دو رنگی کا شکار نہیں ہوسکتا۔ اسی یک جائی فکر کو اہلِ مغرب کبھی ’انقلابی اسلام‘ اور کبھی ’سیاسی اسلام‘ کا نام دیتے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ تاہم، اس ذیل میں دیوبند سے منسلک سب سے بڑی تبلیغی جماعت اور تصوف کے سلسلوں کا مسلک ’دین و دنیا‘ کے تعلق پر خاصا مختلف ہے، مگر اس نقطۂ نظر کو نظرانداز کردیا گیا ہے۔ آگے چل کر لکھا ہے:
مجھے خاص طور پر یاد آتا ہے کہ دہشت گردی کے نیٹ ورک ’الرشید‘ [ٹرسٹ] نے افغانستان کے طالبانی علاقوں میں جابجا تندور، یعنی اوون بیکریاں قائم کر رکھی تھیں۔ ہرروز مائیں اور باپ ان بیکریوں پر آکر اپنے گھرانوں کے لیے مختص کردہ ہرفرد کے لیے ۳،۳نان لے کر جاتے۔ یہ خاندان بھوک سے مر رہے تھے، اب [’الرشید‘ کے طفیل] ان کے پیٹ بھرنے لگے تھے۔ ’الرشید‘ کی قائم کردہ ہر تندور بیکری میں اسامہ کی تصویر آویزاں ہوتی تھی، جو ماں باپ اس روٹی کا راشن یہاں سے حاصل کرتے، وہ اس کا کریڈٹ اسامہ بن لادن کو دیتے۔ (ص ۳۰۴- ۳۰۵)
یہ بیان بھی کذب آمیز رنگین بیانی کا شاہکار ہے۔ دیوبندی مسلک سے وابستہ ایک رضاکار تنظیم افغانستان کے بے آب وگیاہ ویرانوں میں ایسے کتنے تندور قائم کرسکتی تھی کہ انھیں افغانوں کی پوری نسلوں کو روٹی کے بدلے دہشت گردی کی فوج کا سپاہی بننے کا سبب قرار دیا جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ’الرشید‘ والے اپنے رسالوں اور کتابوں میں خود اپنے بانی کی تصویر چھاپنے کو درست نہیں سمجھتے، تو بھلا اسامہ کی تصویر کو کیوں اپنی رضاکارانہ خدمت کا حوالہ بنائیں گے۔ یہ جھوٹ کسی مغربی پروپیگنڈا ٹکسال میں گھڑا گیا، جسے مبالغہ آمیز وسعت دے کر یہاں تھوپ دیا گیا ہے، اور ان کے تمام تر رفاہی و تعلیمی نیٹ ورک کو تباہ کرنے کے جواز کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ نائن الیون کمیشن رپورٹ کی سفارشات (باب ۱۲) میں متعین طور پر یہ کہا گیا ہے: مسلمانوں کی رفاہی تنظیموں کی شہ رگ کاٹ دی جائے، مسلم عورتوں میں آزاد روی کے فروغ کے لیے ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ثانوی درجے تک تعلیم پر مسلم ریاستوں کا کنٹرول کمزور بلکہ ختم کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ پہلے نکتے کی تکمیل کے لیے مذکورہ بالا مثال پیش کرنا سمجھ میں آتا ہے___ مصنفہ نے بیان کیا ہے:
امریکی اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے تعلیمی اور ثقافتی تبادلے کے پروگرام کی بدولت ہزاروں غیرملکی نوجوان ، جن میں سے کئی ایک کو آگے چل کر اپنے اپنے ملک کی قیادتیں سنبھالنی تھیں، امریکا پڑھنے، سیر کرنے، اور سیکھنے کے لیے آئے۔ اور جب یہ لوگ واپس [اپنے ممالک میں] پہنچے تو ہمیشہ آزاد اور قابل مواخذہ معاشروں کے مبلّغ بن کر سامنے آئے۔ وہ جو صدارت اور وزارتِ عظمیٰ کے عہدے تک پہنچے مجھ جیسے لوگ، انھوں نے تعلیم کے دوران میں حاصل ہونے والے جمہوری، صنفی مساوات اور آزادیِ اظہار کے اسباق کو اپنی اقوام کے طرزِعمل پر لاگو کیا۔ اپنے ساتھی [امریکی] طالب علموں کے ساتھ ہمارے گرم جوشانہ تعلقات آج بھی زندہ ہیں۔ اس لیے نوجوان لیڈروں کو مطالعاتی دوروں پر یہاں [امریکا] لانے اور یہاں کے خاندانوں کے ساتھ ٹھیرانے سے انھیں اپنی آنکھوں سے مغربی زندگی کا مشاہدہ کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ (ص ۳۱۲- ۳۱۳)
کتاب میں جگہ جگہ اسی طرح کے مشورے امریکی حکومت کو دیے گئے ہیں۔ شاید مصنفہ کو علم نہیں تھا (مگر مغرب سے قربت رکھنے والی مصنفہ کیوں کر لاعلم ہوسکتی ہیں؟) کہ یہی تجاویز اور کم و بیش انھی الفاظ اور انھی اہداف کے ساتھ، عرب اور مسلم دنیا کے مستقبل کو قابو کرنے کے لیے اکتوبر ۲۰۰۳ء میں امریکی ایوانِ نمایندگان کی رپورٹ Changing Minds Winning Peace میں امریکی سفیروں، دانش وروں اور The Muslim World after 9/11 میں رینڈ کارپوریشن ۲۰۰۴ء نے پیش کی تھیں، جن کو مؤثر ’تریاق زہر‘ سمجھ کر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ پیش نظر یہی رکھا گیا ہے کہ: مسلمان اقوام کو امریکی مرضی کے تابع بنانے کے لیے وہاں کے مؤثر طبقوں کی اولادوں کو یہاں لاکر ذہنی غسل دیا جائے اور یہاں کی تہذیب کا دل دادہ بنایا جائے، اور یہاں کے ’لوگوں‘ [غالباً خفیہ ایجنسیوں] سے مضبوط رابطے قائم کرائے جائیں،تاکہ وہ واپس جاکر، بدلے ہوئے دل و دماغ اور تطہیرشدہ فکرونظر کے ساتھ اپنی ریاستوں کو امریکا کے تابع بناسکیں___ آگے بڑھیں تو انکشاف ہوتا ہے:
مغرب میں مسلمانوں کا معیارِ زندگی غیرمعمولی حد تک بلندہے۔ بہت سی جگہوں پر یہ غیرمسلموں کے برابر یا ان سے بھی بلند تر ہے… مسلمانوں نے ان مغربی ممالک میں نہ صرف اپنے لیے خیرمقدمی جذبات محسوس کیے، بلکہ کوئی انکار نہیں کرے گا کہ انھیں وہاں اپنے مذہب اور ثقافت پر عمل پیرا ہونے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ (ص ۳۱۵)
اس بیانیے کو ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو یہ کسی امریکی سفارت خانے کے پروپیگنڈا پمفلٹ کے ایک ٹکڑے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ ’چند مسلمانوں‘ کو مجموعی طور پر وہاں محنت مشقت کرنے والے لاکھوں مسلمانوں کی حالت زار کی بہتری سے تشبیہہ وہی قارون دے سکتا ہے، جو خود اپنی آسایش و آسودگی کے مماثل سبھی لوگوں کو سُکھ چین کی زندگی گزارتے ہوئے محسوس کر رہا ہو۔ آج مغرب اور امریکا میں مسلمانوں کی عظیم اکثریت قدم قدم پر جس مذہبی و سماجی تعصب کا شکار ہے، جس طوفانی پروپیگنڈے کا ہدف ہے اور جس کے نتیجے میں کم و بیش ہرمسلمان مشکوک انسان قرار پا رہا ہے، بھلا ایسے میں کون کہہ سکتا ہے کہ وہاں رہنے والے: ’’مسلمانوں کا معیارِ زندگی غیرمعمولی حد تک بلند ہے‘‘۔ اپنے استدلال کے لیے ہم مختلف مثالوں اور خود مغربی آرا پر مبنی سروے رپورٹوں سے نظائر پیش کرنے کے بجاے، سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ: ’مذہب اور ثقافت پر عمل کرنے کی مکمل آزادی‘ کا کون سا نمونہ ہے کہ مغرب ایک مسلمان بچی کے سر پر ڈیڑھ فٹ کا اسکارف بھی برداشت نہیں کر رہا، مگر دوسری طرف مکمل عریانی کو وسعتِ نظر قرار دے رہا ہے۔ کتاب کے اختتامی اوراق میں اس بیانیے سے کون سا پیغام دینا مقصود ہے؟
بھارت سے مرعوبیت تو کئی حوالوں سے اس کتاب کا حصہ ہی ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ تواریخ کا حوالہ بھی غلط درج کیا جائے۔ لکھا ہے:
بھارت نے ۱۹۴۹ء میں دستور منظور کیا اور ۱۹۴۹ء ہی میں عام انتخابات منعقد کرائے، جب کہ پاکستان میں پہلے عام انتخابات ۱۹۷۰ء میں ہوئے۔ (ص ۱۶۹)
پہلی بات یہ ہے کہ بھارتی دستور ۲۶نومبر ۱۹۴۹ء کو منظور اور ۲۶ جنوری ۱۹۵۰ء کو نافذ ہوا، اور عام انتخابات ۱۹۵۱ء میں ہوئے۔ جہاں تک دستورِ پاکستان کا تعلق ہے اس کی منظوری میں بیوروکریسی کی سازش اور دستور ساز اسمبلی کے جاگیردار ارکان کی عدم دل چسپی نے مسلسل روڑے اٹکائے، تاہم جب ۱۹۵۶ء میں دستور پاکستان منظور ہوکر نافذ ہوگیا اور ۱۹۵۹ء کے اوائل میں عام انتخابات کی راہ ہموار ہوگئی، لیکن اس مرحلے تک پہنچنے سے قبل ہی میجر جنرل اسکندر مرزا نے بحیثیت صدر، ۷ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو ملک میں مارشل لا نافذ کرکے جنرل ایوب خان کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا، دستور پاکستان کو منسوخ کیا اور ۲۴ اکتوبر کو جمہوریت پر شب خون مارنے والے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی آٹھ رکنی کابینہ میں ذوالفقار علی بھٹو نامی نوجوان ایڈووکیٹ بھی شامل تھے۔ پھر ۲۸ اکتوبر کو دوبارہ وزارت تشکیل دی تو اس میں بھی بھٹوصاحب کو وزیر مقرر کیا گیا، جو جون ۱۹۶۶ء تک فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے دست ِ راست بنے۔ بے نظیر صاحبہ نے اس کتاب میں جمہوریت کی پامالی کا بہت رونا رویا ہے۔ مقامِ عبرت ہے کہ جمہوریت کے قتل میں اور ان کے والد ِ گرامی، فوجی ڈکٹیٹر کے ساتھ شامل تھے۔
کتاب میں تاریخ کے ساتھ مختلف مقامات پر دل چسپ کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس مناسبت سے بہت سی متنازع فیہ باتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ چند سطریں ملاحظہ ہوں:
تحریکِ پاکستان پر لکھی جانے والی کتابوں میں قائداعظم کے لاڑکانہ کے دوروں کا سراغ نہیں ملتا۔ نومبر ۱۹۶۹ء کے برعکس یحییٰ خان کا مارشل لا دسمبر ۱۹۷۱ء تک ہی نہیں، بلکہ بعد میں بھٹوصاحب کے دورِ حکومت میں۱۹۷۲ء تک جاری رہا۔ شیخ مجیب تو ضد میں جتنا اَڑے رہے، وہ اپنی جگہ ایک المیہ ہے، لیکن فروری ۱۹۷۱ء میں خود بھٹوصاحب نے ’اُدھر تم، اِدھر ہم‘ اور ’’۳ مارچ [۱۹۷۱ء] کے طے شدہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے مغربی پاکستان سے جو رکن اسمبلی ڈھاکا گیا، مَیں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا‘‘ جیسی دھمکیاں دے کر جنرل یحییٰ کی فوجی جنتا کے ہاتھ مضبوط کیے،اس پر دبائو ڈالا اور یکم مارچ کو اجلاس ملتوی کرا دیا۔ اس اعلان سے مشرقی پاکستان میں لاکھوں غیربنگالیوں کو موت کے گھاٹ اُتارنے کا سامان کیا گیا۔ اور پھر جب ڈھاکا میں جنرل یحییٰ خاں نے فوجی ایکشن کا حکم دیا تو اُس وقت جنرل موصوف سے ملاقات کر کے نکلنے والے آخری فرد کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا۔
اس بے رحمانہ فوجی ایکشن کے چندگھنٹوں بعد بھٹوصاحب نے مغربی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی یہ بیان دیا: ’’خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا‘‘۔ (روزنامہ مساوات اور روزنامہ نواے وقت، لاہور، ۲۷ مارچ ۱۹۷۱ء) اور جس پاکستانی فوج کو دو ہفتوں کے اندر اندر اُکھاڑ پھینکنے کی بات کی گئی ہے، وہ عملاً چھے ماہ سے بغیر تازہ کمک کے لڑ رہی تھی، جسے تین اطراف سے بھارتی فوج، روسی مدد، کمیونسٹ گوریلا فورس اور مکتی باہنی گھیرے ہوئے تھی۔ اسی طرح ۹۰ہزار فوجی، جنگی قیدی نہیں بنے تھے، بلکہ لگ بھگ ۴۵ہزار فوجی قید ہوئے تھے___ درمیان کی کڑیوں کو اُڑا کر اور من پسند واقعات کو بلاسیاق و سباق نمایاں کرکے بیان کرنا تاریخ نگاری نہیں، دیانت سے عاری منفی پروپیگنڈا ہے۔
وطن عزیز میں یہ ایک غلط روایت ہے کہ حکومتیں نصابِ تعلیم پر طبع آزمائی کرنا اپنا حق سمجھتی ہیں۔ اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے جنرل ضیا الحق نے بھی نصابِ تعلیم کو دو مرتبہ ترمیم و اضافے کی مشق سے گزارا۔ مگر یہ کام فوج کے ہیڈکوارٹر نے نہیں بلکہ ’صوبائی نصابی بورڈوں‘ اور ’قومی نصابی ادارے‘ نے کیا تھا۔ وہ کتابیں آج بھی دیکھی جاسکتی ہیں کہ ان میں کس ’جرم‘ کا کتنا ارتکاب کیا گیا۔ اب زیرتبصر کتاب کا یہ حصہ ملاحظہ کیجیے:
جنرل ضیاء اپنے انتہا پسند اتحادیوں کا وفادار دوست ثابت ہوا، اس نے اسکولوں کی نصابی کتابوں کو بھی تبدیل کردیا اور تحریکِ پاکستان اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں ان کے منفی کردار کو سفید چولا پہنا دیا۔ نصاب میں شامل ہونے والی کتب پاکستان میں فوجی حکومت کی حمایت کرتیں، ہندوئوں کے خلاف نفرت پھیلاتیں، [مسلم] جنگوں کو شان و شوکت کا مظہر بناکر پیش کرتیں اور پاکستان پر مشتمل علاقے کی ۱۹۴۷ء سے پہلے کی تاریخ کو مسخ کرکے پیش کرتیں۔ (ص ۱۸۹)
یہ سارا بھاشن، اصل میں امریکی حکومت کی اس ’فکرمندی‘ کا مبالغہ آمیز اظہار ہے کہ جس کے تحت پاکستان ہی نہیں، بلکہ پورے عالمِ اسلام کے تعلیمی اداروں میں پڑھائے جانے والے نصاب کو گذشتہ ۹برس سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں ایس ڈی پی آئی کی بدنامِ زمانہ رپورٹ میں قومی نصابِ تعلیم کو ہدف بنا کر یہ ثابت کیا گیا تھا کہ: ’’دو قومی نظریے کی تدریس یہاں پر انتہاپسندی کو پروان چڑھا رہی ہے‘‘۔ پھر یہ کہا گیا کہ: ’’محمدبن قاسم اور پاک بھارت جنگوں میں نشانِ حیدر لینے والے کرداروں کے حالات پڑھ کر بچوں میں بھارت سے دشمنی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ‘‘۔ ۱۹۴۷ء سے پہلے کی تاریخ کے بارے میں کہا گیا کہ: ’’نصابی کتابیں پڑھ کر طالب علموں میں برطانیہ کے نوآبادیاتی دور کے حوالے سے انگریزوں کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں‘‘۔ یہ سب باتیں جنرل پرویز مشرف کے دورِ حکومت (۱۹۹۹ء-۲۰۰۸ء) میں، امریکی منشا کے مطابق مشتہر کی گئی تھیں۔ مذکورہ بالا اقتباس بھی انھی خیالات کی نمایندگی کر رہا ہے۔
پیپلزپارٹی، مسلم لیگ (ن) کی اتحادی اور ’اعلانِ جمہوریت‘ پر دستخط کرنے والی ایک حلیف پارٹی ہے۔ گذشتہ پانچ برسوں کے دوران میں میاں محمد نوازشریف نے پیپلزپارٹی کے کسی سابقہ دورِحکومت کو کسی شکوے اور طعنے کا موضوع نہیں بنایا، مگر اس کتاب میں ایک حلیف ہونے کے باوجود نوازشریف مسلسل سوقیانہ تنقید کا نشانہ بنے نظر آتے ہیں۔ بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، تاہم صرف ایک مثال دیکھیں: ’’نواز شریف نے آئی ایس آئی کو طالبان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے فروغ کی اجازت دے رکھی تھی‘‘ (مفاہمت، ص ۲۱۱)۔۱؎ ان امور پر وضاحت پیش کرنا مسلم لیگ (ن) کی ذمے داری ہے، تاہم مصنفہ کتاب میں طالبان حکومت کی آمد کا پورا ملبہ فوج اور میاں نوازشریف پر ڈال کر اپنا دامن جھاڑ کر الگ جاکھڑی ہوئی ہیں۔ مگر کیا غلط بیانیوں سے تاریخی حقائق کا چہرہ مسخ کیا جاسکتا ہے؟
واقعاتی ترتیب دیکھیں تو ۱۹۹۳ء کے وسط میں پیپلزپارٹی نے صدر غلام اسحاق خاں اور فوج کی مدد سے وزیراعظم میاں نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کرادیا، پھر ۱۹۹۳ء میں ہونے والے انتخابات میں اکثریت حاصل کی اور نومبر ۱۹۹۶ء تک بلاشرکت غیرے حکومت کی۔ دوسری طرف نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ: ۱۹۹۴ء کے اوائل میں طالبان پارٹی کے طور پر وجود میں آتے اور نومبر ۱۹۹۴ء میں وہ قندھار کا کنٹرول سنبھالتے ہیں۔ ستمبر ۱۹۹۵ء میں ہرات ان کے زیرنگیں ہوتا ہے اور ستمبر۱۹۹۶ء میں وہ کابل پر قبضہ کرلیتے ہیں___ اس پورے عرصے میں پیپلزپارٹی کے وفاقی وزیرداخلہ میجر جنرل نصیراللہ بابر بڑے فخریہ انداز سے اس آپریشن کی سرپرستی کرتے نظر آتے ہیں اور خود پیپلزپارٹی کی حکومت بھی خوش نظر آتی ہے کہ اس نے مجاہدین کا ’علاج بالمثل‘ کرکے انھیں بے اثر کردیا ہے۔ امریکی حکومت بھی پیپلزپارٹی کے ذریعے طالبان کے اس طلوع میں مددگار بنتی اور سُکھ کا سانس لیتی ہے۔ ان حقائق سے کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ اُس زمانے میں فوجی قیادت سے ان کے تعلقات خوش گوار تھے۔ موصوفہ نے اعتراف کیا ہے:
اپنے دوسرے دورِ حکومت [۹۶-۱۹۹۳ء] میں فوج کے سربراہوں جنرل وحید کاکڑ اور جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے… اسی طرح جب تک جنرل جاوید اشرف قاضی آئی ایس آئی کے سربراہ رہے، اس وقت تک آئی ایس آئی سے بھی میرے اچھے تعلقات تھے۔ (ص ۲۰۸)
تاریخ پر نظر ڈالیں تو طالبان کا آغاز، طلوع اور افغانستان پر قبضہ، پیپلزپارٹی کے دورِحکومت میں ہوا، مگر ان کی ذمہ داری صرف فوج اور نواز شریف پر ڈالتے ہوئے یوں دامن بچالینے کو کسی طرح بھی معروضی عمل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یاد رہے کہ پروفیسر برہان الدین ربانی اور گل بدین حکمت یار کو ۱۹۷۳ء ہی کے وسط میں وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اعتماد میں لے کر افغانستان میں کمیونسٹ روس اور بھارت کے گہرے اثرات کو نشانہ بنانے کا کام شروع کردیا تھا جب سردار دائود نے ظاہرشاہ کا تختہ اُلٹ کر حکومت پر قبضہ جمایا تھا۔ افغانستان پر بھارتی اور روسی گرفت کو کمزور کرنے کے لیے بھٹوصاحب کے رابطہ کار کی ذمہ داری جنرل نصیراللہ بابر ہی ادا کررہے تھے۔ (جاری)