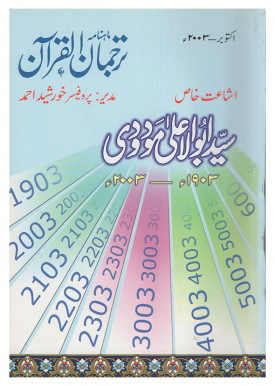
اوریا مقبول جان
|
اکتوبر ۲۰۰۳
|
بھٹکے ہوئے آہو کو‘ پھر سوے حرم لے چل




مغرب کی نماز ختم ہوتی تو وہ کرسی اٹھا دی جاتی جس پر بیٹھ کر وہ نماز ادا کرتے تھے۔ملازم مصلیٰ تہہ کرنے کے لیے واپس پلٹ رہا ہوتا تو میں بھاگ کر اُس جاے نماز پر جاکھڑا ہوتا‘ جس نے ابھی چند لمحے پہلے اُس نابغۂ روزگار شخصیت کے نرم و نازک پائوں چھوئے تھے۔ ذیلدار پارک کے گھر کے برآمدے میں جالی دار دروازے سے لے کر برآمدے اور لان میں بچھی ہوئی صفوں تک ‘میں اُس شخص کی طرف ٹکٹکی لگائے حیرت سے دیکھ رہا ہوتا!
کئی بار میں خود سے سوال کرتا کہ اس چہرے میں ایسی کیا جاذبیت ہے کہ آنکھ اُس سے ہٹتی ہی نہیں‘ گھنٹوں دروازے کے باہر لان میں اُس کی آمد کا انتظار کرتی ہے اور واپسی تک اُس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ کوئی ایسی عمر بھی نہیں کہ کسی ایسی شخصیت کی محبت میں گرفتار ہوا جائے جو مروّجہ اصولوں اور خوابوں کے بنائے ہوئے پیمانوں میں کسی طور پر بھی ہیرو کے سانچے میں نہیں ڈھل پاتی۔ لیکن اس عشق سے چند سال پہلے کی میں اپنی جستجو پر نظر ڈالتاتو جواب مل جاتا۔ مجھے اس جاے نماز‘ ان قدموں کی چاپ اور اُس چہرے سے عشق تھا‘ جسے میں باوجود اپنی کوشش کے آنکھ بھر کے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ یوں تو وہ آنکھیں عینک کے پار سے کبھی کبھار اٹھتیں اور وہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں پر گھوم کر واپس جھک جاتیں۔ لیکن پھر بھی میں سوچتا کہ ان آنکھوں میں دیکھنے کی شاید ہی مجھ میں ہمت ہوسکے۔ نظریں جھکائے وہ سوالوں کا جواب دیتے رہتے۔
آدمی جب کم علم ہوتا ہے تو علمیت زیادہ جھاڑتا ہے‘ اور میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے ایک دفعہ جدلیاتی فلسفے کے حوالے سے اپنے مبلغ علم کو جمع کر کے پوچھا: ’’ہم تاریخ کے جواب دعویٰ (anti thesis) کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس میں صدیوں پرانے سماجی ڈھانچے کی توڑ پھوڑ کو روکنا تاریخ کے پہیے کو روکنا ہے۔ تباہ ہونے دیں اس فرسودہ ماحول کو‘ تاکہ اس کی کوکھ سے ہم نیا نظام جنم دیں‘ دوبارہ نئی بنیادوں پر؟‘‘
وہ واحد لمحہ تھا جب وہ آنکھیں پورے مجمعے کو چیرتی ہوئی مجھ سے ٹکرائیں اور وہ فقرے جن کی گونج میں آج بھی ۳۰ سال گزرنے کے بعد محسوس کرتا ہوں‘ہولے سے ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے انھوں نے کہا: ’’تاریخ میں جن قوموں نے شر کے تھیسس (thesis) کے سامنے خیر کا تھیسس بیک وقت پیش کرنے کی کوشش نہیں کی‘ وہاں پھر کوئی جدلیاتی فلسفہ بھی صالح نظام تخلیق نہیں کرسکا‘‘۔ شاید ہی کسی نے صدیوں کی بحث کو یوں منٹوں میں سمیٹا ہو۔
یہ وہ موڑ تھا جس نے میرے اندر سوال در سوال کے بجاے جستجو کی چنگاری کو سلگا دیا۔ ایک ۱۶ سالہ نوجوان جو تشکیک کے امام نیاز فتح پوری کی من و یزداں سے لے کر مارکس کی داس کیپی ٹال اور ہیگل اور مارگن کی تاریخ کی بھول بھلیوں سے گزرتا ہوا فکری بے یقینی اور روحانی بے اطمینانی کے دور سے گزر رہا تھا‘ اُس کی آنکھوں کے سامنے اُس چہرے کے نور اور لفظوں کی حکمت نے ایک جھپاکا سا کیا۔ایسے جیسے چاروں طرف گھٹاٹوپ بادلوں میں اندھیری رات کے عالم میں اچانک زوردار بجلی چمکے تو ایک لمحے کو سارے نشیب و فراز نظرآجاتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے اور قدم رکھتے ہوئے خوف کا عالم کم اور منزل تک پہنچنے کا یقین زیادہ ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بجلی دوبارہ چمکے یا نہ چمکے‘ راستہ ضرور دکھا جاتی ہے‘ اُس کے نشیب و فراز سے آگاہی ضرور دے جاتی ہے۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ آسمانی بجلی کے برعکس‘ آگاہی دینے والے کی چمک اور پیغام کی گھن گرج جتنی اُس وقت میں نے محسوس کی تھی‘ اُس سے ہزار گنا زیادہ آج کی دنیا محسوس کر رہی ہے۔
مجھے کبھی اپنے ہیروز کے قدوقامت کی پیمایش کے لیے غیروں کے حوالے اچھے نہیں لگتے‘ لیکن کیا کروں مجھے آج کی شرمندہ اور اپنے وجود سے برگشتہ قوم کے سامنے ایک حوالہ رکھنا پڑ رہا ہے۔ گذشتہ ۱۰ سالوں میں مذاہب کی تاریخ اور ان کے عروج و زوال پر جس خاتون کی کتب نے سب سے زیادہ تاثر چھوڑا ہے‘ اور جسے آج کے دور میں سب سے زیادہ غیرمتعصب محقّقہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے وہ کیرن آرمسٹرانگ (Karen Armstrong) ‘ ایک برطانوی کیتھولک راہبہ ہے۔ میں اس کی دو کتابوں Battle for God (خدا کے لیے جنگ) اور Islam: A Short History (اسلام‘ ایک مختصر تاریخ)کا ذکر کرنا چاہوں گا۔
کیرن آرمسٹرانگ ان دونوں کتابوں میں تاریخ کے اس موڑ پر آتی ہے‘ جب مذاہب چلے ہوئے کارتوس بنتے جا رہے تھے اور دنیا سیکولرزم کی گرویدہ اور طلب گار ہوتی جا رہی تھی‘ تو اس سارے طوفان کے مقابلے میں قلم کی صرف ایک آواز اور تحریک کی صرف ایک ہی صورت اُسے نظر آتی ہے اور وہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی ذات ہے۔
مودودی جنھوں نے ۱۹۳۹ء میں اپنا تصور وضع کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح محمد ]صلی اللہ علیہ وسلم[ نے اسلام سے پہلے کی ’’جاہلیت‘‘ یعنی جہالت اور وحشت سے جنگ کی تھی ‘ بالکل اسی طرح دنیا بھر کے مسلمانوں کو تمام میسرذرائع سے مغرب کی جدید ’’جاہلیت‘‘ کی مزاحمت کرنا ہے۔مودودی کو یقین تھا کہ سچے مسلمان دنیا سے الگ رہ کر اور سیاست کو دوسروں پر چھوڑ نہیں سکتے۔ انھیں اس فروغ پاتے ہوئے لادینی سیکولرزم سے لڑنے کے لیے لازماً متحدہوجانا چاہیے اور ایک انتہائی منظم گروہ تشکیل دینا چاہیے۔ مودودی نے لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے اسلام کو ایک مدلل عقیدے اور منظم تحریک کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی‘ تاکہ اسے بھی زمانے کے دوسرے نمایاں نظریات کی طرح سنجیدگی سے لیا جائے۔
حقیقت میں مودودی کسی بھی جدید فرد کی طرح آزادی کے گرویدہ تھے اور آزادی عطا کرنے والی ایک اسلامی الٰہیات پیش کر رہے تھے۔ ان کا استدلال تھا کہ خدا مطلق حاکم ہے‘ اس لیے کوئی انسان دوسرے انسان کی اطاعت پر مجبور نہیں۔ رضاے الٰہی کے مطابق حکومت نہ کرنے والا حاکم اپنی رعایا کو اطاعت پر مجبور نہیں کرسکتا۔ ایسی صورت میں انقلاب صرف ایک حق نہیں‘ بلکہ فرض ہو جاتا ہے۔
شاید ہی کسی نے مولانا مودودیؒ کے اس علمی خزانے سے اتنا مدلل نتیجہ اخذ کیا ہو‘ جتنا اس مصنفہ نے کیا۔ وہ بیان کرتی ہے: ’’مودودی‘ نظریے کی قدر پر یقین رکھتے تھے۔ وہ دوسرے تمام نظاموںکو نقائص سے معمور سمجھتے تھے۔ جمہوریت: حرص و ہوس اور انتشار کا باعث بنتی ہے۔ سرمایہ داری نے طبقاتی جنگ برپا کی ہے اور ساری دنیا کو بنک کاروں کی ایک نہایت قلیل سی تعداد کا غلام بنا دیا ہے۔ کمیونزم نے انسانی آزادی اور انفرادیت کو محدود کر دیا ہے۔ لیکن اسلامی ریاست‘ بدعنوانی اور آمریت سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ انھوں نے جدید اصلاحات کو ایک اسلامی جہت عطا کی‘‘۔ بقول کیرن آرمسٹرانگ: ’’مودودی نے ایک آفاقی جہاد کامطالبہ کیا۔ ان سے پہلے‘ غرناطہ کی تباہی کے بعد سے اب تک کسی مسلمان مفکر نے ایسا دعویٰ نہیں کیا تھا‘‘۔
بقول مصنفہ: ’’یہ آفاقی جہاد کا مطالبہ ‘عدیم النظیر تھا‘ جب کہ حالات بھی مایوس کن تھے۔ عالمِ اسلام میں محمد عبدہ اور حسن البنا پُرامن انداز سے اپنی کوشش کے باوجود مصر کے آمر کے ہاتھوں مغلوب ہوچکے تھے۔ ایسے میں ۱۹۵۱ء میں مولانا مودودی کی حریت فکر اور انقلابی جدوجہد والی تحریریں مصر میں شائع ہونا شروع ہوئیں اور ۱۹۵۴ء میں اخوان المسلمون کی ایک عظیم شخصیت ۱۵ سال کے لیے جیل چلی گئی‘ جہاں اُسے ان تحریروں سے شناسائی حاصل ہوئی اور اُس کی نظروں کے سامنے مغربی دنیا کا ایک ایسا چہرہ اور سیکولر کلچر کی ایک ایسی تصویر آئی جو تقدس اور اخلاقی اہمیت سے خالی اور دہشت سے بھرپور ہے‘‘۔ وہ مولانا مودودی کی تحریروں سے متاثر ہوکر لکھی گئی سید قطب کی اس تحریر کو موجودہ اسلامی تحریک احیا اور سیکولرزم کی کریہہ صورت سے جنگ کا حرفِ آغاز گردانتی ہے۔سید قطب کی یہ تحریر اُس علمی خزانے کے موتیوں سے بھرپور ہے جو مولانا مودودی کی تنقیحات ‘ پردہ‘سود اور تفہیمات جیسے مدلل اور تحقیق سے پُرعلمی سمندر میں مدفون ہیں۔
سید قطب کی تحریر ملاحظہ کریں: ’’دورِحاضر میں انسانیت جسم فروشی کی ایک بہت بڑی مارکیٹ میں زندہ ہے۔ اس کا ثبوت اخبارات‘ فلموں‘ فیشن شو‘ حسن کے مقابلوں‘ رقص گاہوں‘ مے خانوں اور نشریاتی اسٹیشنوں پر صرف ایک نگاہ ڈال کر مل سکتا ہے‘ یا عریاں جسموں کی مجنونانہ نمایش‘ ہیجان انگیز مظاہرے ‘نیز ادب‘ فنون اور ذرائع ابلاغ میں مریضانہ اشاروں سے‘ اور اُس پر سب سے مستزاد سود کا نظام جو انسان میں دولت کی ہوس کو فزوں تر کر دیتا ہے۔ قانون کے لبادے میں دھوکادہی‘ چال بازی اور بلیک میل کرنے کے گھنائونے طریقے اس میں اضافے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں‘‘۔
اپنی دونوں کتابوں میں یہ خاتون کہتی ہے کہ موجودہ اسلامی نشات ثانیہ سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے چراغ سے چراغ روشن کرتی اور سید قطبؒ سے روشنی لیتی ہے۔ پھردنیا بھر میں مغرب کی کریہہ المنظر سوسائٹی کے مقابلے میں اسلام کی نشات ثانیہ کی تحریک کی اس انقلابی اپیل کو انڈونیشیا کے جزائر سے لے کر افغانستان کے پہاڑوں تک اور سوڈان اور الجزائرکے صحرائوں تک لے جاتی ہے۔ مصنفہ کے نزدیک ایران کے انقلاب میں طریق کار کی وضاحت کا شرف اور دنیا بھر میں مزاحمتی تحریکوں کو ایک نیا رخ دینے کا سہرا‘ سید مودودیؒ کے سر بندھتا ہے۔
تاریخ کا یہ تجزیہ بجا اور مصنفہ کی موجودہ دور میں اہمیت اپنی جگہ‘ اُس کا اِس دنیا کی ہربڑی زبان میں ترجمہ ہونے کا اپنا مقام بھی تسلیم‘ لیکن میں آج بھی جب سید مودودی کی تحریریں پڑھتا ہوں تو میں ان کے چہرے کے سحرسے باہر نہیں نکل پاتا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جدید دور کے ایک نئے صوفیانہ سلسلے کے بانی تھے‘ جس میں بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہیں‘ بلکہ ہاتھ میں کتاب دے کر کی جاتی ہو۔ ایسا سلسلۂ تصوف کہ جس میں شیخ طریقت عقلِ کل نہیں‘ تنقید اور احتساب سے بالاتر نہیں بلکہ خود خادم ہے مخدوم نہیں۔
روایت کیا جاتا ہے کہ ہر دور میں صوفیوں نے روحوں کا علاج کیا اور دلوں کی سیاہی کو دُور کیا۔ ہر دور کا اپنا مرض اور ہردور کی اپنی سیاہی ہوتی ہے۔ موجودہ دور کا مرض جہالت پر مبنی علم تھا‘ اور موجودہ دور کی سیاہی اخلاقیات سے تہی زندگی اور کچلی ہوئی انسانیت ہے جو اپنی کم نظری کے باعث اسے آزادی‘ حقوق اور حریت سمجھ رہی تھی۔ حالانکہ ان دونوں کے پیچھے طاغوت کا جال‘ عقلیت کے روپ میں پھیلا ہوا تھا اور اس سارے علم کے جال نے ذہنی غلامی کو جنم دیا تھا‘ جس میں پوری مسلم اُمہ ندامت و شرمندگی کے مارے بُری طرح پھنسی ہوئی تھی اور دوسری طرف مغرب کی چکاچوند کی دلدادہ ہوگئی تھی۔ ایسے میں کئی صدیوں بعد سید علی ہجویریؒ کے شہر میں ایک اور شخص ہجرت کر کے آتا ہے اور انسانی قانون اور الٰہی قانون کے تضادات بیان کرتا ہے۔ یورپ کی اخلاقی حالت کو بیان کرتے ہوئے پردہ میں خیر کی طاقت کا روپ پیش کرتا ہے۔ آج سے ۵۰ سال پہلے لکھی گئی دو کتابیں: تنقیحات اور پردہ آج بھی اُس گہری کھائی کی نشان دہی کے لیے کافی ہیں جس کی طرف پوری انسانیت بحیثیت مجموعی پھسلتی چلی جا رہی ہے۔
حضرت جنید بغدادی ؒکے پاس ایک شخص ملنے گیا۔ بہت دن قیام کیا‘ جانے لگا تو آپ نے پوچھا :’’کیسے آئے تھے؟‘‘ کہا: ’’کوئی کرامت دیکھنے آیا تھا‘ نہیں ملی‘‘۔ فرمایا:’’اتنے دن میرے پاس رہے‘ کوئی ایسا عمل بھی دیکھا جو شریعت کے خلاف ہو؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے!‘‘
میرا عشق بھی اُسی شخص کی طرح ذیلدار پارک کی کوٹھی کے لان میں بیٹھ کر اُس شخص کو دیکھنے سے ہوا‘ اور پھر اُن کتابوں نے میرے ہاتھ میں آنا تھا کہ میں اُس سلسلۂ طریقت میں بیعت ہوگیا۔ لیکن روشن چہرے کے نور کا راز کئی سال بعد کھلا‘ جب میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی:’’چہرہ تو اللہ کے تقویٰ سے روشن ہوتا ہے‘‘۔ جہاں علم اور تقویٰ ایک جگہ جمع ہو جائیں وہاں میرے جیسے شخص کو پکار پکار کر کہنا پڑتا ہے: میں بھٹکا ہوا آہو تھا‘ مجھے سوے حرم اس شخص کا علم اور چہرے کا نور لے آیا--- اے اللہ! اگر ایک بھٹکے ہوئے آہو کو سوے حرم لانے کا کوئی صلہ موجود ہے تو مجھے قیامت کے دن اِس شخص کے حق میں یہ گواہی دینے کی توفیق عطا فرما!